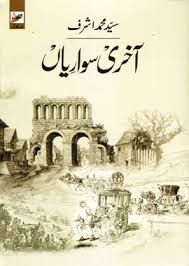آخری سواریاں
سید محمد اشرف
|
|
سید محمد اشرف ہمارے زمانے کے سب سے اچھے فکشن نگاروں میں سے ایک ہیں۔ زبان و بیان پر انھیں جو دسترس حاصل ہے وہ انھیں اپنے بیشتر ہم عصر افسانہ نگاروں سے ممتاز کرتی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنے ثقافتی، تہذیبی، جغرافیائی اورذہنی ماحول کو جس طرح وہ محسوس کرتے ہیں اور پھر ان تمام محسوسات اور تجربات کو جس خوبی کے ساتھ اظہار کے نت نئے سانچوں میں ڈھال دینے پر قادر نظر آتے ہیں، یہ اُن کی ایک غیر معمولی صفت ہے، اس کی کوئی دوسری مثال فی زمانہ نظر نہیں آتی۔ اپنے افسانے ’’ڈار سے بچھڑے‘‘ سے سید محمد اشرف نے جو تخلیقی سفر شروع کیا تھا وہ ان کے تازہ ترین ناول’’ آخری سواریاں‘‘تک آ پہنچا ہے۔یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس درمیان اُن کی ہر تخلیق اردو فکشن میں ایک سنگِ میل ہی ثابت ہوئی ہے۔ چاہے وہ ’’آدمی‘‘ ہو یا ’’روگ‘‘ ، ’’ساتھی‘‘ ہو یا’’ نمبر دار کا نیلا‘‘۔ بقول میلان کنڈیرا ناول اگر انسان کی پوشیدہ وجودی جہات کی دریافت نہیں کرتا تو اسے نہیں لکھا جانا چاہیے۔ ’’آخری سواریاں‘‘ اگرچہ گنگا جمنی ہندو مسلم تہذیب کے گُم ہوتے جانے کا استعارہ ہے مگر اس میں انسان کے وجودی نہاں خانوں پر جو ایک ناقابلِ یقین قسم کی روشنی پڑتی ہے وہ اس ناول کے متن کو اس کے تھیم سے بلند تر اور ماورا کردیتی ہے اور مختلف معنی کی ایک روشن زنجیر جگ مگ کرنے لگتی ہے۔ اس زنجیر کے حلقوں میں ناول کا متن اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ پیوست ہے ۔ ایک مثال پیش ہے: ایک اجتماعی منظرنامے میں وجودی جہات اس لیے روشن ہوئی ہیں کہ اِسی ناول کو Polyphonicکہاجاسکتا ہے۔ Polyphonic کی اصطلاح میخائیل باختن کی دین ہے جو بیسویں صدی میں ناول کا سب سے بڑا پارکھ اور شارح ہے۔اس کا کہنا ہے کہ ناول کو ہمیشہ Polyphonic ہونا چاہیے یعنی اس میں محض ایک راوی کی نہیں بلکہ بہت سے راویوں کی آوازیں شامل ہونا چاہئیں۔ ’’آخری سواریاں‘‘ میں یوں تو محض ایک ہی راوی ہے مگر راوی کی یہ آواز ایک کورس کی طرح ہے جس کے ساتھ بہت سے کرداروں کی آوازیں اپنی اپنی انفرادیت کے ساتھ صاف سُنائی دیتی ہیں۔ کسی ناول میں کئی کرداروں کا ہونا ایک عام سی بات ہے مگر اس سے بہ قول باختن کوئی ناول Polyphonic نہیں ہوجاتا۔ ضروری یہ ہے کہ ناول کے متن اور اس کے شور میں ہر کردار اپنی ایک نمایاں اور منفرد آواز بھی رکھتا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ سطور میں عرض کیا گیا ہے کہ’’ آخری سواریاں‘‘میں مصنّف/ راوی ایک کورس (chorus)کی مانند ہر جگہ موجود ہے اور اپنے کرداروں کے رویّے کا تجزیہ کرتا رہتا ہے اور اس کے پسِ پردہ جو عوامل کارفرما ہیں، ان پر تبصرہ بھی کرتا رہتا ہے۔ دراصل ’’آخری سواریاں‘‘ میں راوی/ مصنّف پوری شدّت کے ساتھ موجود ہے جس کے سبب ناول میں سوانحی عناصر بڑے لطیف اور فطری انداز میں پیدا ہوگئے ہیں۔ یہ کوئی قابلِ گرفت بات نہیں بلکہ کسی بھی سچّے ناول کی ناگزیر خوبی ہے۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ انیسویں اور بیسویں صدی میں ہی ناول نگار کے سوانحی عناصر بہ وجوہ ناول سے غائب ہوئے ہیں یعنی اٹھارہ ویں صدی میں راوی بہ طور ناول نگار ہمیشہ اپنے ناول میں موجود رہا ہے۔ کیوں کہ ناول نگار کا کام کسی صورتِ حال کے جوہر کو کھنگالنا ہے صرف صورتِ حال کو پیش کردینا ہی نہیں ہے۔ سید محمد اشرف نے ماضی کی جو صورتِ حال پیش کی ہے وہ صرف بیان ہی نہیں ہے بلکہ انھوں نے اس صورتِ حال کے جوہر کو کھنگالنے کی بھی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سید محمداشرف کی دل چسپی ماضی یا گنگا جمنی تہدیب کی تاریخ میں کسی Nostalgia سے عبارت نہیں ہے بلکہ وہ ماضی کی تاریخ کے ذریعے حال کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ لہٰذا انھوں نے ’’آخری سواریاں‘‘میں کم و بیش قصّہ گوئی کا وہ انداز اختیار کیا ہے جس کے سرے اٹھارہویں صدی کے مغربی ناول یا کسی حد تک داستان سے بھی جاکر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ’’احوالِ سفرِ سمرقند‘‘ وغیرہ کی شمولیت کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ میں جب یہ ناول پڑھ رہا تھاتو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بھی ’’آخری سواریاں‘‘ میں سے ایک ہوں۔ ناول میں مجھے اپنے سوانحی آثار بھی پیدا ہوتے نظر آئے۔ ہم میں سے ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنی تاریخ کو بار بار لکھتا رہتا ہے۔ ہم ہمیشہ واقعات کو اپنی پسند اور ترجیحات کے مطابق مفہوم دیتے رہتے ہیں اور ایسی اشیا کو بھلا ئے رہتے ہیں جو کسی معنی میں ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں مگر ناول نگار کا کام بہ قول میلان کنڈیرا فراموشی کے خلاف ایک جنگ لڑنا ہے۔ ایک جینوئین ناول نگار کے لیے کچھ بھی ناقابلِ فراموش نہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں ناول نگار نہ صرف ایک عام انسان سے بلکہ جیسا کے لارنس نے کہا ہے کہ وہ ایک سائنس دان، فلسفی اور ستی جتی سے بھی بلند ہوجاتا ہے کیوں کہ یہ سب لوگ زندہ انسان کے مختلف اجزا کے ماہر ہیں مگر ان اجزا کی سالم صورت کا ادراک صرف ناول نگار کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح ناول ہی فقط ایک روشن کتابِ زندگی ہے۔ ’’آخری سواریاں‘‘ اس تعریف پر پورا اُترتا ہے کیوں کہ اس ناول کے ذریعے سید محمد اشرف نے ساٹھ کی دہائی کے اجتماعی ذہن کو ’ناقابلِ فراموش‘ کی دولت سے نوازا ہے۔ فرحت احساس نے کیا عمدہ بات کہی ہے کہ ’’آخری سواریاں‘‘ کو وقت کے گزران اور ایک ثقافتی وفات کا نوحہ بھی کہا جاسکتا ہے جو افسانے کی تخلیقی نثر میں شاید پہلی بار پڑھا گیا ہے۔‘‘ وہ نسل جو ساٹھ کی دہائی میں پیدا ہوئی (میرا تعلق بھی اسی نسل سے ہے) اس جذباتی کشمکش سے پوری طرح مانوس ہوسکتی ہے جسے اس ناول میں پیش کیا گیا ہے۔ اس نسل نے ایک بالکل مختلف زمانے میں اپنے بچپن اور جوانی کو پلتا بڑھتا دیکھا ہے اور اب ڈھلتی ہوئی عمر کے اس پڑاؤ پر یہ نسل اُس سے قطعاً مختلف بلکہ متضاد زمانے میں بھی سانسیں لے رہی ہے۔ تبدیلی کے جس پُر اسرار عمل اور وقت کے جس بھیانک اور فنا کے تماشے کی گواہ یہ نسل ہے شاید اس سے پہلے اور اس کے بعد کی نسلیں اس احساس تک نہ پہنچ سکیں۔ اس ناول کے سچے اور ایماندار قاری وہ ہیں جو خود بھی ایک پُر اسرار اور نادیدہ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور جلد ہی یہ گاڑی ایک ابدی کہرے میں گُم ہوجانے والی ہے۔ سید محمد اشرف کا ہم جیسے لوگوں پر بڑا احسان ہے اور یہ اردو فکشن کی تاریخ میں اضافے کا سبب بھی بنا ہے کہ انھوں نے دور کہرے میں گُم ہوتے ہوئے ندی کے کنارے کو اس کے پورے خد و خال اور مکمل منظر نامے کے ساتھ ایک دستاویزی حیثیت کی شے بنا دیا ہے اور اس کے لیے اُن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ناول کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ اس کی تکنیک اور اس کا متن ؍ مواد آپس میں پوری طرح ہم آہنگ ہوگئے ہیں۔ ناول ایک زبانی ساخت ہوتا ہے اس لیے ہر درس گاہ میں اُسے اس زبان و قوم کے حوالے سے ہی پڑھایا جاتا ہے جس سے ناول کا تعلق ہو۔ اس طور دیکھیں تو ’’ آخری سواریاں‘‘ کو جس درس گاہ میں پڑھایا جانا چاہیے اس کا نام اردو معاشرہ ہے اور ہم سب کو اسے طالبِ علموں کی طرح پڑھنا چاہیے کیوں کہ یہ ناول ہمیں فراموشی کے حملے سے بچاتا ہے۔ اس کا متن ہمیں ایک بھُولاہوا سبق یاد دلاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے پر مجبور کرتا ہے۔ ’’آخری سواریاں‘‘ ہمارے حافظے کا ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرتا ہے۔ ’’رخصت کے تانگے رکشے چلے گئے تو میں پیدل پیدل اسٹیشن روانہ ہوا۔ میرے پیچھے کچھ اور لوگوں کو بھی روانہ کیا گیا۔ ریل گاڑی آنے تک میں پانی کی ٹنکی کے پیچھے کھڑا رہا۔ ریل آئی، دلہن کو اُس کے بیٹوں نے سہارا دے کرچڑھایا۔ وہ کھڑکی کے پاس آکر بیٹھ گئی۔ گارڈ نے سیٹی بجائی اور ہری جھنڈی دکھائی۔ میں ٹنکی کے پیچھے سے نکل کر اس ڈبّے کے سامنے آیا۔ ریل چل دی۔ اُس کا بوڑھا، کمزور باپ ریل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اُس نے ریل کے ساتھ چلتے اپنے باپ کے ہاتھوں کو کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ چھُڑایا۔ دوڑتے ہوئے باپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ساتھ چلنے سے روکا۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر کردیا۔ اب دلہن نے مجھے دیکھا۔ اس نے گھونگٹ نہیں پلٹا۔ مہندی رچا ہاتھ اُٹھا دیا اور اُٹھائے رکھا۔ دور تک وہ ہاتھ نظر آتا رہا۔ میں نے پیچھے مُڑ کر دیکھا۔ امّاں میرا ہاتھ اٹھائے کھڑی تھیں۔ ریل کے آخری ڈبّے کی لال بتّی دھیرے دھیرے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ امّاں نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر انگلیوں سے میرے بال برابر کیے اور کہا:’’اب اس پٹری پر یہ ریل واپس نہیں آئے گی۔‘‘ (آخری سواریاں، ص 93-94 ) مگر یہاں سب سے حیرت زدہ کردینے والی بات یہ ہے کہ سید محمد اشرف کی زبان، اس شائستگی اور تنظیم و تربیت کو ایک توانا اور جاندار پیکر میں تبدیل کردیتی ہے۔ دراصل اُن کی سب سے بڑی طاقت تو اُن کی یہ پاکیزہ اور بامعنی زبان ہی ہے جس کے ذریعے وہ کاغذ ایک سلولائیڈمیں بدل جاتا ہے جس پر اشرف کے قلم کی روشنائی پھیلتی ہے۔ زبان کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ اشرف کی تمام تحریروں میں کلچرل کوڈز، فطری اور قدرتی کوڈز کے ساتھ ایک استعاراتی نظام قائم کرلیتے ہیں اور سب سے بڑا کرشمہ جو اس عمل کے دوران رونما ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان خود بھی ایک فطری یا قدرتی مظہر میں ڈھل جاتی ہے۔ ایک جنگل کی سی پُر اسراریت اور پاکیزگی لیے۔ میرا خیال ہے کہ سید محمد اشرف کی زیادہ تر تخلیقات کا مطالعہ ماحولیاتی تنقیدی نقطۂ نظر سے بھی کیا جانا چاہیے۔ ادب اور ماحول کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور بہ قول Cheryll Glotfelty کسی فن پارے کی پوشیدہ اخلاقیات اس وژن کے ذریعے سامنے لائی جاسکتی ہیں۔ مگر ابھی میں eco-criticism اور اس مسئلے کو کسی اور وقت کے لیے اُٹھا رکھتا ہوں لیکن ناول سے یہ اقتباس ضرور پیش کرنا چاہوں گا: ائے گی؟ لیکن یہ تو ہمیشہ بیٹھ کر پانی کا قطرہ لینے کی عادی ہے۔ تو کیا یہ کنویں میں جاکر ڈوب جائے گی۔ پھر میں بالٹی سے پانی کھینچوں گا تو اس میں ایک مُردہ سبز چڑیا بھی ہوگی جس کی چونچ کھُلی ہوئی ہوگی۔‘‘ ’’یہ نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اس میں مخصوص سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اُٹھاتے ہیں تو اپنی ہتھیلیاں چہرے کی طرف نہیں اوپر کی طرف بلند کر دیتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ اسے دکھاتے ہیں کہ اے مالک و معبود ہمارے ہاتھ خالی ہوگئے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد گرمی میں جاکر جنگل میں اس لیے پڑھنا لازمی ہے کہ عاجزی اور مشقّت کے بغیر کوئی بڑا انعام نہیں ملتا۔ اپنے پالتو جانور بھینس، بکریاں اور بیل بھی لے کر چلنا۔ وہ سب بھی دعا کرتے ہیں۔‘‘ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ سید محمد اشرف نے اس ناول کو داخلی طور پر دو حصّوں میں لکھا ہے۔ پہلا حصّہ وہ ہے جو جمّوکے رخصت ہونے پر ختم ہوجاتا ہے۔ ’’آخری سواریاں‘‘ میں سب سے پہلی جھلک ہمیں جمّو میں ہی نظر آتی ہے اور باقی ناول کو دوسرے حصّے سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ پہلے حصّے میں انفرادی معصومیت کی دبازت زیادہ ہے اور دوسرے میں اجتماعی منظر نامے میں وجودی عناصر کی دریافت کی گئی ہے۔ تقریباً دو الگ الگ کہانیاں ہونے کے باوجودزیریں سطح پر دونوں کا تھیم ایک ہی ہے اور اس طرح ناول میں وحدت پیدا ہوجاتی ہے۔ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی آپس میں مل کر ایک اِکائی خلق کرتی ہیں اور اس طرح ناول کا تھیم دو مختلف آوازوں کی جُگل بندی کے ذریعے تخلیقی طور پر ایک بامعنی اور بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ مگر یہ بھی ہے کہ کوئی بھی تخلیق چاہے وہ ناول ہو یا افسانہ یا شاعری اپنی ماہیت میں ایک ہیجانی اور وجدانی تجربہ ہی ہوتی ہے۔ اس قسم کے معنی تو تجربے کے بعد ہی اس میں سے برآمد کیے جاتے ہیں۔ خود اشرف کے ناول میں کسی تبلیغ یا تلقین کا رنگ نہیں ہے۔ انھوں نے اپنے تخلیقی تجربے کو خاموشی اور آہستگی کے ساتھ کاغذ پر اُتاردیا ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج ناول بھی ہر کلچر اور ہر آرٹ کی طرح ماس میڈیا کے ہاتھ میں آچکا ہے۔ یہ سہل پسندی کا دور ہے۔ لکھنے والوں سے زیادہ تو قاری سہل پسند ہوچکے ہیں۔ یہ ماس میڈیا کے بڑھتے ہوئے اثر کے ذریعے ہورہا ہے۔ ناول لکھے جانے کی جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ناول کا اسکرین پلے لکھا جارہا ہو۔ ہماری بصیرت، ہمارا عقیدہ اور ہماری فکر ریزہ ریزہ ہورہی ہے۔ اِس لیے یہ بہت اطمینان بخش امر ہے کہ ’’آخری سواریاں‘‘ ایسے زمانے میں سامنے آیا ہے جب ایک سنجیدہ اور گہرے ناول کی شدّت سے کمی محسوس کی جارہی تھی۔ ایسے ناول کو ماس میڈیا کبھی نہیں ہڑپ سکتا۔ آخری سواریاں خالص ادبی شرطوں پر پڑھے جانے کا اصرار کرتا ہے۔ یہ ناول شاید اُن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو زندگی کو سہل تر بنانے کے درپے ہیں بلکہ ان کے لیے جو اسے بامعنی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ میں سید محمد اشرف کے اس ناول پر بہت سی رسمی باتوں اور ادبی کلیشوں سے بہ وجوہ گریز کرتا ہوں اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ’’آخری سواریاں‘‘ جاتے ہوئے میں نے بھی دیکھی ہیں۔ میں بھی اس کا گواہ ہوں اور میری نسل کے میری طرح کے بے شمار افراد سید محمد اشرف کے ساتھ سڑک کے اُسی موڑ کی طرف دیکھتے ہوئے اُسی جگہ بیٹھے ہیں،یہ دیکھنے کے لیے کہ سواریاں واپس آتی ہیں یا نہیں۔ |