نویدِ فکر از سبط حسن
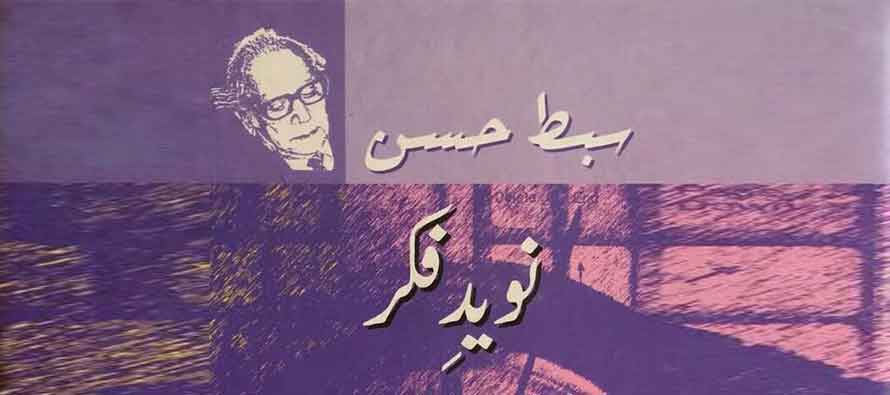
تمہید
یہ مضامین مختلف اوقات میں وقفے وقفے سے لکھے گئے ہیں مگر شاید بے ربط نہ ہوں کیونکہ ان کی شیرازہ بندی تاریخی اصولِ تنقید سے کی گئی ہے۔ واقعات یا خیالات کی تکرار ممکن ہے کہ نازک طبیعتوں پر گراں گزرے لیکن بات سچی ہو تو اس کی تکرار میں چنداں مضائقہ نہیں۔ بعض مضامین نزاعی ہیں۔ ان پر سنجیدگی سے غور کرنا مناسب ہوگا۔ مصنف کی دلیلیں یا دعوے اگر غلط ہوں تو ان کو بے شک رد کر دیجئے۔ مشتعل ہونا قوتِ استدلال کے ضعف کی علامت ہو گی۔ قلم کا جواب زبان قلم سے دینا اربابِ فہم کا مسلک ہے اس لیے کہ خیالات کو بہتر حالات ہی سے شکست دی جا سکتی ہے اور گمراہیاں راستی کی راہ دکھانے ہی سے رک سکتی ہیں نہ کہ احتساب کی آہنی دیواروں سے ۔ پاپائے روم کی روحانی سلطنت میں احتساب کا باقاعدہ ایک محکمہ صدیوں سے قائم ہے۔ پرانے زمانے میں تو ممنوعہ کتابیں اور ان کے مصنف دونوں کو آگ میں زندہ جلا دیا جاتا تھا پھر بھی نئے خیالات پیدا ہوتے رہے۔ سرسید اور علامہ اقبال کی تحریروں کے خلاف جو فتوے لگے ان سے جگ ہنسائی کے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ زمانے نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ خود کردیا۔ سر سید کی تصنیفات آج سرکاری طور پر شائع ہوتی ہیں اور علامہ اقبال مفکرِ پاکستان کہلاتے ہیں۔ہمارے روشن خیال علمائے سلف کا قول تھا کہ یہ نہ دیکھوں کہ وہ کون ہے بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کی فکری اصلاح اسی اصول کے تحت کی۔ جو خیالات ان کو سچ دکھائی دیے ان کو انہوں نے مومن کا کھویا ہوا مال سمجھ کر خوشی خوشی قبول کر لیا۔ نہ ان کے دین میں خلل پڑا نہ ان کے عقائد بگڑے، جو خیالات ان کو غلط لگے ان کو انہوں نے دلائل وبراہین سے رد کرنے کی کوشش کی مگر قدما کی یہ درخشاں روایت افسوس ہے کہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جذباتیت، تنگ نظری اور ناروا داری ذہنوں پر اس قدر حاوی ہے کہ نئی فکر کی تازہ ہوائیں ادھر کا رخ کرتے ہیں حالانکہ؎
جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہے نمود
یہ روش اگر جلد نہ بدلی گئی تو ہم اپنی نئی نسلوں کو شاہ دولہ کے چوہوں کے سوا تحفے میں کچھ نہ دے سکیں گے۔
سبطِ حسن۔ کراچی
24 جولائی 1982
باب اول: تھیو کریسی
” ہم کس چیز کے لیے جدو جہد کررہے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ ہم تھیو کریسی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ نہ ہمارا نصب العین تھیو کریٹک ریاست قائم کرنا ہے۔”
بہر صورت پاکستان تھیو کریٹک ریاست نہیں ہونے والا ہے جہاں مُلاؤں کی حکومت ہو، جن کا خیال ہے کہ ان کو الوہی فریضہ سونپا گیا ہے۔”
تھیو کریسی ریاست کہ وہ قسم ہے جس میں حکومت کے قوانین احکامِ خداوندی سے منسوب کیے جاتے ہوں یا جہاں کا حاکمِ اعلٰی خدا یا خدا کا اوتار یا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں تھیو کریسی وہ ریاست ہے جس میں اقتدارِ اعلٰی کے مالک ملک کے باشندے نہ ہوں اور نہ عنانِ اختیار ان کے چنے ہوئے نمائندوں کے ہاتھ میں ہو بلکہ سربراہ مملکت کسی دوسرے ذریعے سے اقتدار حاصل کر کے احکامِ خدا وندی کی ترجمانی کا مدّعی ہو۔
لیکن تھیو کریسی، ملوکیت اور جمہوریت ریاست کی مختلف قسمیں ہیں لہذا تھیو کریسی کی تفصیلات پر غور کرنے سے پیش تر ریاست کی نوعیت کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ جب سے پاکستان اور ایران میں اسلامی ریاست کا غلغلہ پیدا ہوا ہے بعض حلقے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مُشرف بہ اسلام ہوتے ہی ریاست کی فطرت بدل جاتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم سوچیں کہ کوئی مسیحی مسلمان ہوتے ہی آنکھوں کے بجائے کانوں سے دیکھنے لگے گا یا پاؤں کےبجائے سر کے بل چلے گا۔
ریاست کسی خود مختار علاقے کی سب سے مقتدر سیاسی تنظیم ہے جو علاقے کی آبادی کو مختلف قاہرانہ اور نظریاتی ذرائع سے اپنے احکام کا پابند بناتی ہے۔ ریاست ازل سے موجود نہیں ہے اور نہ آسمان سے اتری ہے۔ وہ انسانوں ہی کا بنایا ہوا سماجی ادارہ ہے جس کی تشکیل ایک دن میں کسی کے حکم سے نہیں ہوئی بلکہ جس نے گزشتہ چھ ہزار برس میں ارتقاء کی کئی منزلیں طے کی ہیں۔ ریاست دراصل اس وقت وجود میں آئی جب معاشرہ طبقوں میں بٹ گیا اور دولت آفرینی کے ذرائع (زمین، زمین کی پیداوار اور آلاتِ پیداوار وغیرہ ) چند افراد کی ذاتی ملکیت بن گئے۔ ریاست انسانوں کی پہلی با اختیار معاشرتی تنظیم بھی نہیں چنانچہ خاندان، گھرانے، برادریاں اور قبیلے کا سردار اور گاؤں کا مُکھیا سب سے مقتدر شخص ہوتا تھا۔ حاکمیت کا مرکز بھی رواج ہی تھا جس کی حیثیت ہر چند کہ اخلاقی تھی مگر جمعیت کے ہر فرد کو رواج کی حاکمیت تسلیم کرنی پڑتی تھی۔ مثلاً آنحضرتؐ کے عہد میں مکّے اور مدینے میں قبیلہ داری نظام رائج تھا مگر ریاست نہ تھی۔ مدینے میں قبیلے الگ الگ چہار دیواریوں میں رہتے تھے اور ہر قبیلہ اندرونی نظم و نسق کا خود ذمہ دار ہوتا تھا۔ پورے شہر کی کوئی با اختیار مرکزی تنظیم نہ تھی۔ مکّے میں بھی جو مذہبی اور تجارتی اعتبار سے نہایت اہم شہر تھا قبیلے جد ا جدا خود مختار و حد تیں تھیں البتہ قبیلوں کے سرداروں کی ایک ڈھیلی ڈھالی تنظیم ضرور موجود تھی جس نے حج اور تجارت کے فرائض آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ جنگ کے موقعے پر کسی موزوں شخص کو لشکر کا سالار چُن لیا جاتا تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی بلکہ شہر کا دفاع ہر بالغ اور تندرست شخص کا فرض تھا۔
ان پرانی تنظیموں میں اور ریاست کے درمیان یہ فرق بھی ہے کہ پرانی تنظیموں کی وحدت کی بنیاد خونی رشتے، مذہبی عقائد اور زبان کی یکسانیت پر تھی۔ مخصوص علاقے سے وابستگی شرط نہ تھی۔ (بدوی قبیلے صحرا نورد تھے) جب کہ ریاست ایک علاقائی یا جغرافیائی سیاسی وحدت ہے جو خونی رشتوں سے متعین نہیں ہوتی بلکہ اس کے حدود میں ایک سے زائد قبیلوں ، قوموں، زبانوں اور مذہبوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک اہم فرق یہ بھی ہے کہ خاندان، برادریاں، قبیلے اور گاؤں کی پرانی تنظیمیں طبقوں میں بٹی ہوئی نہیں تھیں۔ ان میں نہ کوئی حاکم تھا نہ کوئی محکوم اس کے برعکس ریاست کی نوعیت ابتدا ہی سے طبقاتی رہی ہے۔ وہ معاشرے کے طبقات میں بٹ جانے ہی کہ وجہ سے وجود میں آئی اور اس کا منصب ہی یہ ہے کہ حاکم طبقے کی بالادستی کا بچاؤ کیا جائے۔ غرضیکہ ریاست خواہ وہ تھیو کریسی مذہبی پیشواؤں کے اقتدار و مفاد کا تحفظ کرتی تھی۔ ملوکیت کا فریضہ بادشاہ اور شاہی خاندان کے اقتدار کو قائم رکھنا تھا۔ بور ژوا جمہورتیں سرمایہ دار طبقے کی محافظ و معین ہوتی ہیں۔ سو شلسٹ ریاستیں محنت کش طبقوں کے مفاد کا تحفظ کرتی ہیں۔
“ہرگزکوئی ایسی طاقت نہیں جو سو سائٹی پر اوپر سے تھوپی گئی ہو۔۔۔ بلکہ وہ سو سائٹی ہی کی پیداوار ہے جو معاشرتی ارتقا کی ایک خاص منزل پر نمودار ہوتی ہے۔ اس کا وجود اس بات کا اقرار ہے کہ سو سائٹی اب ناقابلِ حل تضاد میں الجھ گئی ہے اور اس کے اندر ایسی مخاصمتیں پیدا ہو گئی ہیں جن کے درمیان کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا اور نہ سوسا ئٹی ان دشمنیوں کو دور کر سکتی ہے لیکن مبادا یہ مخاصمتیں، یہ طبقے جن کے اقتصادی مفاد آپس میں ٹکراتے ہیں، بے سُود کشمکش سے اپنے آپ کو او ر سو سائٹی کو جلا کر خاک کردیں، ایک ایسی طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے جو بظاہر سو سائٹی سے بلند و بالاتر ہو تاکہ تصادم میں اعتدال قائم ہو سکے اور باہمی ٹکر کو ” نظم و ضبط ” کی حدود میں رکھا جا سکے۔ یہ طاقت جو سو سائٹی کے اندر سے ابھرتی ہے لیکن اپنے کو سو سائٹی سے بالا رکھتی ہے اور سو سائٹی سے مسلسل بیگانہ ہوتی جاتی ہے ریاست ہے۔”
ابتدائی ریاستیں شہری ریاستیں تھیں جو سب سے پہلے دھات کے زمانے میں دریاؤں کے کنارے قائم ہوئیں۔ دھا ت کے آلات و اوزار کے رواج پانے سے دیہات کی فاضل پیداوار میں اضافہ ہوا، پیداوار میں اضافے کی وجہ سے پیشوں کی تقسیم اور تجارت کی ابتدا ہوئی اور منڈیوں ، بازاروں اور شہروں کا قیام عمل میں آیا۔ ان شہروں کا مرکز کوئی نہ کوئی عبادت گاہ ہوتی تھی جس نے ریاست کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہری آب پاشی کا بندوبست، علاقائی جنگیں اور غلامی کے رواج نے بھی ریاست کی تشکیل میں بڑی مدد دی۔
ابتدائی ریاستیں تھیو کریسی یعنی مذہبی ریاستیں تھیں خواہ وہ وادیِ نیل اور وادیِ دجلہ و فرات کی ہوں یا وادیِ سندھ اور وادیِ گنگ وجمن کی۔ وجہ یہ تھی کہ بڑی بڑی عبادت گاہیں اپنے گردو نواح کی سب سے بااثر اور دولت مند طاقت ہوتی تھیں۔ عبادت گاہ میں جس دیوی دیوتا کی پوجا ہوتی تھی بستی اسی کے نام سے منسوب کر دی جاتی تھی بلکہ اسی دیوتا کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ مثلاًبالائی مصر کا دارالحکومت تھی بیز خداوند آمون رع کی ملکیت تھا اور زیریں مصر کا صدر مقام مِمِفس بیل دیوتا کی ملکیت تھا۔ اسی طرح جنوبی عراق میں اریدو شہر میٹھے پانی کے دیوتا انِ کی، اریک سب سے بڑے دیوتا انو، نیفر ہو اکے دیوتا ان لیل اور اُر چاند دیوتا انناّ کی ملکیت تھے۔ جاتریوں کی آمدورفت بڑھی تو بنیے بقال، بیو پاری، دکان دار اور دوسرے پیشوں کے لوگ وہاں آکر آباد ہونے لگے اور یہ جگہیں رفتہ رفتہ پہلے شہر پھر شہری ریاستوں کا صدر مقام بن گئیں۔ ان شہری ریاستوں کے سربراہ معبودوں کے مہاپروہت ہوتے تھے جو زمین پر آسمانی دیوتاؤں کے نمائندے خیال کیے جاتے تھے اور جن کے احکام دیوتاؤں کے احکام کا درجہ رکھتے تھے۔ سو میری زبان میں ریاست کے سربراہ کو ” پیتسی” (Patesi ) کہتے تھے جس کے لفظی معنی “پروہت راجہ” کے ہوتے ہیں اور قدیم مصری زبان میں “خدا” اور “بادشاہ” دونوں کے لیے “ہوروس” کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ پروہت راجاؤں کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنوبی عراق کے آثارِ قدیمہ کی کھدائی میں اب تک مٹی کی جتنی لَوحیں نکلی ہیں۔(ڈھائی لاکھ) ان میں سے 95 فیصد لَوحیں معبدوں کے حساب کتاب سے متعلق ہیں۔ فقط پانچ فی صد ایسی ہیں جن پر اشلوک ، گیت بھجن اور داستانیں لکھی ہیں۔
پروہت راج میں ریاست کے سربراہ کو دہرے فرائض سر انجام دینے پڑتے تھے۔ وہ مذہبی پیشوا بھی ہوتا تھا اور ریاست کے نظم و نسق کا نگرانِ اعلٰی بھی۔ مذہبی امور کی حد تک اس کے اختیارات لا محدود تھے کیونکہ وہ زمین پر اپنے ربِ کائنات کا نائب تسلیم کیا جاتا تھا اور اسی کے رو برو جواب دہ تھا لیکن ریاستی امور میں اس مجلسِ شوریٰ کے فیصلوں کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔ یہ مجلسِ شوریٰ عمائدینِ شہر کی نمائندہ تنظیم ہوتی تھی جس کو پاکستان کی نام نہاد مجلسِ شوریٰ کی مانند ریاست کا سرراہ نام زد نہیں کرتا تھا۔ نہروں اور تجارتی راستوں کی دیکھ بھال کرنا، ریاست کے اندر امن و امان برقرار رکھنا، شہریوں کے آپس کے جھگڑے چکانا اور مقدموں کا تصفیہ کرنا مجلسِ شوریٰ کے فرائض میں داخل تھا۔ مجلسِ شوریٰ کے علاوہ بزرگانِ شہر کی ایک مجلسِ اعلیٰ بھی ہوتی تھی۔ ان دونوں “ایوانوں” میں فیصلے کثرتِ رائے سے نہیں بلکہ اتفاقِ رائے سے ہوتے تھے جو قبیلہ داری نظام کی دیرانہ روایت ہے۔
مگر دہرے فرائض اور محدود جمہوریت کا ریاستی نظام زیادہ دن نہ چل سکا کیونکہ شہری ریاستیں اپنے دائرہ اثر کو وسعت دینے اور اپنے ذرائع دولت آفرینی میں اضافہ کرنے کی خاطر بیش تر اوقات ایک دوسرے پر حملے کرتی رہتی تھیں۔ یہ صورتِ حال شخصی حکومت کے قیام کے حق میں بہت مدد گار ثابت ہوئی۔ جنگ کے موقعے پر چونکہ تمام اختیارات لا محالہ سالارِ فوج کے سپرد کرنے پڑتے تھے لہذا وہ سیاسی طاقت کا مرکز بن جاتا تھا۔ سو میری زبان میں اس شخص کو “لُوگل” یعنی بڑا آدمی کہتے تھے۔ ابتدا میں لُوگل کا عہدہ “باندہ” یعنی عارضی ہوتا تھا اورجنگ کے گزر جانے پر تمام اختیارات مجلسِ شوریٰ کو منتقل کر دیے جاتے تھے مگر ہنگامی حالات کے خاتمے کا فیصلہ لُوگل باندہ ہی کرتا تھا چنانچہ ہنگامی حالات رفتہ رفتہ عارضی سے مستقل ہونے لگے کیونکہ لوگل باندہ کا فائدہ اسی میں تھا۔ بالآخر فوجی طاقت کے مالک ریاست کے سربراہ بن گئے۔ البتہ مجلسِ شوریٰ کا نظام شخصی حکومتوں کے قیام کے بعد بھی عرصے تک باقی رہا۔ مثلاً گل گامش کی داستان میں گل گامش کے اس طرزِ عمل پر اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ مجلسِ شوریٰ کو خاطر میں نہیں لاتا۔
” گل گامش ایوانِ شوریٰ میں زبردستی گھس آیا ہے حالانکہ یہ عمارت شہریوں کی ملکیت ہے۔”
اس فقرے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مجلسِ شوریٰ کی اپنی عمارت ہوتی تھی اور حاکمِ وقت بھی اس میں مجلس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ایوان کے کاموں میں مداخلت کرسکتا تھا لیکن بادشاہوں کی طاقت جب مستحکم ہو گئی تو مجلسِ شوریٰ کا ادارہ قدرتی موت مرگیا۔ بادشاہ شہریوں کے نمائندے کے بجائے اپنے نامزد کردہ وزیروں اور درباریوں سے صلاح و مشورے کرنے لگے۔
ملوکیت کے اس ابتدائی دور میں بادشاہ اقتدارِ اعلیٰ کا مالک ضرور تھا لیکن مقننّہ اور عدلیہ کے اختیارات بدستور پروہت طبقے کے پاس رہے۔ پروہت طبقہ مذہبی احکام کے مطابق قانون بناتا اور یہ تصفیہ کرتا کہ مذہب کی روح سے کون سا فعل جائز ہے اور کون سا ناجائز، مذہب نے کس جرم کی کیا سزا مقرر کی ہے اور رعایا کے کون کون سے فرائض متعین کیے ہیں۔ اس تقسیمِ کار کی بدولت بادشاہوں کو ریاست کے نہایت اہم طبقے کا تعاون ہی حاصل نہیں ہوا بلکہ ان کے اقتدار کو مذہبی جواز بھی مل گیا۔
بادشاہوں نے ریاست پر قابض ہونے کے بعد عبادت گاہوں کے وقار پر حرف نہ آنے دیا۔ نہ ان کی املاک ضبط کیں اور نہ عبادت گاہوں کے نظم و نسق میں کوئی مداخلت کی بلکہ ان کو مزید انعام واکرام سے نوازا۔ عبادت گاہ کی مرمت میں شرکت ہر شخص کا مذہبی فریضہ تصور کی جاتی تھی۔ اس رسم کی ابتدا بادشاہ کرتا تھا چنانچہ بابل سو میر اور اسور کے قدیم آثار سے ایسی لَوحیں برآمد ہوئی ہیں جن میں بادشاہ کو سر پر ٹوکری رکھے مرمت کے کام میں مصرف دکھایا گیا ہے۔
پروہتوں نے بھی نئی تقسیم کار کو بہ خوشی قبول کرلیا۔ انہوں نے بادشاہوں سے پورا پورا تعاون کیا اور ان کو خدا، خدا کا اوتار، خدا کا نائب بنا دیا۔ بادشاہ کی شخصیت کے گرد تقدس کا جو ہالہ ان پروہتوں نے چھ ہزار برس پہلے کھینچا تھا ملوکیت کے زوال تک مشرق اور مغرب میں تھوڑے تھوڑے فرق سے ہر جگہ بدستور قائم رہا۔ چنانچہ اسلامی دور میں بھی بادشاہوں کو ظِل اللہ (خدا کا سایہ) کا لقب ملا۔ قاضی ماوردی نے “احکام السلطانیہ” میں، امام غزالی نے “نصیحت الملوک میں، نظام الملک طوسی نے ” سیاست نامے” میں، ابو نصر فارابی نے “الآرا مدینتہ الفاضلہ” اور ان خلدون نے “تاریخ” میں اطیعو اللہ اطیعوالرسول اور اولی الامر منکم کی غلط اور غیر تاریخی تفسیر کی آڑ میں حاکمِ وقت کی اطاعت کا جو سبق مسلمانوں کو دیا وہ غیر مسلم مذہبی پیشواؤں کی تلقینوں سے چنداں مختلف نہیں۔
پرانے زمانے میں ریاستوں کے وسائل اتنے وافر نہیں تھے کہ وہ تنخواہ یافتہ فوج اور پولیس ملازم رکھ کر رعایا کو اپنے احکام کی پابندی پر مجبور پر سکتیں۔ رسل و رسائل اور آمدو رفت کی سہولتیں بھی بہت کم تھیں لہذا شاہی احکام کے نفاذ میں رکاوٹیں پیش آتی تھیں اور ریاست اپنی قوت قاہرہ سے خاطر خواہ کام نہیں لے سکتی تھی۔ حالاتِ زندگی کی ان دشواریوں کا تقاضہ تھا کہ ایسے نظریے رائج کیے جائیں جن کی بدولت لوگوں کے دل و دماغ ریاست کے احکام و قوانین کی پابندی کے خوگر ہو جائیں اور اطاعت و فرماں برداری ان کی سرشست بن جائے ۔ اس روایت پر آج بھی ہر جگہ عمل ہورہا ہے چنانچہ دنیا میں ایسی کوئی ریاست نہیں جس کا کوئی نظریہ نہ ہو۔ نظریاتی ریاست ہونا پاکستان کی انفرادی خصوصیت نہیں۔
ریاستوں کے تشکیلی دور میں عقائد و افکار کی اجارہ داری مذہبی پیشواؤں کو حاصل تھی اور لوگوں کے ذہنوں پر انہیں کی حکومت تھی لہذا ریاست کے ابتدائی نظریوں پر مذہب کی چھاپ پڑنا قدرتی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابل، مصر، ایران، یونان، فلسطین، ہندوستان اور چین ہر ملک میں ریاست کو عطینئہ خداوندی قرار دیا گیا، حاکمِ وقت کو خدا، خدا کا اوتار یا نمائندہ بنا یا گیا اور ریاست کے احکام و قوانین کو فرمانِ الہیٰ سے منسوب کردیا گیا۔ شہری ریاست اریک (جنوبی عراق) کے بادشاہ اتوہیگل (2120۔2114 ق۔م) نے تو ان بادشاہوں کی باقاعدہ فہرست مرتب کروالی جو دجلہ و فرات کی وادی میں ” آسمان سے اُتری تھیں”۔ اس فہرستِ شاہاں کے مطابق “آسمان سے پہلی بادشاہت اریدو میں اتاری گئی” جو سو میری قوم کا سب سے قدیم شہر تھا۔ ” یہ بادشاہت 64 ہزار 8 سو برس تک قائم رہی ” اور اس طویل عرصے میں فقط دو بادشاہ ہوئے، پھر کسی نامعلوم سبب سے بادشاہت شہر باد طبریٰ میں منتقل ہو گئی۔ وہاں سے لہرک، پھر سیپر اور آخر میں شروپک پہنچی اور ” تب زمین پر سیلاب آگیا۔”
سیلابِ عظیم کے بعد ” بادشاہت دوبارہ آسمان سے اتاری گئی ” لیکن اب کے شہر کیش میں۔ وہاں 23 بادشاہوں نے ساڑھے 24 برس تک حکومت کی ” تب کیش کو جنگی ہتھیاروں نے کاٹ کھایا، اور بادشاہتِ ایانا (اریک کا مقدس معبد) کو منتقل ہو گئی۔ اریک کا پہلا بادشاہ میس کیاگ گاشر تھا جو خداوند انو ( سورج) کا بیٹا تھا۔ ” وہ مندر کا مہا پروہت بھی تھا اور بادشاہ بھی۔” اتوہیگل صاحب جنہوں نے یہ فہرستِ شاہاں مرتب کروائی تھی اسی کی اولاد تھے۔
تھیو کریسی میں قانون بھی عالمِ بالا سے نازل ہوتے تھے اور ان کو مقدس او ر واجبِ تعظیم بنانے کے لیے خدا کا نام بڑی کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ مثلاً فرعون اول منیز (3400 ق۔م) نے جب بالائی اور زیریں مصر کو ملا کر اپنی سلطنت قائم کی اور پہلا قانون نافذ کیا تو یہی دعویٰ کیا کہ یہ ضابطہ قانون مجھ کو خداوند قمر (توتھ) نے عطا کیا ہے۔ منیز کے جانشینوں نے اس پر اکتفا کی بلکہ خدائی اختیارات خود سنبھال لیے۔ وہ ربِ عظیم آمون رع (سورج) کے بیٹے بن گئے۔ اس ناتے وہ مصریوں کے مذہبی پیشوا بھی تھے اور ریاست کے سربراہ بھی۔
خدائی قوانین کے نزول کا طریقہ بھی قریب قریب یکساں تھا۔ عالم بالا تک رسائی ممکن نہ تھی لہذا پہاڑ کی بلندی عالمِ بالا کی علامت ٹھہری اور بادشاہوں کو احکامِ خدا وندی پہاڑکی چوٹیوں پر عطا ہونے لگے۔ مثلاً شہنشاہ حَمُورّبی (1892۔1850 ق۔م) کے آئین کی جو کندہ شدہ لاٹ پیرس کے عجائب گھر لوور میں محفوظ ہے اس کے بالائی منظر میں خدا وند شمس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا حَمُورّبی کو آئین کا خریطہ عطا کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ حَمُورّبی کا آئین دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین ہے۔ آئین کے تمہیدی فقرے یہ ہیں:
“جس وقت ربِ عظیم اُنوم اور زمین و آسمان کے آقا ان لیل نے جو سب کی تقدیروں کا متعین کرنے والا ہےمردوک کو تمام بنی نوع انسان کا حاکم مقرر کیا اور بابل کو اس کے عظیم نام سے پکارا اور اس کو دنیا میں سب پر فضیلت بخشی اور اس کے وسط میں ایک مضبوط بادشاہت قائم کی۔ اسی وقت انوم اور ان لیل نے مجھے نامز د کیا۔ میں حَمُوربی ہوں۔ آقا مردوک جس سے خوش ہے، جس کے کارنامے عشتار دیوی کو پسند ہیں، جو قانون کا حکم منواتا ہے۔ جب مردوک نے مجھ کو ہدایت کی کہ اپنی رعایا کو راہِ راست پر لے چلوں اور ملک کی نگرانی کروں تو میں نے ملک کی زبان میں قانون اور انصاف رائج کیا۔
روایت کے مطابق جزیرہ کریٹ کے بادشاہ مینو Minos کو بھی خداوند زیوس نے قانون کی لَوحیں کوہِ دکتا پر عطا کی تھیں اور یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ قانون کے دیوتا داایونائی سَس Dionysus نے قانون کو پتھر کی دو تختیوں پرکندہ کروا کر زمین پر اُتارا۔ اور ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ زرتشت بنی نے پہاڑ پر جا کر خدا وند اُہوورمزدا سے التجا کی ۔ ” تب بجلی چمکی، آسمان گرجا اور اُہور مزدا نے پہاڑ پر اتر کر ” کتابِ قوانین ” زرتشت کے حوالے کی ” حضرتِ موسٰی ؑ کے ساتھ بھی یہی حادثہ گزرا:
” اور خداوند کوہِ سینا کی چوٹی پر اترا اور خداوند نے موسٰی کو پہاڑ کی چوٹی پر بلایا اور کہا کہ میں تجھے پتھر کی لَوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔
اسی طرح داریوش اعظم (522۔467ق۔م) اپنے ایک فرمان میں جونقش رستم کی پہاڑی کندہ ہے اعلان کرتا ہے کہ:
“خدائے عظیم اُہور مزدا کے نام سے جس نے یہ زمین خلق کی اور آسمان بھی، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے خوشیوں کو اور جس نے داریوش کو بادشاہ بنایا، بہت سے بادشاہوں کا بادشاہ اور بہتوں کا آقا، وہی ہے جس نے اس وسیع اقلیم کی شاہی ، جس میں بہت سی قومیں آباد ہیں داریوش کو بخشی۔”
یونان کی ریاست اسپارٹا میں بھی آئین آسمان ہی سے نازل ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ مشہور قانون داں لائی کرگس (آٹھویں صدی قبل مسیح )آئین سازی پر مامور ہوا تو وہ ڈیلفی گیا جو یونان کی سب سے مقدس عبادت گاہ اور غیب دانی کا مرکز تھا۔ واپس آکر اس نے اعلان کیا کہ آئین کی دفعات مجھ پر غیب سے الہام ہوئی ہیں۔ پلوٹارک لکھتا ہے کہ آئین نافذ کرتے وقت لائی کرگس نے اسپارٹا والوں سے عہد لیا تھا کہ میری واپسی تک تم لوگ آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کرو گے ۔ یہ عہد لے کر لائی کرگس ڈیلفی چلا گیا مگر کبھی نہ لوٹا۔
ملوکیت کے الوہی استحقاق میں ہندوستان ، چین اور جاپان مشرقِ وسطی سے پیچھے نہیں رہے۔ چنانچہ منوسُمرتی کے مطابق جو بعض مورخین کی رائے میں چوتھی صدی قبلِ مسیح سے پہلے کی تصنیف ہے ریاست کے سربراہ کا رتبہ دیوتا کے برابر ہے۔
” بھگوان نے راجپتی کو سب جیو کی رکشا کے لیے جنم دیا۔ وہ اندرا، وایو (ہوا ) یَم ( موت ) سُوریہ (سورج) اگنی، ورونا، چندرما اور کُوبیر (دولت کا دیوتا) کے ابدی ذرات کا آمیزہ ہے۔ وہ منوش کے روپ میں مہادیو ہے۔ پس خبردار! کوئی شخص راجہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے خواہ ان احکام کا تعلق انعام سے ہو یا سزا اور خفگی سے ۔”
منوریاست کی قوتِ قاہرہ پر بالکل پردہ نہیں ڈالتا بلکہ سزا کو بھی مقدس عمل سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ ” ڈنڈا برہما دیوتا کا بیٹا ہے اور تمام مخلوق کا محافظ۔ عقل مندوں کے نزدیک قانون اور ڈنڈا ہم معنی الفاظ ہیں۔”
چین کے فرماں روا بھی ” آسمان کی اولاد” Tien-tse کہلاتے تھے اورزمین پر خدائے عرش کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ ریاست کے سربراہ اور مذہب کے پیشوا بھی ہوتے تھے۔ ان کے ہر حکم کو احکامِ خداوندی کا درجہ حاصل تھا اور ان کا فیصلہ خدا کا فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ کو اگر جنگ میں شکست ہو جاتی یا قحط پڑ جاتا یا کوئی دشمن اس کو تخت سے اتار دیتا تو تاویل یہ کی جاتی تھی کہ خدا نے اس کو اپنی خلافت سے محروم کردیا ہے۔ خدا کی یہ خود ساختہ اولاد 1911ء تک انہیں لغود عوؤں کے ساتھ چین پر حکومت کرتی رہی اور تب وہاں جمہوری انقلاب آیا اور اس آسمانی بادشاہت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔
جاپان میں 1945ء تک یہی صورت رہی۔ وہاں شہنشاہ کا لقب ” سورج دیوتا” تھا اور جاپانیوں کی عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص شہنشاہ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرات نہیں کرسکتا تھا۔ یہی ذاتِ شریف اب بھی جاپان کے شہنشاہ کہلاتے ہیں لیکن دوسری جنگِ عظیم کے بعد وہاں جب پارلیمانی جمہوریت قائم ہوئی تو شہنشاہ کی حیثیت شاہِ شطرنج کی ہو گئی۔
یہودی، نصرانی اور اسلامی عقائد کے مطابق پیغمبری اور بادشاہی کا دہرا منصب خدانے سب سے پہلے حضرت داؤدؑ کو عطا کیا۔ ان سے پیش تر کوئی پیغمبر سیاسی اقتدار کا طلب گار نہیں ہوا اور نہ خدا نے اس کو سیاسی اقتدار سونپا حتیٰ کہ حضرت موسیٰؑ کو بھی جو بنی اسرائیل کے نجات دہندہ تھے ریاست کی سربراہی نصیب نہیں ہوئی پھر وہ کون سے معاشرتی حالات تھے جن کے باعث ایک دیرینہ روایت ترک کردی گئی اور ایک نئی روایت کی ریت پڑی؟
بنی اسرائیل 430 سال تک مصر میں رہنے کے بعد جب 1220 ق۔م میں وہاں سے نکلے تو بائبل کی کتاب خروج کے بقول ان کی تعداد چھ لاکھ سے بھی زیادہ تھی جو یقیناً مبالغہ ہے۔ یہ لوگ بارہ قبیلوں اور سینکڑوں خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا اور ایک مجلسِ بزرگان جو سن رسیدہ اشخاص پر مشتمل ہوتی تھی۔ یہی مجلسِ بزرگان قبیلے کی عدالت کے فرائض انجام دیتی تھی ۔ قبائل فقط ہنگامی حالات میں آپس میں تعاون کرتے تھے۔ وہ اتنے خود مختار اور خود سر تھے کہ حضرتِ موسیٰؑ کو سفر کے دوران ان کو متحد رکھنے اور احکامِ ربّانی کی اطاقت پرآمادہ کرنے میں بڑی بری مشکلیں پیش آئیں۔ چالیس سال تک سینا اور فاران کے بیابانوں میں خاک چھاننے کے بعد آخر کار یہ انبوہِ کثیر کنعان میں داخل ہوا جہاں اُن دنوں عملیقیوں، موابیوں، فلسطیوں وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں قائم تھیں۔ بنی اسرائیل نے لاکھوں باشندوں کو جان سے مارا اور ان کے کھیتوں، باغوں اور تاکستانوں پر قبضہ کرلیا۔ غارت گری اور تسخیر کا یہ سلسلہ عرصے تک جاری رہا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے قبیلے الگ الگ علاقوں میں آباد ہو گئے۔
مگر ارضِ مقدس میں مستقل بود و باش کے با وصف بنی اسرائیل کا معاشرتی نظام بدستور قبیلہ داری رہا۔ البتہ جگہ جگہ “قاضی” مقرر کر دیے گئے جو شریعتِ موسوی کے مطابق فیصلے صادر کرتے تھے۔ یہ تھیو کریسی کی ابتدائی شکل تھی لیکن اس وقت تک کوئی اسرائیلی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی اور نہ کسی شخص کو شاہی اختیارات حاصل تھے چنانچہ بائبل کی کتاب ” قضاۃ” میں اس بات کو کئی بار دہرایا گیا ہے کہ ” اُن دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔”
اسرائیلیوں نے کنعان کے قدیم باشندوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا اس کی وجہ سے آس پاس کی غیر اسرائیلی ریاستیں ان سے سخت نفرت کرتی تھیں اور اسرائیلیوں کو ہر دم ان کے حملے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ مفت کی دولت ہاتھ آنے اور ذاتی ملکیت کے رواج پانے کے باعث اسرائیلی قبیلوں کے مابین لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور قبیلوں کے اندر بھی طبقاتی اُونچ نیچ پیدا ہو گئی تھی۔ ان حالات میں کسی مرکزی طاقت کا قیام وقت کی اہم ضرورت بن گیا ۔
اس مرکزی طاقت کے وجود میں آنے کی داستان بائبل کی کتاب “سموئیل” میں بڑاے ڈرامائی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یہ اُن دنوں کا واقعہ ہے جب سموئیل بنی اسرائیلیوں “قاضی القضاۃ” تھے۔ مولانا مودودی کا یہ بیان کہ “سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل پر حکومت کرتے تھے” غلط ہے۔ کیونکہ وہ جس کتابِ سموئیل سے استنباط کرتے ہیں اس میں سموئیل کو قاضی کہا گیا ہے نہ کہ حاکمِ وقت۔
“وہ زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا اور وہ سال بہ سال بیت ایل اور جلجال اور مصفاہ میں دورہ کرتا اور ان سب مقاموں میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ پھر وہ رامہ میں لوٹ آتا کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا اور وہاں اسرائیل کی عدالت کرتا اور وہیں اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔
جب سموئیل بُڈھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کا قاضی ٹھہرایا پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کردیتے تھے۔
تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر رامہ میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ ” دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے۔
سموئیل بنی بادشاہت کی اصل حقیقت سے واقف تھا لہذا اس کو اسرائیلی بزرگوں کی تجویز بہت بری لگی اور اس نے خدا سے شکایت کی۔ خدا نے کہا کہ تو ان کی بات ما ن لے البتہ ان کو جتا دے کہ بادشاہی کیا شے ہوتی ہے۔
” اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو اس بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں اورا س نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے اور وہ ان کو ہزار ہزار کے سردار اور پچاس پچاس کے جمع دار بنائے گا اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر کُندھن اور باورچن اور نان ینپر بنائے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمت گاروں کو عطا کرے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا دسواں حصہ لے کر اپنے خوجوں اور خادموں کو دے گا اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا اور تمہارے بھیڑ بکریوں کا دسواں حصہ لے گا تم اس کے غلا م بنا جاؤ گے۔”
مگر بادشاہت کی یہ نہایت سچی تصویر بھی اسرائیلیوں کو ان کی ضد سے باز نہ رکھ سکی اور و ہ کہنے لگے ” نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تاکہ ہم بھی اور قوموں کی مانند ہوں اور ہمارا بادشاہ عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔”
آخر مجبور ہو کر سموئیل نے ساؤل کو بادشاہ مقرر کردیا جو قبیلہ بنی یامین کے ایک ” زبردست سورما” کا بیٹا تھا۔
ساؤل نے اسرائیلیوں پر تیرہ سال (1025۔1012 ق۔م) بادشاہت کی لیکن سموئیل بنی سے اس کی کبھی نہیں بنی۔ آخر کار ساؤل کی حرکتوں سے خدا بھی ناراض ہو گیا اور خدا نے ساؤل کی موت کے بعد بادشاہت اس کی اولاد کے بجائے حضرت داؤدؑ کو سونپ دی جو ساؤل کے اسلحہ بردار تھے اور بنی اسرائیل کے سب سے بڑ ے قبیلے یہوداہ سے تلعق رکھتے تھے۔
ساؤل کے خدا کی طرف سے مامور بہ خلافت ہونے قصّہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے البتہ تفصیلات بائبل سے قدرے مختلف ہیں۔
حضرت داؤد کو شہرت اس وقت ملی جب اُنہوں نے فلسطیوں کے پہلوان جالوت کو جس سے ساؤل کو کوئی سورما لڑنے کی جرات نہ کرتا تھا میدانِ جنگ میں قتل کر دیا۔ ساؤل کو یہ اندیشہ ہوا کہ مبادا داؤدؑ میرے بعد تختِ شاہی کا دعوے دار بن جائے لہذا وہ داؤدؑ کی جان کے درپے ہو گیا لیکن داؤدؑ اس کے چنگل سے بچ نکلے۔ ساؤل کی موت کے بعد خدا نے داؤد کو اسرائیلیوں کا بادشاہ مقرر کردیا:
آخر کار اللہ کے اِذن سے اُنہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤدؑ نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کا علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔
اس طرح امامت اور خلافت کے عہدے جو ساؤل کے وقت میں جد اجدا منصب تھے ایک ہی شخص کو مل گئے۔ البتہ حضرت داؤدؑ کے بیٹے حضرت سلیمانؑ کے بعد امامت اور خلافت کے عہدے دوبارہ الگ کردیے گئے۔ شاید تجربہ کامیاب ثابے نہیں ہوا۔
عہدِ قدیم میں الوہی استحقاق کا ریاستی نظریہ ایک عالمگیر عقیدے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ کافر، مشرک اور مومن سب کا خیال تھا کہ ریاست کی سربراہی اور ریاست کے بنیادی قوانین عالمِ بالا سے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی حاکمیت اور قانون کا مخرج و منبع ریاست کے باشندے نہیں بلکہ کوئی مافوق الفطرت طاقت ہے۔ وہی جس کو چاہتی ہے اقتدار عطا کرتی ہے اور جس کو چاہتی ہے اس نعمت سے محروم کردیتی ہے۔ رعایا کا فرض حاکمِ وقت کی اطاعت اور قوانین کی پابندی کرنا ہے۔
پروہتی راج کے نظریے ملوکیت کے دور میں بدستور رائج رہے کیونکہ ان کی تبلیغ و اشاعت بادشاہوں کے مفاد میں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پروہت راج کے خاتمے کے بعد حالاتِ زیست میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ پرانا اقتصادی ڈھانچہ جوں کا توں رہا۔ نہ آلاتِ پیداوار بدلے نہ پیداواری رشتوں میں فرق آیا۔ پروہت راج میں زمین عبادت گاہوں کی ملکیت ہوتی تھیں۔ بادشاہی دور میں زمین بادشاہ اور امرائے سلطنت کی ملکیت بن گئی۔ کاشت کار، مزدور اور غلام ارسطو کے بقول “زندہ آلات” تھے سو زندہ آلات رہے۔ پرانا زرعی نظام بدستور قائم رہا۔ فقط آقا بدل گئے۔
یوں بھی زرعی نظام میں کوئی اور نظریہ رواج نہیں پا سکتا تھا کیونکہ زراعت پیشہ لوگ قدرت کے رحم و کرم پر ہوتے تھے۔ علم و شعور کی کمی کی وجہ سے وہ مظاہرِ قدرت کے اسباب و علل کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ بارش، سیلاب، خشک سالی، اولے پالے کسی پر ان کا اختیار نہ تھا۔ مذہبی پیشوا بھی ان کو یہی باور کراتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے آسمانی طاقتوں کی مرضی سے ہوتا ہے لہذا لوگوں کی نظریں آسمان ہی کی طرف لگی رہتی تھیں۔ ان کی اپنی زندگی بھی حاکمِ وقت کی مرضی پر منحصر تھی۔ ان حالات میں لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ ریاست اور ریاست کے قوانین آسمان سےاترتے ہیں زیادہ دشوار نہ تھا۔
مگر تھیو کریسی فیوڈل ازم کا ریاستی نظریہ ہی نہیں معاشرے کا ضابطہ حیات بھی تھی۔ پیدائش سے موت تک زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہ تھا جس سے انسان مذہبی احکام ادا کیے بغیر گزر سکتا۔ ولادت کی رسمیں، مونڈن کی رسمیں، خواندگی کی رسمیں، مذہبی تیوہاروں کی رسمیں، بالغ ہونے کی رسمیں، منگنی اور شادی بیاہ کی رسمیں، تجہیزو تکفین کی رسمیں، جو مُردے کے جلانے یا دفن کرنے کے بعد بھی جاری رہتی تھیں۔ ان کے علاوہ غسل کرنے، دانت صاف کرنے، اٹھنے بیٹھنے ، کھانا کھانے، سونے حتٰی کہ عورت کے ساتھ ہم بستیری آداب بھی مقرر تھے۔ پوجا پاٹ کے قاعدے ان پر مستزاد تھے۔
تھیو کریسی کی افیون لیکن عوام ہی کا مقدر تھی۔ بادشاہ، شاہی خاندان کے افراد، اور امراء و رؤسا شرعی احکام پر بس واجبی واجبی عمل کرتے تھے۔ بادشاہ اپنے سوا کسی دوسری ریاست کے فرماں روا کے الوہی حق کو تسلیم نہیں کرتا تھا بلکہ موقع ملتے ہی اس پر لشکر کشی کردیتا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد اور امرا بھی بادشاہ کے خلاف سازشوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے ورنہ زمین پر خدا کے نائب وقتاً فوقتاً قتل نہ ہوتے اور نہ شاہی خاندان بدلتے رہتے۔ کوئی زہر سے ہلاک ہوتا تھا کوئی آبِ شمشیر سے۔ اسرائیل کے اُنیس بادشاہوں میں سے آٹھ قتل ہوئے۔ قریب قریب یہی اوسط قیصرانِ روم کی ہلاکت کی بھی ہے جو دیوتا کہلاتے تھے۔ ایران کے قاچاری بادشاہوں میں فقط ایک کو قدرتی موت نصیب ہوئی۔ سلاطینِ دہلی کو بھی انہیں حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ خاندانِ غلاماں کے گیارہ میں پانچ بادشاہ قتل یا برطرف ہوئے، خلجیوں میں سے چھ میں سے چار اور تغلقوں میں نو میں سے پانچ پر یہی آفت آئی۔ سلطنتِ مغلیہ کے کل اٹھارہ بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ ان میں آخری بارہ قتل اوربرطرف ہوئے یا اندھے کردیے گئے۔
ریاست اور رعایا کا مذہب جب تک ایک رہا شرعی قوانین کے نفاذ میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی لیکن ریاستیں جب سلطنتوں میں بدل گئیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رعایا بن گئے تو رعیت اور ریاست میں تصادم نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ مثلاً بنی اسرائیل خدائے واحد کے ماننے والے اور شریعتِ موسوی کے پابند تھے۔ اسرائیلی علاقوں پر جب رومیوں نے قبضہ کر کے اپنے قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی تو اسرائیلیوں نے ان قوانین کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ نوبت کُشت و خون تک پہنچی۔ آخر طے یہ پایا کہ یہودیوں کے آپس کے مقدموں کا فیصلہ بدستور یہودی عدالتیں کریں البتہ سلطنت کے شہری ہونے کی حیثیت سے یہودیوں کو عام رومی قوانین کی پابندی کرنی ہو گی۔ اسی تجربے کی روشنی میں حضرتِ مسیحؑ نے اپنے ماننے والوں یہ مشورہ دیا تھا کہ ” سیزر کو اس کا حق دو اور خدا کو اس کا حق” اُنہوں نے ریاست کو مذہب سے جدا کردیا۔
دورِ حاضر کے بعض علمائے دین کو حضرتِ مسیحؑ کے اس قول پر سخت اعتراض ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست میں کسی مذہب کے پَیرو اگر اقلیت میں ہوں تو ریاستی قوانین کے بارے میں ان کا طرزِ عمل کیا ہونا چاہیے۔ برطانوی عہد میں مسلمان اقلیت میں تھے۔ چنانچہ اُنہوں نے بھی دوسروں کی طرح انگریزی قوانین کی پیروی کی اور حضرتِ مسیحؑ کے مشورے پر حرف بہ حرف عمل کیا۔ انگریزوں نے فوجداری کے ضابطے اور قوانین تو بلا لحاظِ مذہب و مِلت پورے ملک میں نافذ کر دیے البتہ سِول قوانین میں جن امور کا تعلق خالص مذہبی عقائد سے تھا ان کے بارے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے الگ الگ قوانین بنا دیے۔ مثلاً شادی اور طلاق، وراثت، اوقاف، عبادت گاہوں اور دینی درس گاہوں کی دیکھ بھال۔ آج بھی مسلمان اقلیت کی حیثیت میں ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکا، برما، تھائی لینڈ اور چین میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور کے لیے “سیزر کا حق” ادا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔
ملوکیت میں بادشاہ کا مذہب ریاست کا سرکاری مذہب ہوتا تھا اور قوانین بھی مذہبی احکام کے مطابق وضع ہوتے تھے لیکن اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مطلق العنان بادشاہوں کے عہد میں مذہب ریاست کے تابع ہو گیا اور ریاست کی سیاسی مصلحتوں کو شرعی احکام پر ترجیح دی جانے لگی۔ شرعی احکام اگر سیاسی مصلحتوں سے ہم آہنگ ہوتے تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جاتا مگر ریاست کی بنیادی حکمتِ عملی اور شرعی احکام میں اگر تصادم کی صورت پیدا ہوتی تو تنخواہ دار پادریوں، پنڈتوں اور مفتیوں سے ریاست کے حق میں فیصلے حاصل کر لیے جاتے تھے اور شرعی احکام کو نظر انداز کردیا جاتا تھا۔
تھیوکریسی میں سربراہِ مملکت اور مذہبی ادارے چکی کے دو پاٹ تھے عوام جن کے درمیان پستے رہتے تھے۔ دونوں کے اختیارات کا سر چشمہ خداکی ذات تھی یا احکامِ خداوندی۔ ” عوام کالانعام” مویشی تھے لہذا ریاست کے نظم و نسق میں ان کی کوئی آواز نہ تھی۔ ملک کا معاشرتی اور معاشی نظام کیا ہو۔ عنانِ اقتدار کن لوگوں کے ہاتھ میں ہو، طرزِ حکومت کیسی ہو، قانون کون وضع کرے، ان پر عمل در آمد کی کیا صورت ہو اور عدالتیں کس نوع کی ہوں ان تمام امور کا فیصلہ بحق سربراہ محفوظ تھا اور وہ کسی کے رُو برو جواب دہ نہیں تھا نہ کوئی اس سے باز پرس کر سکتا تھا۔
مذہبی پیشوا سربراہِ ریاست سے پورا پورا تعاون کرتے تھے اور اس تعاون کا خاطر خواہ معاوضہ پاتے تھے۔ کوئی قاضی بنتا تھا، کوئی مفتی اور محتسب۔ جن کو یہ عہدے نہ ملتے وہ عقیدت مندوں کو اطاعت و فرماں برداری کا درس دے کر اپنی دنیا اور ان کی عاقبت درست کرتے رہتے تھے اور وہ عالم فاضل بزرگ جن کو لکھنا آتا تھا ہماری دیدہ عبرت نگاہ کے لیے اپنی اطاعت گزار فہم و فراست کے ایسے ایسے نادر شاہ کار چھوڑ گئے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر ان کے مشوروں پر عمل کیا ہوتا تو ترکی ، ایران اور مصر میں مطلق العنان ملوکیت آج بھی مسلط ہوتی اور الجزائر، لیبیا اور شام وغیرہ بدستور مغربی سامراج کے قبضے میں ہوتے۔
2
پروہت راج کے خاتمے کے بعد مذہبی پیشوا مشرق میں سیاسی اقتدار کے مالک کبھی نہیں ہوئے اور نہ اُنہوں نے کبھی تاج و تخت کی آرزو کی ۔ ہندو راجاؤں کے زمانے میں راج پاٹ کرنا دھرم شاستر کی رُو سے چھتریوں کا منصب قرار پایا اور برہمن پنڈتوں کا کام راجاؤں کو مشورے دینا اور دھرم کی حفاظت کرنا ٹھہرا۔ مسلمانوں میں بھی خلافتِ بنی اُمیّہ سے لے کر خلافتِ آلِ عثمان اور سلطنتِ مغلیہ تک کسی دور میں بھی مذہبی پیشوا ریاست کے سربراہ نہیں ہوئے۔ کلیسائے روم کی مانند یہاں کوئی مذہبی مرکز بھی قائم نہ ہو سکا جو بجائے خود ریاست ہوتا یا بادشاہوں کے سیاسی اقتدار کو چیلنج کرنے کی جرات کرتا۔ اگر کسی مذہبی پیشوا نے ریاست کے غیر شرعی طرزِ عمل سے اختلاف کیا تو اس کو قتل یا قید کردیا گیا یا جسمانی اذیتیں پہنچا کر راستے سے ہٹا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے بارہ سال قید میں گزارے اور قید خانے ہی میں انتقال فرمایا۔ امام احمد بن حنبل کو ننگی پیٹھ پر کوڑے لگائے گئے۔ یہی سزا مدینے کے عباسی گورنر جعفر ابن سلیمان امام مالک کو دی جس سے ان کا کندھا اکھڑ گیا۔ قدری اور معتزلہ فرقے سوادِ اعظم کی نظر میں کافر تھے لہذا ان کے قتل میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی اور جب خلیفہ مامون رشید کے عہد میں ان کا ستارہ چمکا تو اُنہوں نے اپنے مخالف علما کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان سے پیش تر ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اشراقی صوفی اور عالمِ دین شیخ شہاب الدین سہروردی مقتول سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم سے شہید کیے گئے کیونکہ ان کی تعلیمات “اسلام کے لیے خطرہ ” تھیں۔ غرضیکہ اسلامی ریاستوں میں علمائے دین اقتدار سے منسلک ہو کر مختلف سرکاری خدمات بجا لاتے رہے یا دربار سے دور رہ کر مذہب کی تعلیم دیتے رہے مگر اُنہوں نے عملی سیاست سے اپنا دامن حتی الوسع پاک رکھا۔
اس کے برعکس مغرب میں مسیحی کلیسا بڑی طاقت ور سیاسی قوت بن کر ابھرا۔ رومتہ الکبریٰ کے غیر مسیحی عہد میں تو کتنے ہی پوپ اور پادری روم میں مصلوب ہوئے اور عیسائیوں کا خون بڑے بے دردی سے بہایا گیا شہنشاہ قسطنطین اوّل (274۔337) نے جب عیسائی مذہب اختیار کیا اور عیسائیت سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پائی تو کلیسا کا وقار بہت بڑھ گیا۔
پوپ کا دعویٰ تھا کہ وہ زمین پر یسوع مسیح کا خلیفہ ہے اور عیسائیت چونکہ سلطنت کا سرکاری مذہب ہے لہذا قوانین دین مسیحی کے مطابق و ضع ہونے چاہئیں اور عدالتیں مذہبی ہونی چاہئیں۔ دین مسیحی کی تشریح اور تاویل کا حق فقط پوپ کو حاصل ہے لہذا مقننّہ اور عدلیہ دونوں کلیسا کے اثر و اقتدار میں اسی نسبت سے اضافہ ہوا۔ پوپ کے مقرر کردہ پادری لاکھوں کی تعداد میں شہروں شہروں قریوں قریوں پھیل گئے۔ جس طرح ریاست میں عہدے داروں کی درجہ بندی ہوتی ہے اُسی طرح کلیسا مین بھی پادریون کے درجے مقرر ہوئے۔ کارڈنیل، آرچ بشپ، بشپ، گاؤں کا پادری، سب کو پوپ نامزد کرتا تھا اور وہ پوپ کے علاوہ کسی کا حکم ماننے پر مجبور نہ تھے۔ ان پر ریاستی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا بلکہ ان کی مذہبی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل در آمد کرنا حکومت کا فرض تھا۔ وہ اگر کسی نومولود کو بپتسمہ نہ دیتے تو وہ ذات سے باہر ہو جاتا تھا۔ اگر کسی کا نکاح نہ پڑھتے تو اس کی اولاد حق وراثت سے محروم کردی جاتی تھی۔ اگروہ کسی کی آخری رسم ادا نہ کرتے یا نمازِ جنازہ نہ پڑھتے تو اس کا مقام جہنم ہوتا۔ پادریوں کے سوا کوئی شخص بچوں کو پڑھا نہیں سکتا تھا نہ مدرسہ قائم کر سکتا تھا۔ کلیسا انسان کی پوری زندگی پر حاوی تھا۔
مگر کلیسا فقط روحانی طاقت نہ تھی بلکہ یورپ کا سب سے دولت مند اور سب سے بڑا جاگیر دار بھی رومن کلیسا ہی تھا۔ اسپین میں ملک کی چوتھائی زمین کلیسا کی ملکیت تھی۔ برطانیہ میں زمین کا پانچواں حصہ، جرمنی میں تیسرا حصہ اور فرانس میں نصف رقبہ کلیسا کے قبضے میں تھا۔ ضلع لانگرے کا بشپ پورے ضلعے کا مالک تھا۔ اٹلی کے شہر بولونیا کے دو ہزار گاؤں کلیسا کی ملکیت تھے۔ اسپین میں کلیسا64 قصبوں کا مالک تھی۔ فُلدا کی خانقاہ 15 ہزار گاؤں کی مالک تھی۔ سینٹ گال کی خانقاہ کے پاس دو ہزار چاکر تھے، شہر ٹور کے پادری کے پاس بیس ہزار چاکرتھے۔ یہ سب زمینیں معافی تھیں جن پر کوئی محصول نہ تھا اور نہ حکومت ان کے معاملات میں کوئی مداخلت کرسکتی تھی۔ ایک مورخ کے بقول ” فیوڈلزم نے کلیسا کو بھی فیوڈل بنا دیا تھا”۔ اس کے علاوہ اپنی آمدنی اور پیداوار کا دسواں حصہ کلیسا کو ادا کرنا ہر شخص کا قانونی فریضہ تھا۔ گرجا گھروں کو چڑھاؤں اور نذرانوں سے بھی وافر رقمیں وصول ہوتی تھیں۔ مزید برآں صاحبِ جائیداد افراد حتیٰ کہ مزار عوں سے بھی یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ مرتے وقت کلیسا کے نام کچھ نہ کچھ ترکہ ضرور چھوڑ جائیں ورنہ وہ بے دین تصور کیے جائیں گے اور جہنم میں جلیں گے۔ آٹھویں صدی عیسوی میں جب وسطی اٹلی کا بہت بڑا علاقہ کلیسا کے قبضے میں آگیا تو کلیسا ایک خود مختار ریاست بن گئی اور پوپ ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے یورپ کی سیاست میں براہِ راست حصہ لینے لگے۔
پوپ اور دوسرے بڑے پادری اطالوی ریاستوں کے شاہی خاندان سے چُنے جاتے تھے اور شاہانہ ٹھاٹ باٹھ سے رہتے تھے۔ وہ شادی نہیں کر سکتے تھے لیکن علانیہ داشتائیں رکھتے تھے اور ان کی اولاد شہزادوں کی سی زندگی گزارتی تھی۔ کلیسا کی دولت کا سر چشمہ زمینیں تھیں اور پادری بھی فیوڈل ماحول کے پروردہ ہوتے تھے لہذا ان کا قدرتی جھکاؤ فیوڈل عناصر کی جانب تھا۔ فیوڈل امرا کی طرح وہ بھی تاجروں اور صنعت کاروں کو بڑی حقارت سے دیکھتے تھے چنانچہ ان کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کی غرض سے سودی کاروبار کی سختی ممانعت کر دی گئی تھی۔
کلیسا روم کی پہلی ٹکّر فرانس، جرمنی، اسپین اور برطانیہ کے بادشاہوں سے ہوئی۔ بادشاہ پوپ کے روحانی اقتدار کو تو تسلیم کرتے تھے مگر پوپ کے اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ امورِ ریاست میں بھی پوپ کی اطاعت بادشاہوں کا فرض ہے۔ بادشاہوں کو کلیسا سے یہ شکایت بھی تھی کہ پوپ اور دوسرے بڑے پادری بادشاہ کے مقابلے میں نیم خود مختار نوابوں کی پُشت پناہی کرتے ہیں اور ان کو کلیسا کا عہدے دار بنا دیتے ہیں۔ چودھویں صدی میں کلیسا اور ملوکیت کے مابین نزاع نے اتنی شدت اختیار کی لی کہ فرانس کے بادشا ہ فلپ چہارم نے روم پر دھاوا کر کے پوپ کلیموں پنجم کو گرفتار کر لیا اور کلیسا کا صدر مقام شہر اَوِنیان میں منتقل کردیا۔ پاپائے روم کو وہاں ستر سال تک (1309۔1378ء) فرانس کی نگرانی میں رہنا پڑا۔ 1378ء میں اگرچہ پوپ رہا ہو کر روم واپس آیا لیکن کلیسا کا پرانا اثرو اقتدار پھر کبھی بحال نہ ہو سکا۔
مغربی مورخین کلیسا کے ہزار سالہ اقتدار کو ” عہدِ تاریک” سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اس وجہ سے کہ وہاں چوتھی صدی سے چودھویں صدی تک تعصب ، تنگ نظری اور توہم پرستی کا اندھیرا چھایا رہا۔ کلیسا نے عقل و خِردپر پہرے بٹھا رکھے تھے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ کلیسائی عقائد سے سرِ مو اختلاف کر سکے۔ ہر جگہ مذہبی عدالتیں قائم تھیں جن کے فیصلوں کی داد تھی نہ فریاد چنانچہ لاکھوں بے گناہ بے دینی اور جادو گری کے جرم میں گرفتار ہوئے۔ ان کو ٹکٹکی پر باندھ کر پہلے کوڑے لگائے جاتے تھے پھر ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھیں۔ ان کی لاشوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جاتا تھا اور تب چتا میں جلا دیا جاتا تھا۔ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی تھی اور ان کا مال و متاع ضبط کر لیا جاتا تھا۔ یورپ کا ہر فردِ بشر، جس کو بادشاہوں کی براہِ راست سر پرستی حاصل نہ تھی مذہبی عدالتوں کے خوف سے کانپتا رہتا تھا۔
اس ہولناک ماحول میں علوم و فنون کیا ترقی کرتے۔ تعلیم کلیسا کی اجارہ داری تھی لہذا درس گاہوں میں فقط وہی علوم پڑھائے جاتے تھے جن سے کلیسائی عقائد کو تقویت ملتی۔ معقولات کی جگہ منقولات، درایت کی جگہ روایت اور اجتہاد کی جگہ تقلید۔ کسی استاد یا شاگرد کو شرعی احکام پر شک کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ کلیسا کی خرِد دشمنی نے ذہنوں کو مفلوج کردیا تھا اور کوئی شخص آزادی سے سوچ نہ سکتا تھا۔
لیکن قرونِ وسطیٰ کے آخری دنوں میں جب یورپ الخصوص اٹلی میں صنعت و حرفت اور تجارت نے ترقی کی تو حالات بدلنے لگے۔ کلیسا یورپ کا سب سے بڑا زمیندا تھا لہذا سرمایہ دار طبقے کے فروغ سے دوسرے فیوڈل عناصر کی طرح کلیسا کے مفاد و اقتدار پر بھی کاری ضرب لگی۔ وینس، فلورنس، جینوا اور مِلان بڑے خوش حال شہر تھے۔ وہاں تاجر پیشہ طبقوں کی جمہوری ریاستیں قائم تھیں۔ وینس میں لوہے، ریشمی کپڑوں، زردوزی اور شیشہ سازی کے بڑے بڑے کارخانے تھے۔ اس کے پاس دو سو تجارتی جہاز تھے جو مال لے کر مصر، تونس، ترکی اور اسپین تک جاتے تھے۔ فلورنس بھی بہت بڑی مندی تھا۔ وہاں اسّی بینک روپے کا لین دین کرتے تھے اور اونی کپڑوں کی تین سو فیکٹریاں تھیں جن میں تیس ہزار مزدور کام کرتے تھے۔ جینوا میں کمخواب بنتا تھا اور طلائی کام ہوتا تھا ۔ غرضیکہ نوزائیدہ سرمایہ دار طبقے نے اٹلی کے سب ہی بڑے شہروں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔
شہروں میں صنعت و حرفت اور تجارت کے فروغ کا اثر دیہاتی زندگی پر بھی پڑا۔ فیکٹریوں اور بندرگاہوں میں محنت کاروں کی مانگ بڑھی تو نوابوں اور پادریوں کی زمینوں سے بندھے ہوئے چیرے (زرعی غلام) بھاگ بھاگ کر شہروں میں پناہ لینے لگے۔ فلورنس نے اعلان کیا کہ ریاست میں پناہ لینے والا ہر زرعی غلام آزاد شہری تصور کیا جائے گا اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ دوسرے شہروں نے بھی زرعی غلاموں کی حوصلہ افزائی کی۔ نوابوں اور پادریوں کا طبقہ شہر کے نودولتیوں سے پہلے ہی نفرت کرتا تھا زرعی غلاموں کے بھاگنے کی وجہ سے سرمایہ دار طبقے کے تعلقات نوابوں اور پادریوں سے اور کشیدہ ہو گئے۔
اُنھی دنوں مغربی یورپ کے تجارتی مراکز میں بھی کارواری طبقے کی طاقت میں اضافہ ہوا اور بادشاہوں نے نوابوں اور پادریوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی خاطر سرمایہ داروں کی حوصلہ افزائی کی۔ برطانیہ میں لندن اور دوسرے کئی شہروں کو بلدیاتی اختیارات حاصل ہو گئے۔ البتہ یورپ میں کلیسا نے بلدیاتی اختیارات کی شدت سے مخالفت کی نتیجہ یہ ہوا کہ فرانس میں کئی جگہوں پر شہریوں کو کلیسا سے باقاعدہ مسلح جنگ لڑنی پڑی۔ بہت سے پادری ہلاک ہوئے اور گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ آخر کار کلیسا کو شکست ہوئی اور مغربی یورپ کے بیش تر شہروں مثلاً مارسیلز، ہمبرگ اور ایمسٹرڈم وغیرہ کو بھی بلدیاتی حقوق مل گئے۔
مگر تجارتی مال و اسباب کی نقل و حرکت میں یورپ کی خود مختاری نوابیاں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں۔ ہر چند کہ نواب اپنے بادشاہ کی وفاداری کا دم بھرتے تھے لیکن نوابی کے اندر اُنھیں کا حکم چلتا تھا۔ ان کی اپنی عدالتیں، جیل خانے، پولیس اور فوج تھی۔ تاجروں کو ہر نوابی سے گزرتے وقت محصول ادا کرنا پڑتا اور نواب کو خوش کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً دریائے رھائن پر 62 چنگیاں تھیں، دریائے لوائر (فرانس) پر 74، دریائے اِلب (جرمنی) پر 35 اور دریائے ڈینوب پر 77۔ اگر کسی سوداگر کا مال اتفاق سے سڑک پر گر جاتا تو وہ بحق سرکار ضبط ہو جاتا۔ سرمایہ داروں اور نوابوں میں نزاع کا بڑا سبب چنگیاں اور دوسری ناجائز وصولیاں تھیں۔ سرمایہ داروں نے ان چنگیوں کو توڑنے کا مطالبہ کیا تو بادشاہوں نے ان کی حمایت کردی۔
اسی اثنا میں امریکا اور ہندوستان کے بحری راستے دریافت ہوگئے تو بین الاقوامی تجارت کی راہیں کھل گئیں مگر تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کا مرکز اب اٹلی سے مغربی یورپ میں منتقل ہوگیا۔ امریکا اور ہندوستان سے تجارت کرنے کی غرض سے اسپین، پرتگال، ہالینڈ، فرانس اور برطانیہ میں نئی نئی تجارتی کمپنیاں قائم ہونے لگیں (ایسٹ انڈیاں کمپنی 1600ء میں قائم ہوئی تھی) نو آبادیاتی نظام کی داغ بیل پڑی اور جہاز سازی کی صنعت نے بہت ترقی کی۔
اسی دوران جرمنی میں چھاپہ خانہ ایجاد ہوا (1465ء) جس کے اثرات بہت دُور رس ثابت ہوئے۔ کتابوں اور رسالوں کی اشاعت سے پادریوں کی ذہنی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ خواندگی میں بھی اضافہ ہوا اور لوگ کتابوں کے لیے پادریوں کے محتاج نہ رہے بلکہ اپنی مرضی سے جو کتاب چاہتے بازار سے خرید لیتے۔ ابھی تک تصنیف و تالیف بیش تر پادریوں کے حلقے تک محدود تھی۔ چھاپے خانوں کے قائم ہو جانے کے بعد وہ مصنف بھی منظرِ عام پر آئے جن کا تعلق کلیسا سے نہ تھا۔ ایسے رسالے بھی شائع ہونے لگے جن میں پادریوں اور راہباؤں کی بدچلنی اور دنیاوی حرص و ہوس کے قصے مزے لے لے کر بیان کیے جاتے تھے۔
سائنسی ایجادیں اور دریافتیں بھی اسی زمانے میں شروع ہوئیں اور سائنسی اندازِ فکر و نظر کی داغ بیل پڑی۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ سائنسی نظریے اور ایجادیں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان کا گردو پیش کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ اتفاقاً ہو جاتا ہے حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ گلیو کی دُور بین ہو یا نیوٹن کا کششِ ثقل کا نظریہ، بھاپ سے چلنے والے انجن کی ایجاد ہو یا برقی قوت کی دریافت، سب کے ٹھوس سماجی محرکات تھے۔ ان نئی سائنسی دریافتوں سے کلیسائی عقائد و افکار کے ایوان میں زلزلہ آگیا۔ کلیسا نے نظامِ بطلیموس کو اپنے مذہب کا جُز بنا لیا تھا۔ کوپرنی کس، گلیو اور کپلر نے ثابت کر دیا کہ زمین دوسرے سیاروں کی طرح سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کلیسا کا دعویٰ تھا کہ زمین فرش کی مانند پانی پر بچھی ہوئی ہے۔ سائنس دانوں نے ثابت کردیا کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر گردش کرتی ہے۔ اسی طرح کلیسا کے دوسرے مفروضات واذغان کی نفی ہونے لگی اور انجیل کے تقدُس اور مسیحی تعلیمات کی صداقت کو شک کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔
کلیسا اپنے عقائد یہ کھلی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا ۔ چنانچہ سائنس دانوں کو سخت سزائیں دی گئیں۔ برونو کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا حالانکہ وہ پادری تھا ۔ گلیو پر مذہبی عدالت میں مقدمہ چلا۔ اس نے توبہ کر لی مگر چپکے سے بولا کہ میں مانوں یا نہ مانوں زمین تو بہرحال گھومتی رہے گی۔ سائنس دانوں کی کتابیں نذرِ آتش ہوئیں اور ان کا پڑھنا اور رکھنا جرم قرار پایا لیکن صنعت کاروں نے سائنسی ایجادوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور سائنسی علوم کی مقبولیت برابر بڑھتی گئی۔
مارٹن لُوتھر، تھامس مونزر، زونگلی اور کالون کی مذہبی بغاوتوں نے بھی کلیسا کے وقار کو سخت صدمہ پہنچایا۔ یہ لوگ خود پادری تھے لیکن کلیسا کے جو روستم سے ان کا پیمانہ بھی چھلک اٹھا۔ پادری سادہ لوح عقیدت مندوں سے رقم لے کر جنت کے پروانے جاری کرتے تھے اور گنڈے تعویذیں بانٹ کر توہم پرستوں کو اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ مارٹن لُوتھر وغیرہ نے پوپ سے ان بد عنوانیوں کو روکنے کی درخواست کی تو الٹے ان کو مذہب سے خارج کردیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی، شمالی یورپ، ہالینڈ، بلجیم، برطانیہ ہر جگہ پوپ کی مخالفت شروع ہو گئی اور پروٹسٹینٹ فرقہ وجود میں آیا جس نے کلیسا ئے روم سے بالکل قطع تعلق کرلیا۔ نئے فرقے کی بنیادی تعلیم یہ تھی کہ خدا اور انسان کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ انجیل اپنی زبان میں پڑھے، اپنی زبان میں عبادت کرے اور اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرے۔
ان معاشرتی اور مذہبی انقلابات کا اثر طرزِ حکومت پر بھی پڑا۔ ابھی تک ریاست پر فیوڈل عناصر کا قبضہ تھا مگر معاشرے میں طاقت کا توازن بدلا تو تاجروں اور صنعت کاروں نے نظم و نسق میں شرک کا مطالبہ شروع کردیا۔ اُنھوں نے شہریوں کی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے عوام کے حقوق کا پیوند بھی لگایا۔ رومن کلیسا کو نیچا دکھانے میں پہل برطانیہ نے کی ۔ ہنری ہشتم (1506۔1547ء) نے روم سے ناتا توڑ لیا تھا۔ کلیسا کی جائیدادیں ضبط کرلی تھیں اور پادریوں کو درس گاہوں سے نکال دیا تھا لیکن فیوڈلزم کا ریاستی نظریہ الوہی استحقاقِ ملوکیت بدستور رائج تھا بلکہ ہنری ہشتم نے اس نظریے کی آڑ میں پوپ سے ٹکر لی تھی لیکن سترھویں صدی کا برطانوی معاشرہ سو سال پہلے کا معاشرہ نہ تھا۔ اب برطانوی پارلیمنٹ لندن کے تاجروں کے زیرِ اثر تھی۔ ان کو بادشاہ جیمس اوّل (1603۔1625ء) سے یہ شکایت تھی کہ وہ پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر ٹیکس لگا دیتا ہے، سرکاری قرضے لیتا ہے، لوگوں کو بتائے اور مقدمہ چلائے بغیر قید کردیتا ہے اور جب چاہتا ہے ملک میں مارشل لا لگا دیتا ہے۔ بادشاہ کا کہنا تھا کہ ” ہم خدا کی ناقابلِ تغیر مرضی و منشا کے حقیقی ترجمان ہیں لہذا ہمارا ہر عمل درست ہے اور تم کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے” لیکن پارلیمنٹ نے بادشاہ کے اُلوہی استحقاق کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔ بادشاہ اور پارلیمنٹ کی اس نزاع نے آئینی بحران کی شکل اختیار کر لی۔ سوال یہ تھا کہ اقتدارِ اعلیٰ کا مرکز پارلیمنٹ ہے یا بادشاہ، جو خدا کی نمائندگی کا دعویٰ کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کا موقت یہ تھا کہ:
شہری آزادیاں، ذمہ داریاں، مراعات اور پارلیمنٹ کا حلقہ اختیار انگلستان کے باشندوں کا قدیم پیدائشی حق اور ورثہ ہے اور یہ کہ بادشاہ کی شخصیت ، مملکت کے اصول، قلمرو کا دفاع، مذہبی امور، قانون سازی، قوانین کا نفاذ اور شکایتوں کی تلافی، یہ تمام موضوعات پارلیمنٹ میں بحث و مباحثے اور غوروفکر کے مناسب موضوعات ہیں”۔ (1621ء)
بادشاہ نے پارلیمنٹ کے ان مطالبات کو رد کردیا۔ پارلیمنٹ توڑ دی اور اس کے سات سر بر آوردہ ارکان کو قید کردیا لیکن تحریک نہ دبی بلکہ اس کے بیٹے چارلس اوّل (1625۔1649ء) کے عہد میں پارلیمنٹ اور بادشاہ کے نزاع نے بالآخر خانہ جنگی کی صورت اختیار کرلی۔ پانچ سال کی خوں ریزی کے بعد چارلس اول نے شکست کھائی۔ اس کا سر قلم ہوا اور برطانیہ ری پبلک بن گیا۔ اُلوہی استحقاق کا نظریہ بادشاہ کے خون کے ساتھ خاک میں مل گیا۔ 1688ء میں اگرچہ ملوکیت بحال ہوئی مگر فیوڈل عناصر نے برسر اقتدار سرمایہ دار طبقے سے سمجھوتہ کرلیا اور کسی نے پھر اُلوہی استحقاق کا نام نہ لیا۔ ملوکیت پارلیمنٹ کے تابع ہو کر آئینی ملوکیت ہو گئی۔
برطانیہ نے تھیو کریسی کو ختم کرنے میں سبقت کی لیکن بقیہ یورپ کو اس عمل کی تکمیل میں مزید سو سال لگے۔ اور تب انقلابِ فرانس نے تھیو کریسی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ فیوڈل ازم کے تینوں ستون۔۔۔۔ ملوکیت، کلیسائیت اور نوابی۔۔۔ زمین پر آرہے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رومن کلیسا کی خود مختار مملکت جو تھیو کریسی کا سب سے مضبوط قلعہ تھی فقط 109 ایکڑ زمین کی مالک رہ گئی۔ اب وہ روم کا ایک محلہ ہے جس کی آبادی کُل ایک ہزار ہے۔
سترھویں اور اٹھارویں صدی کو یورپ میں خرد مندی اور خرد افروزی کا عہد کہا جاتا ہے۔ اس دور میں صنعتی انقلاب اور سائنسی علوم کی ترقی کے باعث مغربی معاشرے کی کایا پلٹ گئی۔ عقل آزاد ہوئی اور سائنس دانوں ، فلسفیوں اور سیاسی مفکّروں نے قرونِ وسطیٰ کے فرسودہ عقائد و نظریات کے بخیے اُدھیڑ دیے۔ بیکن، ہابس، لاک، ملٹن، والٹیر، دیدرو، اولباخ، ایلوتیئیس، گے سندی، ڈیکارٹ، لامارتی، کانٹ، اسپائنوزا، لائبنیز، روسو، ہرڈر اور مانتسکیو جیسے روشن خیال دانش وروں کی تحریریں شوق سے پڑھی جانے لگیں اور جمہوریت، مساوات، نمائندہ طرزِ حکومت، تقسیمِ اختیارات، حُبِ بشر، سلطانی جمہور اور کمیونزم سوشلزم کا چرچا عام ہوا۔ دنیا سماجی انقلاب کے نئے دور میں داخل ہو گئی۔
تھیو کریسی کے آغاز اور عروج و زوال کے اس جائزے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تھیو کریسی کوئی ابدی اور مقدس نظریہ ریاست نہیں ہے بلکہ معاشرتی ارتقا کے ایک مخصوص عہد میں تاریخی ضرورتوں کے تحت وجود میں آئی اور جب یہ ضرورتیں باقی نہ رہیں تو تھیو کریسی کا بھی وہی انجام ہوا جو غلامی کا ہوا۔
تھیو کریسی پروہت راج اور فیوڈلزم کا نظریہ ریاست تھی۔ موجودہ دور میں جب صنعتی انقلاب کے باعث معاشرے کے حالاتِ زیست بدل گئے ہیں، سائنسی علوم نے تھیو کریسی کے تمام اذعان و مفروضات کا بھرم کھول دیا ہے اور فیوڈلزم کا چل چاؤ ہے تھیو کریسی کے احیا کی کوشش ارتقائے انسانی کو پیچھے کی طرف لے جانا ہے۔ تھیو کریسی جمہوریت اور جمہوری قدروں کی نفی کرتی ہے۔ تھیو کریسی معاشرے کو آگے لے جانے کے بجائے لوگوں کو ماضی کا سنہرا خواب دکھاتی ہے۔ تھیو کریسی سائنسی علوم اور سائنسی سوچ کی دشمن ہے۔ وہ اجتہاد کے بجائے تقلید اور تحقیق و جستجو کے بجائے منقولات اور روایت پرستی کی تعلیم دیتی ہے۔ تھیو کریسی خوف اور لالچ کی عفریتی قوتوں سے عقل و خرد کا گلا گھونٹنے کے درپے رہتی ہے۔ تھیو کریسی ظلمت پرستوں کا آخری حربہ ہے جو خدا کی حاکمیت کی آڑ میں تنگ نظر مُلاؤں کا راج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ فیوڈلزم اورر فیوڈل قدروں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو ان کے پیدائشی حقوق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔
حوالہ جات و حواشی
1 ۔ مسٹر جناح کا خطبہ مسلم لیگی ممبرانِ اسمبلی کے کنونشن میں 1964ء دہلی
2 ۔ قائداعظم محمد علی جناح۔ فروری1947ء
3۔Frederick Engels. Anti duhring. P.247
4 ۔ قدیم شہری ریاستوں پر ہم نے اپنی کتاب ” ماضی کے مزار” میں تفصیل سے بحث کی ہے۔
5۔Will Durant. Our Oriental Heritage, vol. 19, p. 147.201
6۔ کتابِ خروج۔ ب 12:24
7۔A, Buhier (ed.) Manu’s Smirti, oxford, 1886,pp,216-18
8۔Hemrich Zimmler, Philosophies of India, New york, 1953, p.97
9۔حضرت موسیٰ کی قومیت کے بارے میں مغربی مورخین میں بڑا اختلاف ہے۔ بعضوں کا (جن میں فرائڈ کا سا یہودی النسل مفکر بھی شامل ہے)ج دعویٰ ہے کہ موسیٰ عبرانی لفظ نہیں بلکہ قدیم مصری لفظ ہے جو ” اہموس” کا مخفف ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ موسیٰ دراصل وحدانیت پرست فرعون اخناطون کے درباری امیر تھے۔ اخناطون کی وفات کے بعد آمون رع کے پروہتوں نے موحدوں کا تختہ الٹا تو موسیٰ خدا پرست اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر ترکِ وطن کر گئے۔
10۔قضاۃ۔ باب۔ 16،17
11 ۔ دیکھئے تفہیم القرآن ۔ جلد اول۔ ص 175۔176
12۔ کتاب سموئیل، باب۔ 15۔7 باب 5۔8
13۔ عشر کا دستور اسلام ہزاروں برس پہلے رائج تھا۔
14۔ کتابِ سموئیل ، باب 8:10۔ 18
15۔ سورۃ البقرہ، 225،226
16۔ ایضاً، 250
17۔ تفصیل کے لیے دیکھئے کیمیائے سعادت از امام غزالی اور حجتہ اللہ البالغہ از شاہ ولی اللہ۔
باب دوم: اسلامی ریاست
” مجھ کو پاکستان کے ابتدائی دنوں کی وہ لا متناہی بحثیں اب تک یاد ہیں جو نظریہ پاکستان کے بارے میں نجی صحبتوں اور عام جلسوں میں ہوتی رہتی تھیں لیکن ان بحثوں کے دوران میں نے ایک بار بھی کسی کے منھ سے یہ نہیں سنا کہ افلاس (اور جہالت) کا مکمل قلع قمع بھی نئی ریاست کے بنیادی نظریات میں شامل ہے۔” 1
سماجی ادارے ہوں یا عقائد و افکار، ان کا مطالعہ تاریخی پس منظر میں کرنا چاہیے تاکہ اُن عوامل و محرکات کا سراغ مل سکے جو ان حقیقتوں کے ظہور کا سبب بنے۔ اس اندازِ نظر کو فلسفہ تاریخ کی اصطلاح میں ” تاریخی ذہنیت” Historical Mindedness کہتے ہیں۔ یہ وہی اندازِ نظر ہے جس کے تحت علمائے سلف نے آیاتِ قرآنی کی شانِ نزول دریافت کی تھی اور یہ پتہ چلایا تھا کہ یہ آیتیں کب، کس موقعے پر کس مقصد سے نازل ہوئی تھیں۔ مگر تاریخ چونکہ ایک متحرک اور تغیر پذیر حقیقت ہے اور علامہ اقبال کے بقول چونکہ
سکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میں
لہذا ہم پر لازم ہے کہ حقیقتوں کا مطالعہ ان کے عالمِ حرکت و تغیر میں کریں نہ کہ عالمِ سکون ثبات میں۔ یعنی طرز معاشرت میں، سماجی اداروں میں، اور عقائد و افکار میں وقتاً فوقتاً جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں ان کو نظر میں رکھیں۔
علامہ اقبال نے کائنات کے حرکی اور ارتقائی تصور پر بہت زور دیا ہے۔ ان کے نزدیک تمام موجودات ِع عالم جن میں انسان بھی شامل ہے قانونِ حرکت و تغیر کے تابع ہیں (” ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں”) وہ اپنی مشہور نظم” ساقی نامہ” میں لکھتے ہیں کہ
فریبِ نظر ہے سکون و ثبات
تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات
ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود!
کہ ہر لحظہ تازہ ہے شانِ وجود
دمادم رواں ہے یم زندگی
ہر اک شے سے پیدا رمِ زندگی
علامہ اقبال نے انھیں خیالات کا اظہار ” ارتقا، زمانہ” اور دوسری متعدد نظموں میں بھی کیا ہے۔ دراصل تغیر اور ارتقا کا تصور علامہ اقبال کی فکر کا نہایت اہم جز ہے۔ چنانچہ انھوں نے ” خطبات مدراس” میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کی رُو سے۔
” کائنات ترقی پذیر حقیقت ہے کہ نہ مکمل تخلیق جس کو اُس کا خالق مدت گزری ایک بار تخلیق کر کے الگ ہو گیا اور اب وہ (کائنات) خلا میں مادے کا بے جان ڈھیر ہے جس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔” 2
اشعری مفکروں کا ذکر کرتے ہوئے (جو ایٹمی فلسفے کا قائل تھے) علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ” خدا کا تخلیقی عمل مسلسل جاری ہے لہذا ایٹموں کا شمار ممکن نہیں ۔ ہر لحظہ نئے ایٹم وجود میں آتے ہیں اور کائنات مسلسل بڑھتی اور پھیلتی رہتی ہے۔”3 اور کوئی شے ثابت اور قائم نہیں ہے4 علامہ اقبال انسان کے جسمانی ارتقا کے بھی قائل ہیں۔ وہ اتقائے بشر کو قرآن کی رُوح کے عین مطابق سمجھتے ہیں اور ان مسکویہ اور مولانا روم کی سند پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ” ارتقا کے تصور نے بتدریج تشکیل پائی”5 اس ضمن میں وہ الجاحظ، البیرونی اور ابن مسکویہ کی دریافتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں “تخلیقِ مسلسل کا تصور خالص اسلامی ہے۔” 6
یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید
کہ آرہی ہے دما دم صدائے کن فیکون
علامہ اقبال کے ایک خطبے کا عنوان ہی “اسلامی ڈھانچے میں حرکت کا اصول ” ہے ۔ ان کے خیال میں ” تہذیبی تحریک کے اعتبار سے اسلام کائنات کے پرانے جامد تصور کور د کرتا ہے۔ اسلام کا تصوف کائنات حرکی Dynamic ہے”7 چنانچہ “اسلام کی نظر میں زندگی کی روحانی اساس اپنے کو تغیر اور تبدیلی میں منکشف کرتی ہے”8 مگر ” اسلام کی فطرت میں حرکت کا اصول کیا ہے” 9 یعنی اسلام قانونِ حرکت پر کس طرح عمل کرتا ہے۔ علامہ اقبال جواب دیتے ہیں کہ اجتہاد کے ذریعے۔ اُن کو اسلامی معاشرے سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ اس نے اجتہاد کی ضرورت اور افادیت کو فراموش کردیا اور لکیر کا فقیر بن گیا۔ وہ ماضی پرستی اور ماضی کے احیا کے سخت خلاف ہیں۔ ان کی نظر میں ” پرانی تاریخ کا غلط احترام اور ضابطہ سازی اسلام کے داخلی تہپج Impulse کے منافی ہے”۔11 اسی بنا پر وہ ترکوں کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے اجتہاد سے کام لیا اور شخصی خلافت کے ادارے کو ختم کردیا۔
یہ اس شخص کا انداز ِ فکر ہے جس کو ” مفکر پاکستان” اور ” حکیم الامت” کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اربابِ حل و عقد اور علمائے کرام کا اندازِ فکر علامہ اقبال کے اندازِ فکر کی عین ضد ہے۔ یہ حضرات حقائق ہستی کو جامد و ساکت خیال کرتے ہیں اور حرکت و تغیر کے نام سے کانپتے ہیں۔ ان کی نظر میں اسلام پتھر کا کوئی بے جان بت ہے جس پر انقلابِ زمانہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ گزشتہ چودہ سو برس میں کرہ ارض کی شکل ہی کچھ اور ہوگئی ہے۔ خود مسلمانوں کی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہمارے معاشرتی رشتے بدلے ہیں، پیداوار کے طریقے بدلے ہیں، سماجی قدریں بدلی ہیں، رسم و رواج بدلے ہیں، رہن سہن بدلا ہے، خوراک اور پوشاک بدلی ہے، ریاست کا نظام و آئین بدلا ہے، قانون اور ضابطے بدلے ہیں، اخلاق و عادات بدلی ہیں، سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز بدلا ہے، علوم و فنون بدلے ہیں۔ اب ہم تیل کے چراغ کی جگہ بجلی کے بلب جلاتے ہیں، اورنٹ کے بجائے موٹر اور ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں۔ چٹائی پر نہیں بلکی چارپائی پر سوتے ہیں اور صوفوں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ فاؤنٹین پین سے لکھتے ہیں۔ ٹیلی فون، گھڑی ، ریڈیو، ٹی وی، ایرکنڈیشنر اور ریفریجریٹر غرضیکہ بے شمار چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کا عہدِمصطفویؐ اور خلافتِ راشدہ میں نام و نشان تک نہ تھا لیکن مولوی حضرات ان معاشرتی تبدیلیوں کو در خورِ اعتنا نہیں سمجھتے بلکہ ان کا مطالبہ ہے کہ معاشرے کی تنظیم اُنہیں خطوط پر ہونی چاہیے جو اسلاف نے اپنی ضرورتوں کے لیے وضع کیے تھے۔
مگر حقیقت کو زمان ومکان کے تناظر سے جدا کر کے دیکھنے سے یہ پتہ چلتا کہ یہ حقیقت ایک خاص وقت میں اور خاص مقام پر کیوں ظاہر ہوئی اور حالاتِ زیست میں تبدیلی کے بعد کیوں معدوم ہو گئی۔ مثلاً غلامی کی رسم پرانے زمانے میں بہت عام تھی چنانچہ ارسطو نے غلامی کی بڑی شدت سے حمایت کی ہے اور عہدِمصطفویؐ میں بھی غلامی کا رواج تھا۔ اور مسلمان بھی غلام رکھتے تھے لیکن اب بین الاقوامی قوانین کے تحت غلامی اور بردہ فروشی دونوں جرم ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ غلامی چونکہ عہدِمصطفویؐ میں جائز تھی لہذا دورِ حاضر میں بھی غلام کنیزیں رکھنا جائز ہے (مولانا مودودی کا موقف یہی ہے) تو اس کا یہ طرزِ استدلال غیر تاریخی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ماضی کو حال کی عینک سے دیکھے اور موجودہ دور کی سماجی قدروں کے مطابق ارسطو یا آنحضرت صلعم پر یہ اعتراض کرے کہ ان بزرگوں نے غلامی کو ممنوع کیوں نہیں قرار دیا تو اس کا یہ اعتراض بھی غیر تاریخی ہوگا۔ کیونکہ دونوں صورتوں میں غلامی کو اس کے تاریخی پس منظر سے الگ کر دیا گیا ہے ۔ غلامی کی رسم کا صحیح شعور ان معاشرتی حالات کے مطالعے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے جن کے باعث یہ رسم شروع ہوئی ۔ تب ہی ہم جان سکیں گے کہ غلامی پرانے زمانے میں کیوں ناگزیر تھی اور اب کیوں جرم ہے۔
دوسری مثال غزواتِ نبوی کی ہے جن کو ” ذہنیتِ حاضرہ” رکھنے والے مورخین لوٹ مار سے تعبیر کرتے ہیں دورِ حاضر کے سماجی اور اخلاقی معیار سے غزوات واقعی لوٹ مار نظر آئیں گے مگر غزوات پر تاریخی پسِ منظر میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ عربوں کی پرانی ریت تھی اور مخالف قبیلے کے مال و اسباب پر قبضہ کر لینے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لہذا موجودہ اخلاقی اصولوں کے حوالے سے غزوات کی مذمت کرنا اتنا ہی غلط اور غیر تاریخی عمل ہو گا جتنا دورِ حاضر میں غزوات کی تلقین کرنا۔
یہی وہ غیر تاریخی طرز فکر ہے جس کے تحت بعض حلقے پاکستان میں عہدِمصطفویؐ اور خلافتِ راشدہ کے انداز کی اسلامی ریاست قائم کرنے پر اصرار کررہے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام کی حرکی روح کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ انھوں نے اجتہاد کے بجائے تقلید اور معقولات کے بجائے منقولات ہی کو اسلام سمجھ لیا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ریاست کی نوعیت حالاتِ زیست سے متعین ہوتی ہے اور حالاتِ زیست بدل جائیں تو ریاست کا نظام بھی بدل جاتا ہے۔ مدنی ریاست کے احیا کا مطالبہ کرتے وقت ان بزرگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ جن معروضی حالات میں مدنی ریاست کی تشکیل ہوئی تھی وہ دوبارہ واپس نہیں آسکتے۔ وہ یہ بھی نہیں معلوم کرنا چاہتے کہ وہ کون سے داخلی تضادات تھے جن کے باعث خلافتِ راشدہ 32 سال کی مختصر مدت میں ایک مطلق العنان ملوکیت میں بدل گئی۔ ابھی تک تو خلافت بنی امیّہ اور بنی عباس کی ” اسلامی” حیثیت بھی متعین نہیں ہو سکی ہے۔ جب فتوحات کا ذکر چھڑتا ہے اور اس میں سندھ کی فتح بھی شامل ہے یا عباسی دور میں علوم و فنون کے فروغ کی داستان رقم ہوتی ہے تو ان سلطنتوں کو مشرف بہ اسلام کر لیا جاتا ہے مگر ان کے جبرو استبداد اور غیر شرعی اعمال و افعال پر اعتراض کرو تو جواب ملتا ہے کہ یہ حکومتیں ہمارے لیے قابلِ تقلید نہیں۔
آئیے دیکھیں کہ مدنی ریاست کن حالات میں وجود میں آئی۔
ہر شخص جانتا ہے کہ عہدِ رسالت سے قبل حجاز کے کسی خطے میں کبھی کوئی ریاست قائم نہیں ہوئی۔ حجاز کے چہار جانب چھوٹی بڑی کئی ریاستیں موجود تھیں۔ مثلاً ایران کی ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت اور ان کے تابع حیرا اور غسان کی عرب بادشاہتیں اور یمن کی متعدد ریاستیں لہذا اہلِ حجاز ریاستوں کے وجود سے ناواقف نہ تھے۔ تجارتی مال کی خریدو فروخت کے سلسلے میں وہ ان علاقوں کاسفر بھی کرتے رہتے تھے ۔ مگر انھوں نے حجاز میں ریاست قائم کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی۔ مکے میں ایک شخص عثمان بن حویرث نے جو قبیلہ بنی اسد کا دولت مند فرد تھا بازنطینیوں کے اشارے پر بادشاہ بننے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن اسی قبیلے کے ایک شخص اسود بن المطلب نے سازش کا راز فاش کردیا۔ یہ واقعہ بعثت سے بیس سال پہلے آنحضرتؐ کے قیام مکہ کے دوران پیش آیا تھا۔12
حجاز میں گنتی کے کُل تین قابلِ ذکر شہر تھے۔ مکہ، طائف اور یثرب (مدینہ) ان میں سب سے اہم مکہ تھا جس کی آبادی دس ہزار کے قریب تھی۔ حرم کعبہ کی وجہ سے مکے کو پورے جزیرہ نما عرب میں امتیازی حیثیت حاصل تھی ۔ حج کے موقعے پر وہاں ہزاروں عرب دُور دراز مقامات سے آتے البتہ کوئی شخص شہر میں ہتھیار سمیت داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حج کے زمانے میں مکے میں بہت بڑا بازار لگتا تھا اور شاعروں کے درمیان مقابلے بھی ہوتے تھے۔ اپنی جائے وقوع کی وجہ سے مکہ اہم تجارتی مرکز بھی تھا۔ یمن و شام اور عراق و حبشہ جانے والے تجارتی قافلے مکے ہی سے گزرتے تھے۔ اہلِ مکہ ان قافلوں سے قیام اور راہ داری کا محصول وصول کرتے تھے۔ اہلِ مکہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ کیونکہ زمین اتنی پتھریلی تھی کہ کھجور کے درخت بھی اگ نہ سکتے تھے نہ کوئی کاشت ہو سکتی تھی۔ یہ لوگ روپے کا لین دین بھی کرتے تھے ( عرب میں بازنطینی سکے رائج تھے) کہتے ہیں کہ مکے کے قریب چاندی کی کانیں تھیں اور قریش کا مالِ تجارت چاندہ ہوتا تھا 13 مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ چاندیج کی کانیں اہلِ مکہ کی اجتماعی ملکیت تھیں یا ان پر کسی مخصوص گھرانے کا قبضہ تھا۔
مکے میں اکثریت مشرکینِ قریش کی تھی لیکن عیسائی، مجوسی اور دین حنیف(وحدانیت پرست) کے پیرو بھی مختصر تعداد میں آباد تھے۔ (حضرت خدیجہٖٖرضی اللہ عنہا کا گھرانہ حنیفی تھا) البتہ یہودی کوئی نہ تھا۔ قریش کا مخصوص خدا اگرچہ اللہ تھا 14 لیکن اہلِ مکہ عزیٰ (سارۂ صبح۔ زہرہ ) اور ہبل (روح یا ہوا) کی پرستش بھی کرتے تھے۔ کعبے میں ہبل کا بت سب سے ممتاز جگہ پر نصب تھا۔
مکے میں نظم و نسق کے لیے کوئی مرکزی ادارہ نہ تھا بلکہ ہر قبیلہ اپنی جگہ ایک خود مختار وحدت تھا۔ البتہ شہر کے اجتماعی مسائل طے کرنے کے لیے ایک ڈھیلی ڈھالی تنظیم ضرور تھی جس کو ” ملاء” کہتے تھے۔ یہ مجلسِ شوریٰ سردارانِ قبیلہ اور عمائینِ شہر پر مشتمل ہوتی تھی اور اس میں فیصلے اتفاقِ رائے سے ہوتے تھے۔ کسی قبیلے کو دوسرے پر نہ فوقیت تھی نہ کوئی کسی کا مطیع تھا۔ کعبے کے انتظام کی خاطر مندرجہ ذیل مناصب مختلف قبیلوں میں منقسم تھے
منصب تفصیل خاندان
حجابتہ کعبے کی کلید برداری اور تولیت بنی طلحہ
رفادۃ حجاج کی خبری گیری بنی نوفل
سقایہ حجاج کو پانی پلانا بنی ہاشم
مشورہ ملاء کا اجلاس طلب کرنا بنی اسد
دیات خوں بہا کا فیصلہ بنی یتم
عقاب سالارِ فوج(جنگ کے موقعے پر) بنی امیہ
قبہ خیمہ و خرگاہ کا انتظام بنی مخزوم
سفارت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بنی عدی
اموال کعبے کے اثاثے کی نگرانی بنی سہم
مگر قبائلی انفرادیت کے باوصف قبیلوں کے اندر روایتی مساوات ختم ہوتی جا رہی تھی اور امیر اور غریب گھرانوں کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا تھا۔ ابو سفیان بن حرب بنی امیہ، ولید بن مغیرہ (بنی مخزوم) عاص بن وائل (بنی سہم ) ابو جہل (بنی مخزوم) اور عتبہ بن ربعیہ (ابوسفیان کا سسر) کا شمار امرائے شہر میں ہوتا تھا۔
مکے کے ابتدائی باشندے بنی جرہم تھے۔ ان پر خزاعہ نے غلبہ پایا اور کعبے کے متولی بن گئے۔ 440ء میں قبیلہ قریش کے ایک شخص قصّئی نے خزاعہ سے اختیارات چھین لیے۔ ابن اصحاق کی روایت کے مطابق قصّئی نے کعبے کے متولی حلیل خزاعی کی بیٹی سے شادی کی تھی اور حلیل کی وفات پر کعبے کا متولی بنا تھا۔ “کعبے کی کنجیاں اس کی تحویل میں رہتی تھیں اور ملاء کی صدارت کرنا، حاجیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور جنگ کے موقعے پر لشکر کا علم بردار مقرر کرنا اس کا حق تھا” 15 مکے میں قریش کے علاوہ دوسرے قبیلے بھی بسے ہوئے تھے لیکن اکثریت قریش کی تھی اور ان کا اثر رسوخ بھی دوسروں سے زیادہ تھا۔ قریش کے لفظی معنی” تیغا مچھلی” کے ہیں۔ ” قریش” اس قوم کا غالباً ٹوٹم تھا جو یمن سے حجاز میں آکر آباد ہو گئی تھی۔
قصّئی کے مرنے پر اس کے بیٹوں کی اولاد میں جھگڑا ہونے لگا۔ عبد مناف کو بنی اسد، بنی زُہرہ، بنی یتم اور بنی حارث کی حمایت حاصل تھی جب کہ بنی عبدالدار کو بنی مخزوم، بنی سہم، بنی جماح اور بنی عدی کی۔ بالآخر بنی عبدِ مناف کو حاجیوں کو پانی پلانے (سقادہ) اور محصول وصول کرنے (رفادہ) کا کام سپرد ہوا اور بنی عبدالدار کو “ملاء” طلب کرنے، کعبے کی کلید برداری اور علم بردار کے تعین کا۔ آنحضرت صلعم کی ولادت تک اسی تقسیمِ کار پر عمل ہوتا رہا لیکن عبد مناف کی وفات پراس کے دو بیٹوں ہاشم اور عبدالشمس کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی اور ہاشم کی وفات پر عبدالشمس کے بیٹے اُمیّہ کو بالادستی حاصل ہو گئی۔ بنی ہاشم اور بنی اُمیّہ کی تاریخی عداوت کی بنیاد یہی کشمکش تھی۔
مدینے کے طبعی اور معاشرتی حالات مکے سے مختلف تھے۔ مدینہ نہایت شاداب نخلستان کے درمیان واقع تھا۔ ” دراصل مدینہ کوئی باقاعدہ شہر نہ تھا بلکہ چھوٹے چھوٹے قریوں (پُروں) کھیتوں اور کوٹوں کا جمگھٹا تھا جو تقریباً بیس مربع میل میں پھیلا ہوا تھا اور پہاڑیوں، چٹانوں اور ناقابلِ کاشت زمینوں سے گھرا تھا”16 نخلستانوں کا یہ سلسلہ فدک، خیبر اور تبوک تک جاتا تھا۔ مدینے کے لوگ زراعت پیشہ تھا مگر ریاست کا وہاں بھی نام و نشان نہ تھا۔
مدینے کی آبادی بہت ملی جلی تھی۔ تین قبیلے یہودیوں کے تھے۔ قینقاع جو سنار اور ساہو کار تھے، اور بنی نضیر اور بنی قریظہ جو مدینے کی زرخیز زمینوں کے مالک تھے۔ مدینے کا سب سے دولت مند گروہ یہودیوں کا تھا۔ اَوس اور خزرج کو مدینے میں انھیں نے بسایا تھا۔ تھوڑی سی آبادی ان عربوں کی بھی تھی جو یہودیوں سے پہلے یہاں آباد تھے۔ اکثریت بنی اَوس اور بنی خزرج کی تھی مگر رفتہ رفتہ وہ بہت سے ضمنی قبیلوں میں بٹ گئے تھے اور ان میں بڑی پھوٹ تھی۔
” ہر ممتاز قبیلہ اپنی جگہ ایک چھوٹی سی ریاست، ایک آزاد وحدت تھا۔ اس علاقے کے اندر جہاں قبیلہ بسا ہوا تھا بڑی حد تک امن رہتا کیوں کہ اپنے ہم قبیلہ کا خون بہانا ناقابلِ معافی جرم تھا۔ البتہ اپنے قبیلے سے یا حلیف قبیلے کے حدود سے باہر تحفظ مفقود تھا۔ جنگِ بعاث (اَوس اور حزرج کے درمیان 617ء) کے بعد ” ٹھنڈی جنگ” کے زمانے میں تو جان ہر وقت خطرے میں رہتی تھی۔ا یک قبیلے کی سرحد کو پار کر کے دوسرے قبیلے کی سرحد میں قدم رکھنا خطرے سے خالی نہ تھا”۔ 17
مدنی قبیلے، یہودی ہوں یا غیر یہودی کسی کی بالا دستی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جان و مال کے تحفظ کی واحد ضمانت بدلے کا خوف تھا یعنی یہ اندیشہ کہ اگر کسی کو مارا یا نقصان پہنچایا تو پورے خاندان بلکہ قبیلے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
جنگِ بعاث (617ء) سے اوس اور خزرج دونوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ جنگ چوں کہ فتح و شکست کے بغیر عارضی صلح پر ختم ہوئی تھی لہذا مدینے کا معاشرہ باہمی نفاق اور غیر یقینی صورتِ حال کی وجہ سے سخت بحران میں مبتلا تھا۔ وہاں فریقین کو اپنے نخلستانوں کو اچانک حملے سے بچانے کے لیے ہر دم چوکس رہنا پڑتا تھا۔ اَوس اور خزرج دونوں لڑتے لڑتے تھک گئے تھے اور کسی ایسے پر امن اور باعزت حل کے خواہاں تھے جس سے کسی کی سبکی نہ ہو۔
یہ تھے وہ معروضی حالات جن میں آنحضرتؐ نے اہلِ مکہ کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت کی اساس پر اُمتِ واحدہ کا انقلابی فلسفہ پیش کیا جو رنگ و نسل ، قوم و وطن اور قبیلے خاندان کی تفریقوں سے بلند عالمگیر انسانی برادری کا نظریہ تھا مگر اُمت کا یہ تصور سردارانِ قریش کے لیے قابلِ قبول نہ تھا۔ تجارت اور حج ان کی آمدنی کے دو زرائع تھے جن سے نزاع کےبجائے یک جہتی پیدا ہوتی تھی۔ اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کا تصفیہ وہ ملاء کی مجلسِ شوریٰ میں کر لیتے تھے۔ اہلِ مدینہ کی مانند خونی رشتوں کی عصبیت ان کے لیے عذابِ جان نہیں بنی تھی اور نہ روز روز کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ان کا معاشرہ بے یقینی اور عدم تحفظ کا شکار تھا بلکہ ایک مستحکم معاشرہ تھا جس کو اپنی طاقت پر پورا اعتماد تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرتؐ کی بارہ سال کی مسلسل سعی و تبلیغ کے با وصف مکے میں بہ مشکل ڈیڑھ دو سو افراد نے اسلام قبول کیا۔ حالاں کہ اہلِ مکہ آپؐ کی ایمان داری، صدق گوئی اور غیر جانب داری کا بار بار امتحان کر چکے تھے۔
لیکن آنحضرتؐ کی روحانی قیادت اور اُمتِ واحدہ کا وہی تصور جس کے باعث اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے اہلِ مدینہ کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ ” جو چیز مکے میں آنحضرتؐ کی مخالفت کا سبب تھی یعنی نبوت اور اس کے سیاسی مضمرات وہی چیز اہلِ مدینہ کے لیے امن و آشتی کی امید تھی” 18 اَوس اور خزرج کے نمائندوں کا العقبہ میں 622ء میں یک جا ہو کر اسلام قبول کرنا، رسولؐ کی قیادت کو تسلیم کرنا اور آنحضرتؐ کو مدینہ منتقل ہونے کی دعوت دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں قبیلے خونی رشتوں کے تقدس سے تنگ آچکے تھے۔
آنحضرتؐ کا دستور تھا کہ مکے میں حج یا دوسرے تیوہاروں کے موقعے پر جب قافلے باہر سے آتے تو آپؐ ان سے ملاقات کرتے اور اسلام کا پیغام ان کو سناتے چنانچہ جنگِ بعاث سے پہلے بنی اوس کی ایک جمعیت جب قریش سے خزرج کے خلاف مدد کی درخواست کرنے مکے آئی تو آپؐ ان سے ملے اور ان کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز پیش کرسکتا ہوں جس کے لیے تم یہاں آئے ہو اور وہ ہے اسلام جو تم امن و آشتی کی خوش خبری سناتا ہے اور اللہ کی عبودیت کی طرف بلاتا ہے۔ آپؐ نے ان کو چند آیاتِ قرآنی بھی پڑھ کر سنائیں ” تب ایاث جو جوان تھا کہنے لگا کہ خدا کی قسم لوگو! یہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو ” مگر اس کو ڈانٹ کر چپ کردیا گیا۔19
جنگِ بعاث کے بعد 10 نبوی/620ء میں آنحضرتؐ کی ملاقات العقبہ کے معام پر بنی خزرج کے چھ افراد سے ہوئی جو مدینے میں وحدانیت پر ست یہودیوں کے حلیف تھے اور جب انھوں نے رسولؐ کی گفتگو سنی تو وہ مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کسی قوم میں اتنی پھوٹ نہیں اور نہ اتنی عداوت اور دشمنی ہے جتنی ہم آپس میں ہے۔ شاید خدا آپ ہی کے وسیلے سے ہم کو متحد کردے۔ پس آؤ اور ان کے (اہلِ مدینہ) پاس چلیں اور آپ کے مذہب کی دعوت ان کو دیں۔ اگر خدا نے ان کو متحد کردیا تو آپ سے زیادہ کوئی طاقت ور نہ ہوگا۔20 ان کی تعداد چھ تھی۔
دوسرے سال مدینے سے بارہ افراد مکے آئے۔ ان میں نو کا تعلق بنی خزرج سے تھا اور تین کا بنی اوس سے۔ انھوں نے اسلام قبول کرلیا اور آنحضرتؐ نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کردیا تاکہ وہ نو مسلموں کو قرآن پڑھ کر سنائیں اور اسلام کی تعلیم دیں۔ وہ نماز میں امامت بھی کرتے تھے کیوں کہ اوس اور خزرج یہ برداشت نہیں کرسکتے تھے کہ ان کا کوئی حریف امامت کرے21 مصعب کو مدینے بھیجنے کا مقصد وہاں کے صحیح حالات معلوم کرنا بھی تھا۔ ان کوششوں سے بنی اوس منات کے علاوہ تمام دوسرے خاندانوں کے متعدد افراد مسلمان ہو گئے لیکن مکے کے برعکس مدینے میں کسی نے ان مسلمانوں کو اذیت نہیں پہنچائی۔
آنحضرتؐ کی حجاجِ مدینہ سے تیسری ملاقات جون622ء میں ہوئی اس ملاقات میں مختلف قبیلوں کے 73 مرد اور 2 عورتیں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ انھوں نے آنحضرتؐ کے ہاتھ پر بیعت کی جو ” بیعت الحرب” کے نام سے مشہور ہے اور عہد کیا کہ ہر اچھے برے وقت میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے لیے لڑیں گے۔22 انھوں نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی دعوت بھی دی۔ چنانچہ مہاجرین چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مکے سے مدینہ روانہ ہونے لگے اور بالآخر 16 جولائی 622ء (12 نبوی) کو آنحضرتؐ نے بھی ہجرت فرمائی اور ستمبر میں واردِ مدینہ ہو کر ابو ایوب انصاری کے گھر اترے جو آنحضرتؐ کے دادا عبدالمطلب کے رشتہ دار تھے۔
یہ امر غور طلب ہے کہ اہلِ مدینہ کی بہت بڑی تعداد غالباًاکثریت نے ازخود پیش قدمی کر کے ہنسی خوشی اسلام قبول کیا جب کہ اہلِ مکہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔
مدینے میں آنحضرتؐ کی پذیرائی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اہلِ مدینہ آپ کو اپنا قریبی عزیز خیال کرتے تھے مگر ایسا عزیز جو ان کی زمینوں اور نخلستانوں میں حصہ کا نہ خواہش مند تھا نہ مستحق 23 البتہ جس کے بارے میں اوس اور خزرج دونوں کو کامل یقین تھا کہ وہ کسی کی پاسداری نہیں کرے گا بلکہ غیر جانبدار رہے گا اور جو فیصلہ بھی کرے گا حق و انصاف کے مطابق ہوگا۔ یاد رہے کہ مدنی معاشرے پر مادری نظام کا اثر ہنوز باقی تھا۔ وہاں مادری رشتوں کو بڑی قدر اور محبت کی نگاہ سےدیکھا جاتا تھا اور عورتوں کو مکی عورتوں سے زیادہ آزادی حاصل تھی۔
مدینے میں آنحضرتؐ کے پیشِ نظر تین چار اہم مسائل تھ، (1) ۔ مہاجروں کی آباد کار، (2) امتِ واحد کے تصور کو زیادہ سے زیادہ سے موثر اور مقبول عام بنانا تا کہ مدنی قبیلوں کی خانہ جنگیاں ختم ہوں، امن و صلح کی قوتیں فروغ پائیں اور اسلامی اتحاد و اخوت کی جڑیں مضبوط ہوں، (3)۔ قریشِ مکہ کی تجارتی بالا دستی کا خاتمہ جو اسلام کی ترویج و اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے، (4)۔ مدینے کے قرب و جوار کے بدوی قبیلوں سے امن و صلح کے معاہدے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آنحضرتؐ نے ان مسائل کو بڑی خوبی اور خوش اسلوبی سے حل کیا۔
عہدِ مصطفویؐ میں اسلامی سیاست دو مدارج سے گزری۔ اوّل میثاقِ مدینہ سے فتحِ خیبر تک دوئم فتحِ خیبر سے فتحِ مکہ تک۔ میثاقِ مدینہ بری اہم تاریخی دستاویز ہے۔ ابن اصحاق نے ” سیرۃ رسول اللہ” میں میثاق کا پورا متن نقل کیا ہے مگر وہ یہ نہیں بتاتا کہ دستاویز اس کو کہاں سے ملی اور نہ یہ کہ دستاویز پر کب اور کہاں دستخط ہوئے۔ مغربی مورخین کی رائے ہے کہ میثاق کئی دستاویزوں کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں لکھی گئی تھیں۔ پروفیسر مانٹگو مری واٹ کا خیال ہے کہ دستاویز کی ابتدائی دفعات مکے میں بعیت الحرب کے موقعے پر تحریر کی گئیں کیوں کہ ان دفعات کا تعلق مدینے کے عرب قبیلوں کے مابین امن قائم رکھنے سے ہے۔ یہودیوں سے متعلق دفعات اسی زمانے یا اوائلِ ہجرت کی ہیں۔ ابنِ اصحاق نے میثاق کو ہجرت کے واقعات کے فوراً بعد نقل کیا ہے۔ اس سے بھی گمان ہوتا ہے کہ میثاق کا بڑا حصہ اوائلِ ہجرت میں لکھا گیا البتہ بعد میں اس دستاویز میں وقتاً فوقتاً اضافے اور ترمیمیں ہوتی رہیں۔
یہ معاہدہ چوں کہ مسلمانوں کے درمیان ہوا لہذا اس کی پہلی شرط خدا کی وحدانیت اور رسول صلعم کی نبوت کا اقرار تھی۔ ” یہ محمد رسول اللہؐ کی تحریر ہے ماننے والوں اور قریش ااور یثرب کے مسلمانوں کے درمیان اور جو ان کے پیرو اور ان کے حلیف ہیں اور ان سے مل کر جہاد کرتے ہیں۔ وہ ایک واحد اُمت ہیں دوسروں سے جدا۔”
اس میثاق کی رُو سے مدینے کے یہودی بھی امت میں شامل تھے حالاں کہ وہ اس معاہدے میں شریک نہ تھے۔ “بنو عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ اُمت ہیں۔ یہودیوں کا دین ان کے لیے اور مسلمانوں کا دین ان کے لیے ” یہودی چونکہ وحدانیت پرست تھے لہذا آنحضرتؐ کو یہودیوں کو، جو مدنی معاشرہ کا اہم جز تھے امت کا رکن قرار دینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔
معاہدے کی نہایت اہم دفعہ وہ ہے جس میں مدینے کو دارالامن کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ ” یثرب کی وادی اس دستاویز کے لوگوں کے لیے مقدس ہے۔ جو شخص گھر سے باہر نکلتا ہے اور جو شخص سکون سے بیٹھتا ہے مدینے میں محفوظ ہے سوائے اس شخص کے جو خطا کار ہو یا غداری کرے۔ یہ دستاویز خطا کار یا غدار کو پناہ نہیں دیتی؟” دراصل اس معاہدے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اہلِ مدینہ اپنے قبائلی جھگڑوں کو ختم کر کے دین، امتِ واحدہ کے رشتے میں منسلک ہو کر شہر میں پرا من زندگی گزاریں اور مت کے دشمنوں (قریش) کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ” قریش اور ان کے حلیفوں کو پناہ دی جائے اور یثرب پر اچانک حملہ ہو تو سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ”
باہمی اختلاف کے بارے میں طے پایا کہ ” اگر تم میں کسی چیز کی بابت اختلاف ہو تو خدا اور محمدؐ سے رجوع کرو۔” مزید وضاحت یوں کی گئی کہ ” جب کبھی اس دستاویز کے لوگوں کے مابین کوئی فساد اٹھ کھڑا ہو یا ایسا جھگڑا پیدا ہو جس سےتباہی کا اندیشہ ہو تو اس کو اللہ اور محمد رسول اللہ سے رجوع کیا جائے۔”
امن و عافیت کی بنیادوں کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے یہ شرط رکھی گئی کہ ” امت کا کوئی فرد محمد رسول اللہ کی اجازت کے بغیر جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔”
ہر چند کہ اس دستاویز کی رُو سے اہلِ مدینہ آنحضرتؐ کی اطاعت کے پابند نہیں ہوئے اور نہ سرادارنِ قبیلہ کے حقوق و اختیارات پر کوئی اثر پڑا لیکن یہ معاہدہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ معاہدہ کرنے والوں نے آنحضرتؐ کی روحانی پیشوائی کو قبول کر لیا تھا اور ان کے حق میں اپنے دو اہم حقوق سے بھی دست بردار ہو گئے تھے۔ اب وہ رسولؐ کی اجازت کے بغیر کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے اور وہ اپنے، آپس کے جھگڑوں کے تصفیے کے لیے آنحضرتؐ سے رجوع کریں گے۔ ان شرطوں کی محرک اوس اور خزرج کی دیرینہ عداوت تھی۔ جب وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کی تاب نہی لا سکتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے حکم یا فیصلے کو کیسے تسلیم کرتے۔میثاقِ مدینہ آنحضرتؐ کی سیاسی قیادت کی جانب پہلا قدم تھا۔
میثاقِ مدینہ کے بعد جنگِ بدر (2 ہجری) ایک فیصلہ کن موڑ ہے جہاں پہنچ کر مدنی ریاست کی تخم ریزی کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے۔ مالِ غنیمت کل کا کل جہاجرین میں تقسیم کردیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اب انصار کی اعانت کی ضرورت نہیں رہتی۔ چند ہی ہفتوں کے اندر بنو قینو قاع کو مدینے سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ مدینے کے سب سے بڑے بازار پر قابض تھے۔ ان کی شہر بدری کے بعد تجارت پیشہ مہاجروں کو مزید سہولتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور انصار بھی جوبن قینو قاع کے مقروض تھے قرضوں سے بری ہو جاتے ہیں۔ ایک سال بعد بنو نضیر کے اخراج اور پھر بنو قریظہ کے قتلِ عام کے بعد یہودیوں کے کھیت اور نخلستان آنحضرتؐ کی تحویل میں آجاتے ہیں (بطورفے) آنحضرتؐ ان زمینوں کو مہاجرین اور چند حاجت مند انصار میں تقسیم کردیتے ہیں۔ اب مدینہ خالص مسلمانوں کا شہر ہے۔ اب مالِ غنیمت کے علاوہ دشمنوں کی زمینیں بھی آنحضرتؐ کی مرضی سے تقسیم ہوتی ہیں۔ اب آپؐ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے اہلِ مدینہ کے مذہبی پیشوا ہی نہیں بلکہ شہر کے حاکمِ اعلیٰ بھی ہیں۔ زمین پر ریاست کا بیج پڑ چکا ہے اور انکھولے پھوٹنے لگے ہیں۔ اسی سال قرآن کی رُو سے وراثت کا قانون نافذ ہوتا ہے۔ مدینے کے قرب و جوار کے صحرا نشینوں سے امن و امداد باہمی کے معاہدے کیے جاتے ہیں اور آنحضرتؐ کے سفیر ایران، مصر، قسطنطنیہ، یمن اور غسان کو اسلام قبول کرنے کا پیغام لے کر روانہ ہوتے ہیں ۔ واضح رہے کہ یہ خطوط اللہ کے رسول محمدؐ کی جانب سے ہیں۔ ان خطوں میں نہ تو کسی ملک کی طرزِ حکومت پر اعتراض کیا گیا تھا اور نہ کسی مخصوص طرزِ حکومت قائم کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔
اور تب خیبر فتح ہوتا ہے جو شمال میں یہودیوں کی بستی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی کے بقول ” یہ پہلا غزوہ ہے جس میں غیر مسلم رعایا بنائے گئے اور طرزِ حکومت کی بنیاد قائم ہوئی اور اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیا دور شروع ہوا”۔ 24 خیبر میں چوں کہ مسلمان آباد نہ تھے اور نہ مجاہدین وہاں جا کر بسنے پر راضی تھے لہذا آنحضرتؐ نے وہاں نخلستانوں اور زمینوں کو بٹائی پر یہودیوں ہی کے حوالے کردیا۔ بعد میں فدک ، وادی القریٰ اور تیمہ وغیرہ میں بھی اس طریق پر عمل کیا گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ ان زمینوں کا کچھ حصہ فے قرار پایا یعنی مسلمانوں کی اجتماعی اور مشترکہ ملکیت اور کچھ حصہ افراد کی ذاتی ملکیت ” پیداوار کے تیار ہونے کے وقت آنحضرتؐ کسی صحابی کو نصف پیداوار وصول کرنے کے لیے بھیج دیتے تھے”۔ 24
9 ہجری کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ” اب ملک میں امن و امان کا دور شروع ہوا۔ اب حصولِ زر کے مواقع حاصل تھے اس بنا پر زکوٰۃ کا حکم اس سال نازل ہوا اور تحصیل زکوٰۃ کے لیے عمال قبائل پر مقرر ہوئے۔ سود بھی اسی سال حرام ہوا26 اور یمن، حضرموت، تیمہ، نجران، مکہ، عمان اور بحرین میں والی مقرر ہوئے۔ گویا فتحِ مکہ کے بعد مدنی ریاست کی تشکیل مکمل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس نوزائیدہ ریاست کے پاس رعایا سے الگ اور بالا نہ کوئی فوج تھی نہ پولیس، نہ بڑے بڑے انتظامی دفاتر، نہ کثیر التعداد اربابِ مناصب ، نہ وزرا شوریٰ، نہ امرائے ریاست، نہ الگ الگ حکام و قضاۃ27 مگر ریاست کے وجود سے انکار ممکن نہیں۔ یہ ریاست نوعیت کے اعتبار سے شہری ریاست تھی۔ یعنی عرب کا تقریباً تین چوتھائی علاقہ اگر چہ اس ریاست کے تابع تھا لیکن سیاسی اختیارات، حقوق اور مراعات کا مرکز شہرِ مدینہ تھا۔ طرزِ حکومت کے لحاظ سے یہ ریاست تھیو کریسی تھی یعنی ریاست کا حاکمِ اعلیٰ خدا کا رسول تھا جو تعلیماتِ قرآنی کی روشنی میں احکام صادر کرتا تھا۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کا مقصد ریاست قائم کرنا تھا۔ کیا خدا کسی مخصوص ریاستی نظام کو درست اور بقیہ کونا درست سمجھتا تھا اور کیا آنحضرت صلعم دنیا میں تھیو کریسی قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ تاریخ ان سوالوں کا جواب نفی میں دیتی ہے اور عقل اس نفی کی تائید کرتی ہے۔ خدا کو اس سے کوئی سروکار نہیں ک کسی ریاست کا نظام شاہانہ ہے۔ آمرانہ ہے ، جمہوری ہے یا اشتراکی کی۔ اگر خدا کی مرضی یہ ہوتی کہ فلاں نظام ریاست رواج پائے تو وہ انسان کوابتدا ہی میں اپنی مرضی سے آگاہ کردیتا ہے اور پچھلے پانچ چھ ہزار برس سے تھیو کریسی، ملوکیت، آمریت، جمہوریت اور اشتراکیت کے جو تجربے ہو رہے ہیں ان کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ قرآن میں بادشاہتوں کے تذکرے ہیں مگر ریاست جیسے اہم مسئلے پر قرآن بالکل خاموش ہے۔ حضرتِ ابراہیم نمرود کی مطلق العنان بادشاہت پر معترض نہیں ہوتے بلکہ اس کے دعویٰ خدائی سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ فرعون کی ملازمت کو برا نہیں سمجھتے، حضرت موسیٰؑ فرعون کی طرزِ حکومت کی مخالفت نہیں کرتے البتہ اس کے دعوائے ربوبیت کو رد کرتے ہوئے خدائے واحد کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرتِ سلیمانؑ تو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی۔ پس معلوم ہوا کہ خدا نے انسان کو اس بات کی مکمل آزادی دے دی ہے کہ وہ جس طرز کی ریاست یا حکومت چاہے قائم کرے۔ آنحضرتؐ نے مختلف فرماں رواؤں کو جو خطوط لکھے ان میں بھی فقط اسلام کی دعوت دی گئی۔ طرز حکومت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بعثتِ نبویؐ کا مقصد بیان کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ:
“آنحضرت ؐ کی اصل بعثت کا مقصد دعوتِ مذہب، اصلاحِ اخلاق اور تزکیئہ نفوس تھا۔ اس کے علاوہ تمام فرائض محض ضمنی تھے۔ اس بنا پر انتظاماتِ ملکی آپؐ نے اسی حد تک قائم کئے جہاں تک ملکی بد امنی کے باعث دعوتِ توحید کے لیے عوائق پیش آتے تھے”۔28
سر زمینِ حجاز میں ریاست کا ظہور وہاں کے سیاسی اور معاشرتی حالات میں تبدیلیوں کا منطقی نتیجہ تھا۔ مدنی ریاست رفتہ رفتہ انھیں تاریخی عوامل کے بروئے کار آنے سے وجود میں آئی جن کے باعث بعض اوقات چھوٹی بستیاں شہروں میں اور شہر شہری ریاستوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ تبدیلیاں کسی فردِ واحد کی خواہشوں یا کوششوں کی مرہونِ منت نہ تھیں بلکہ معاشرتی حالات ان کا سبب تھے۔ آنحضرتؐ کبھی نہ ریاست قائم کرنے کے آرزو مند ہوئے، نہ انھوں نے ریاست قائم کرنے کا منصوبہ بنایا اور نہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جدو جہد کی البتہ مدینے کے حالات ہجرتِ نبوی کے بعد ایسی صورت اختیار کرتے چلے گئے کہ ریاست کا قیام ناگزیر ہوگیا۔
پروفیسر قمر الدین خان بڑے عالم و فاضل بزرگ ہیں۔ انھوں نے روزنامہ ڈان کراچی 14اگست 1980ء کی اشاعتِ خاص میں ایک طویل مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا۔ “اسلام کا مقصد ریاست قائم کرنا نہیں تھا اور نہ قرآن مسلمانوں کو اسلامی ریاست قائم کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ ذیل میں ہم پروفیسر صاحب کے مضمون کا خلاصہ انھیں کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں تاکہ اسلامی ریاست کی اصل حقیقت واضح ہو جائے۔
1۔فلسفہ سیاست کا بنیادی تصور ریاست ہے۔ دوسرے تمام سیاسی خیالات براہِ راست یا بالواسطہ اسی سے منسلک ہیں لیکن قرآن میں ریاست کا کوئی تفصیلی یا اجمالی نظریہ موجود نہیں ہے۔
2۔ قرآن نے دراصل کسی اصولِ ریاست کی تشریح نہیں کی ہے۔ قرآن میں کسی جگہ نہ دستورِ اساس کا مطلب اور تصور ملتا ہے نہ اقتدارِ اعلیٰ کا تصور، نہ حق رائے دہی کا اصول ، نہ انسانی حقوق کاتفصیلی تصّور اور نہ ریاستی اداروں اور تنظیموں کے ضابطے۔ قرآن شریف ان تمام موضوعات پر خاموش ہے کیوں کہ تاریخی ارتقا کے ساتھ ان کے معنی و مفہوم بدلتے رہتے ہیں مزید برآں قرآن کا مقصد ریاست قائم کرنا نہیں بلکہ معاشرے کی تخلیق ہے۔
3۔ ریاست اور آئینِ ریاست کی تعریف کی عدم موجودگی (قرآن میں) مسلمانوں کے لیے بڑی وجہ خیر ہے کیوں کہ اس کے باعث اسلام کے لیے زمانے کی ترقی کے ساتھ قدم ملا کر چلنا اور نئے حالات اور نئے ماحول کے ساتھ مطابقت کرنا ممکن ہے۔
4۔ قرآن میں اختیار اور اقتدار کا ذکر مختلف تناظر میں بار بار آیا ہے لیکن نہ تو ریاست کی کہیں تعریف کی گئی ہے نہ مثالی ریاست کی۔
5۔ سنت بھی اس موضوع پر قرآن ہی کی مانند خاموش ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر خدا کے فوری جانشینوں نے سیاسی تنظیم کے مختلف اصول کیوں اختیار کیے۔
6۔ قرونِ اولیٰ میں قرآنی ریاست کے بارے میں کبھی قیاس آرائی نہیں کی گئی۔ نظریہ سازی در حقیقت عباسیوں کے ابتدائی دور میں شروع ہوئی اور خلافت کاتمام و کمال تصور، غیر معتبر احادیث اور بعد کے تاریخی واقعات کی بنیاد پر قائم ہوا اور بعد میں خلافت کا جو نظریہ وضع ہوا اس کا کوئی تعلق قرآن سے نہ تھا۔ وہ سیاسی مصلحت اور مذہبی ضرورت کی پیداوار تھا ( یہ تمام نظریات دَورِ ملوکیت میں ایجاد ہوئے)۔
7۔ قرآن کی غلط ترجمانی اسلامی تاریخ کی بالتکر روایت ہے۔ چنانچہ دورِ حاضر مین بھی بعض علمائے دین قرآن کی اَکّا دُکّا آیتوں کو ان کے اصلی سیاق و سباق سے الگ کر لیتے ہیں اور ان سے اُن خیالوں اور ارادوں کی تائید کا کام لیتے ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔
8۔ اِن دنوں احیائے دین کے بجائے سارازور اسلامی ریاست قائم کرنے پر دیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام پہلے ضروری ہے تاکہ دین کا احیا ہو سکے۔ یہ کوشش بھی کی جارہی ہے کہ ریاست کو دین کے برابر گردانا جائے ( جماعتِ اسلامی کا نعرہ ” پاکستان کا مطلب کیا؟ لاالہ الااللہ”) لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ خود خدا نے جس کا م کو مناسب نہ جانا اس پر اتنی محنت کیوں صرف کی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ ریاست کے اصول اور ڈھانچے کا ذکر تفصیل سے بیان کردیتا اور مسلمانوں کوبے شمار خونی نزاعوں اور مستقل پریشانیوں سے بچا لیتا لیکن اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے کسی مخصوص سیاسی سانچے کا پابند کر دینا حکمتِ خدا وندی کے خلاف تھا۔ مزید برآں اسلام کا مقصد ریاست قائم کرنا نہ تھا بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا جس کی قدروں کی تشریح کر دی گئی ہے۔
9۔ریاست معاشرے کے مناصب میں سے ایک منصب ہے اور چوں کہ معاشرہ وقت کے ساتھ بدلتا اور ارتقائی مدارج طے کرتا رہتا ہے لہذا ریاست کی فطرت اور ہیئت بھی اس کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ یہ تھی اصل وجہ جس کی بنا پر قرآن نے ریاست کے اصول منضبط نہیں کیے اور مسلمانوں کو اس بات کی پوری آزادی دے دی کہ وقت اور زمانے کی مناسبت سے جس معاشرے کے لیے جس قسم کا سیاسی ڈھانچہ چاہیں وضع کرلیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علمائے دین مثلاً امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، امام غزالی اور ابن تیمہ وغیرہ نے موروثی سلطانوں کی ملازمت کی اور غیر اسلامی ریاست کی خدمت کرنے پر احتجاج نہیں کیا۔ اس کے برعکس ان میں سے اکثر ریاستوں کے بڑے سر گرم حامی تھے کیوں کہ اس وقت کے حالات میں کوئی بہتر صورت ممکن نہ تھی۔
10۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں کا خاص مقصد زمین پر قوانینِ الوہی کے مطابق سیاسی اقتدار قائم کرنا تھا۔ اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو بیش تر انبیا اپنے مشن میں ناکام رہے ۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن میں جن نبیوں کا ذکر موجود ہے ان میں سے کسی کو بھی یہ ہدایت نہیں کی گئی کہ تمھارا منصب و فریضہ دنیا میں اسلامی ریاست قائم کرنا ہے۔ وہ لوگوں کو فقط کائنات کے خالق اور رب کی عبادت کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے اور بدی سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آنحضرتؐ اور اہلِ مکہ میں نزاع کا اصل سبب یہ نہ تھا کہ آنحضرتؐ وہاں پر کوئی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے بلکہ انھوں نے اہلِ مکہ کے عقیدہ بت پرستی کو رد کیا تھا۔ قرآن نے آنحضرتؐ کے مشن کو بار بار وضاحت سے بیان کر دیا ہے:
11۔کہا جاتا ہے کہ ریاست میں حاکمیت کا مستحق صرف خدا ہے نہ کہ ریاست کے باشندے مگرظاہر ہے کہ خدا خود زمین پر آکر فیصلے نہیں کرے گا بلکہ فیصلے انسان ہی کریں گے البتہ دعویٰ یہ کریں گے کہ یہ فیصلے مقدس ہیں کیوں کہ خدا کے نام پر کیے گئے ہیں مگر اسلامی تاریخ میں بدترین قسم کا استبداد اسی طور پر نافذ ہوا ہے۔
خلاصہ
1۔ قرآن اور احادیث میں مسلمانوں کو ریاست قائم کرنےکی ہدایت کہیں درج نہیں ہے۔
2۔ قرآن اور سنت میں آئین، قانون یا سیاسی نظریے کا کوئی اصول موجود نہیں ہے۔
3۔ رسولِ مقبولؐ نے سیاسی حکومت ضرور قائم کی مگر ہو تاریخی صورتِ حال کا نتیجہ تھی، ان کے پیغمبرانہ مشن کا بنیادی مقصد نہ تھی۔
4۔ اسلامی سیاسی نظریے قرآن اور سنت پر مبنی نہیں ہیں بلکہ صحابہ ؑکرام کی آراء اور خلفائے راشدین کے عمل سے ماخوذہیں اور تاریخی حالات کا نتیجہ ہیں لہذا ان کو کوئی مذہبی سند حاصل نہیں۔
5۔ ریاست معاشرے کے مناصب میں سے ایک ہے اور ہمیشہ ضروری نہیں ہے (ہجرت سے قبل مکے میں کوئی ریاست نہ تھی مگر مسلمان موجود تھے) لہذا اسلامی معاشرہ ریاست کے بغیر کام کر سکتا ہے۔ ہندوستان ، سری لنکا، سویت یونین، برما، تھائی لینڈ، فلپائن اور متعدد افریقی ملکوں میں مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں۔
6۔ یہ دعویٰ کہ اسلام مذہب اور سیاست کا آہنگ ہے جدید تصور ہے اسلام کی تاریخ میں جس کا سراغ نہیں ملتا۔ اسلامی تاریخ میں ” اسلامی ریاست” کی اصطلاح 20 ویں صدی سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی۔
ہماری نام نہاد اسلامی جماعتیں قرآن و حدیث سے اپنے مطلب کے ریاستی نظریے ہی اخذ نہیں کرتیں بلکہ قرآن کی بعض آیتوں کو سیاق و سباق سے الگ کر کے ان سے حاکمِ وقت کی اطاعت کا جواز بھی ثابت کرتی ہیں۔ آیاتِ قرآنی کا یہ بیجا استعمال بنی اُمیّہ اور بنی عباس کے دورِ ملوکیت میں شروع ہوا اور ہنوز جاری ہے۔ چنانچہ فقہائے اسلام اپنی اطاعت گزار فہم و فراست کے ایسے ایسے نادر شاہ کار چھوڑ گئے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر ان کی ہدایتوں پر عمل کیا ہوتا تو ترکی، مصر، ایران اور عراق وغیرہ میں ملوکیت آج بھی مسلط ہوتی۔ پاکستان وجود میں نہ آتا اور الجزائر، لیبیا، شام، ہندوستان، ملائیشیا اور انڈونیشیا بدستور مغربی سامراج کے قبضے میں ہوتے۔
نظام الملک طوسی تو خیر سلجوقیوں کا وزیر تھا لہذا اس کی تصنیف ” سیاست نامہ” پر حرف زنی فضول ہے لیکن امام غزالی (1057ء 1111ء) کا سا عالمِ دین جب آیاتِ قرآنی کے ساتھ یہی ناانصافی کرتا ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ ” نصیحت الملوک” ان کی آخری تصانیف میں شمار ہوتی ہے۔ کتاب کے حصہ دوم میں امام صاحب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:
” تم کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے دو طبقے منتخب کیے اور ان کو بقیہ بندوں پر فوقیت عطا کی۔ اول انبیا، دوئم سلاطین، اپنے بندوں کو معبود کی طرف رجوع کرنے کی غرض سے انبیا بھیجے اور بندوں کی حفاظت کے لیے سلاطین بھیجے۔۔۔ سلطان زمین پر خدا کا سایہ ہے لہذا یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ سلطانی اور فرایزدی سلطانوں کو خدا نے مرحمت کی ہے لہذا ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے اوران کا حکم ماننا چاہیے۔ سلاطین سے جھگڑا کرنا درست نہیں اور ان سے نفرت کرنا غلط ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیعو اللہ واطیعو الرسول و اولیٰ لامر منکم۔29
حالاں کہ سورۂ النسا کی اس آیت کا حاکمِ وقت کی اطاعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ابو الحسن علی ابن علی ابن احمد الواحدی (وفات 428ھ /1075ء) اپنی مشہور تصنیف “اسباب النزول” 30 میں اس آیت کی شانِ نزول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:
” عبداللہ ابنِ عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابنِ حدیفہ کے باب میں نازل ہوئی۔ پیغمبر ؐ نے ان کو ایک مہم پر بھیجا تھا۔ابنِ عباس یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ پیغمبرِ اسلام نے خالد بن ولید کو ایک عرب قبیلے سے لڑنے بھیجا۔ عمار بن یاسر ان کے ہمراہ تھے۔ عمار نے ایک عرب کو پناہ دی دی جو اُسی وقت مسلمان ہوا تھا۔ خالد نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی۔ عمار کو معلوم ہوا تو انھوں نے خالد سے کہا کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا ہے اور میں نے اس کو پناہ دی ہے لہذا اس کو رہا کردو۔ خالد نے عمار کو ڈانٹا اور کہا کہ تم لشکر کے سالار نہیں لہذا تم کو پناہ دینے کا حق نہیں۔ مہم سے واپس آکر دونوں نے یہ رُوداد آنحضرتؐ کو سنائی۔ تو آنحضرتؐ نے عمار بن یاسر کے حق میں فیصلہ دیا اور نو مسلم کو پناہ دینے کو درست قرار دیا لیکن یہ حکم بھی صادر فرمایا کہ سالارِ لشکر کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہ دی جائے۔
یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی”
فوجی مہم کے دوران سالارِ لشکر کے احکام کی اطاعت نہایت ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ آج بھی افسر کی حکم عدولی فوجی قوانین کے تحت نہایت سنگین جرم خیال کی جاتی ہے لیکن اس آیت کو تاریخی پس منظر سے جدا کر کے کسی سیاسی کلیے کی بنیاد بنانا بڑی اخلاقی بد دیانتی ہے۔ یہاں ہم کو جنرل ایوب خان کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ 1969ء میں جن دنوں ان کے خلاف عوامی تحریک عروج پر تھی ایک روز میں ڈرگ روڈ سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گورا قبرستان کے چوراہے کے ایک کونے میں ساٹھ ستر فٹ کا سبز رنگ کا ایک لمبا چوڑا سائن بورڈ لگا ہے۔ اس پر ” اطیعو اللہ و اطیعو الرسول و اولیٰ لامر منکم” کی آیت معہ اردو ترجمہ نہایت جلی حروف میں لکھی ہوئی ہے۔ آگے بڑھا تو ایسے ہی بورڈ ہر چوراہے پر نظر آئے جو راتوں رات نصب کیے گئے تھے۔ البتہ چند روز بعد جب ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا تو یہ بورڈ چپکے سے اتار لیے گئے۔
امام غزالی نے ” اطیعوالامر” کا جو مفہوم پیش کیا وہ اس لحاظ سے لائقِ در گزر ہے کہ گیارھویں صدی عیسوی میں ملوکیت کے علاوہ کسی دوسری طرزِ حکومت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن مولانا ابو الاعلیٰ مودودی بیسوی صدی کی آٹھویں دہائی میں کہ عوامی جمہوریت کا دور ہے جب اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے یہ فقیہانہ دعویٰ کرتے ہیں کہ:
” یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی او سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔” 31
تو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جس شخص نے قرآن کا ترجمہ معہ تفسیر کیا ہو وہ اس آیت کی شانِ نزول سے واقف نہ ہو اور جس آیت کا کوئی تعلق اسلام کے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام سے نہیں اس کو وہ اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ قرار دے۔ فریب خودردہ اور فریب کارذہنیت کی اس سے بری مثال مشکل سے ملے گی۔
عباسیوں کے دور ملوکیت میں تو ایسی حدیثیں بھی گڑھ لی گئیں جن سے حاکمِ وقت کی اطاعت مذہباً واجب قرار پائے۔ چنانچہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے امام بخاری کی کتاب الاحکام کے حوالے سے اس حدیث کو اپنے موقف کی تائید میں پیش کیاہے۔ فرماتے ہیں کہ ” حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ ” اسمعو او اطیعو اولواستعمل علیکم عبد حبشی” سنو اور اطاعت کرو اگر چہ تمھارا سردار ایک حبشی ہی کیوں نہ بنا دیا جائے۔” 32
پاکستان میں اِن دنوں ایک ، مجلسِ مشاورت، مرکزی سطح پر قائم ہے۔ اس کی کارروائیوں کی خوب پبلسٹی ہو رہی ہے اور یہ تاثر دیا جارہا ہے گویا اس مجلسِ شوریٰ کا قیام احکام قرآنی کے عین مطابق ہے حالاں کہ مجلسِ شوریٰ کو پاکستان کے باشندوں نے منتخب نہیں کیا ہے بلکہ ایک شخصِ واحد نے نامزد کیا ہے۔ حکومت اس کے فیصلوں اور ” مشوروں ” کی پابند بھی نہیں اور نہ اس کے رو برو جوا ب دہ ہے۔
قرآن شریف میں آپس میں مشورہ کرنےسے متعلق فقط دو نہایت مختصر آیتیں ملتی ہیں۔ پہلی آیت میں آنحضرتؐ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ” وشاور ہم فی لامر فازاعزمت فتو کل علی اللہ (اور ان سے معاملات میں مشورہ کرو پھر جب تم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ سو رہ آل عمران 159) طبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ” علمانے الامر کی دو تفسیریں کی ہیں۔ بعضوں کا خیال ہے کہ الامر سے مراد جنگ کی حکمتِ عملی ہے اور بعضوں کا خیال ہے کہ الامر سے مراد دینی مسائل ہیں” 33 اس آیت کا تعلق جنگ احد کے واقعات سے ہے لہذا اول الذکر تشریح مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا اور وہ شکست سے بال بال بچے تھے۔ وہاں جو سانحے پیش آئے ان کا مسلمانوں کی نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑا تھا چنانچہ آلِ عمران کی مسلسل چالیس آیتوں (120۔159) میں جنگ ِ احد کے واقعات اور ان سے پیدا ہونے والی صورتِ حالات کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور خدا نے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی ہے اور ان کی تسکینِ قلب کی ہے اور آخر میں آنحضرتؐ کو ہدایت کی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرلیا کرو۔
دوسری آیت کی نوعیت عمومی ہے۔ پوری آیت یہ ہے۔
ولاذین الستجابو الربھم وااقامو الصلوٰۃ وامرھم شوریٰ بینھم و مما رزقنھم ینفقون
جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں ، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں ( سورہ الشوریٰ۔37)
ظاہر ہے کہ ان دونوں آیتوں کا کوئی تعلق جمہوریج نظام یا ملکی سیاست سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مشیر اور منتخب شدہ رکن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حکومت مشیروں کے مشورے کو جی چاہے مانے جی چاہے نہ مانے لیکن مجلسِ قانون ساز کے منتخب شدہ ارکان اگر کوئی فیصلہ کثرتِ رائے سے کریں تو اس کی تعمیل حکومت کا فرض ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر ان آیتوں کی جو تفسیر کی جارہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔
مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہونے کی وجہ سے اشاعتِ اسلام کی سہولتیں بڑھیں اور مسلمانوں کے اثر و اقتدار اور دولت اور دولت آفرینی کے ذرائع میں حیرت انگیز اضافہ ہوا مگر اُمت واحدہ کو تقویت نہیں ملی کیوں کہ اُمتِ مسلمہ کا تصور اجتماعیت کا متقاضی تھا جب کہ مدنی ریاست کا میلان انفرادیت کی جانب تھا اور اقتصادی ڈھانچہ ذاتی ملکیت کو فروغ دینے کی اجازت دیتا تھا۔ آنحضرتؐ کی آنکھ بند ہوتے ہی امت اور ریاست کے تضادات کھل کر سامنے آگئے۔ حصولِ اقتدار کی کشمکش ، قبائلی گروہ بندیاں اور طبقاتی امتیازات جن پر رسولؐ کی عظیم شخصیت پوری طرح حاوی تھی منظرِ عام پر آگئے۔ ابھی آنحضرتؐ کی لاشِ مبارک دفن بھی نہیں ہوئی تھی کہ اکابر انصار نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر سعد بن عبادہ کو ریاست کا سربراہ چن لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عمر کو اس اجتماع کی خبر ملی تو وہ حضرت ابو بکرنے رسول اللہ ؐ کا یہ قول پیش کیا کہ ” الائمہ من القریش ” (امام قریش میں سے ہوں گے) تو اس روایت کو انھوں نے قبول کیااور سچ سمجھا اور اب تک وہ خود تنہا جو کار روائی کررہے تھے اس سے رُک گئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک امیر ہو اور تم میں سے ایک امیر ہو، پھر جب حضرت ابو بکرنے فرمایا کہ ہم امیر بنیں اور تم وزیر بنو تو انصار نے ان کی اس بات کو منظور کرلیا۔34
خلافتِ راشدہ کے عہد میں فتوحات میں روز افزوں توسیع کے ساتھ امت کے جسدِ واحدہ میں پھوٹ اور نزاع کا زہریلا مادہ بھی بڑھتا گیا۔ یمنی مسلمانوں کا زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑے پیمانے پر قتل، ارتداد کا فتنہ، چار میں سے تین خلفا کی مسلمانوں کی بغاوتیں، حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کی نزاع اور پھر حضرت علی رضی اللہ اور امیر معاویہ رضی اللہ کے درمیان باقاعدہ جنگ اور خوارج کا ظہور وہ المناک واقعات ہیں جن سے اُمت اور ریاست کا تضاد واضح ہو جاتا ہے۔
مدنی ریاست دراصل عبوری ریاست تھی جو قبائلی جمہوریت اور ملوکیت کی درمیانی کڑی تھی۔ وہ نہ جمہوریت تھی نہ ملوکیت بلکہ چند سری حکومت تھی۔ ایک طرف قبائلی روایتیں تھیں۔ دوسری طرف نوزائیدہ ریاست تھی جس نے قبائلی حدوں کو توڑ دیا تھا کیوں کہ یہ بندشیں ریاست کے نظم و نسق میں حارج تھیں البتہ چاروں خلفا کا چار مختلف طریقوں سے انتخاب قبائلی جمہوریت اور ریاست کے تقاضوں کے مابین مفاہمت کی مخلصانہ کوشش تھی جو کامیاب نہ ہو سکی 35 اور جب ریاست کا تو سیعی دور شروع ہوا اور شہری ریاست ایک وسیع و عریض سلطنت میں تبدیل ہو گئی تو قبائلی جمہوریت کے بچے کھچے اثرات بھی زائل ہو گئے۔ فتح ایران کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے مالِ غنیمت کا انبار لگا تو آپ زارو قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین خوشی کے اس مبارک موقع پر آپ رو کیوں رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ نے جوا ب دیا کہ اس انبار میں، میں اسلام کی تباہی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ ریاست کی توسیعی سرگرمیوں کے انجام سے بخوبی آگاہ تھے لیکن معاشرتی ارتقا کے عمل کو وہ روک نہیں سکتے تھے چنانچہ وہی ہوا جس کا ان کو اندیشہ تھا۔ خلافتِ راشدہ بنی امیہ کی مطلق العنان ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔
اس سوال کے جواب میں کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں میں جمہوریت نے کیوں فروغ نہ پایا۔ علامہ اقبال ؒ لکھتے ہیں کہ:
” قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی زندگیوں زیادہ تر فتوحات کی زندگی تھی۔ان کی تمام قوت و ہمت، تمام رحجان و میلان ملک و سلطنت کی تقویم و توسیع کے لیے وقف تھا۔ دنیا میں اس روش کا ہمیشہ یہی نتیجہ ہوا کہ حکومت اور ریاست کی باگ ہمیشہ چند افراد کے ہاتھ میں رہی ہے جن کا اقتدار گو نادانستہ طور پر تاہم عملاً مطلق العنان بادشاہ کے اقتدار کے مترادف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ سوائے اس کے اور کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ جمہوریت قدرتاً شہنشاہیت کے دوش بدوش چلنے اور کام کرنے کو تیار نہیں۔” 36
علامہ اقبال نے توسیع پسندی کے جن نتائج کی جانب اشارہ کیا وہ بے شک صحیح ہیں لیکن ہم کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ ساتویں صدی عیسوی دنیا کے کسی گوشےے میں بھی کوئی جمہوری ریاست نہ موجود تھی اور نہ ممکن۔ افریقا اور ایشیا میں بے شمار ایسے قبائل تھے جن کا طرزِ معاشرت جمہوری تھا مگر وہ ریاستیں نہ تھیں۔ یہ بھی درست ہے کہ بعثِ رسولؐ سے ہزار برس پیش تر یونان کی متعدد شہری ریاستوں کا طرزِ حکموت جمہوری تھا 37 اور ان کا جمہوری نظام اپنی خامیوں کے با وصف چار پانچ سو سال تک کامیابی سے چلتا رہا۔ مگر قرونِ اولیٰ کے عربوں پر جن کو ریاستی نظام ہی کا کوئی تجربہ نہ تھا اور نہ وہ غالباً یونانی جمہوریت کی تاریخ سے واقف تھے یہ اعتراض کرنا ک انھوں نے جمہوری ریاست کیوں نہ قائم کی اسی ” ذہنیت حاضرہ” کی علامت ہے جس کا ہم ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں۔
جمہوریت میں اقتدارِ اعلیٰ کا سر چشمہ ریاست کے باشندے ہوتے ہیں اور ریاست کے تینوں عناصر ترکیبی۔ مقنّہ، انتظامیہ اور عدلیہ ان کے چنے ہوئے نمائندوں کی مرضی و منشا کے مطابق اپنے فرائضِ منصبی سر انجام دیتے ہیں۔ ساتویں صدی عیسوی میں ان اصولوں پر عمل کرنا ممکن ہی نہ تھا لہذا بحث فضول ہے کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں میں جمہوریت نے فروغ کیوں نہیں پایا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ قرونِ وسطیٰ میں ریڈیو اور ٹیلی فون او رہوائی جہاز کیوں رائج نہیں ہوئے۔
خلافتِ راشدہ اور عہدِ بنی امیہ میں کسی نے بھی ریاست کی نوعیت پر غور نہیں کیا اور نہ اسلامی ریاست کے اصول وضع ہوئے۔ ریاست کے نظریاتی مسائل پہلی بار بنی عباس کے دور بحث آئے مگر جن فقہا 38 نے اسلامی ریاست کے قاعدے اور ضابطے تدوین کیے وہ سب کے سب دورَ ملوکیت کے پر وردہ تھے اور ملوکیت کو بد یہی اور ابدی حقیقت سمجھتے تھے۔ ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ کس طرح ملوکانہ طرزِ حکومت کا ڈانڈا اسلامی تعلیمات سے ملا دیا جائے اور عامتہ الناس کو یہ باور کرو ادیا جائے کہ حکومت اسلامی شریعت کے عین مطابق ہے۔
فقہائے اسلام ریاست کا کوئی مسئلہ پیش نہیں کرتے اور نہ اقتدارِ اعلیٰ کے مسئلے سے بحث کرتے ہیں حالانکہ ریاست کا کلیدی مسئلہ یہی ہے کہ ریاست میں اقتدار کا مالک کون ہے اور اقتدار کا اس کو کیا استحقاق ہے۔ فقہا ہم کو یہ تو بتاتے ہیں کہ سربراہِ مملکت کے اوصاف کیا ہوں اور احکامِ شریعت کو نافذ کرنے کی خاطر ہو کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ سربراہِ مملکت اقتدار کا مالک کیسے بنے۔ آیا اس کا انتخاب ہو یا جو شخص بھی طاقت کے بل پر یا قانونِ ِ وراثت کی بنیاد پر مملکت کا حاکم ِ اعلیٰ بن جائے ( بنی اُمیّہ اور بنی عباس کے عہد میں انھیں دونوں طریقوں پر عمل ہوا) ہمارا فرض اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ابن جمع (1241۔ 1333ء) ” قہر الصاحبِ الشوک ” کو جائز سمجھتا ہے39 یعنی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔
اس موضوع پر الماوردی خلیفہ القادر (991ء۔1031ء) کے عہد میں بغداد کا قاضی تھا۔ یہ زمانہ خلافتِ عباسیہ کے انحطاط کا تھا اور ضمام اختیار پر بودیہہ امرا کا قبضہ تھا۔ ماوردی کی رائے میں خلافت، امت مسلمہ اور خلیفہ کے درمیان ایک معاہدہ آزاد فریقین کے درمیان ان کی مرضی خوشی سے ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاہدے کی یہ بنیادی شرط خلافت کے کسی دور میں بھی پوری نہیں ہوئی۔ کہا جا تاہے کہ بیعت ہی اُمت کی مرضی کا ثبوت تھی مگر بیعت میں خلیفہ پہلے اقتدار پر قابض ہوتا تھا تب لوگوں سے بیعت لیتا تھا اور جو شخص بیعت سے انکار کرتا تھا اس کا حشر برا ہوتا تھا۔ ( اس کے برعکس موجودہ دور کے جمہوری انتخابات میں صدارت یا وزارت کا امیدوار پہلے ووٹروں کی اکثریت کی منظوری حاصل کرتا ہے تب صدر یا وزیر بنتا ہے)
ماوردی خلیفہ کی موزونیت کی متعدد شرطیں بیان کرتا ہے مثلاً وہ شریعت سے واقف ہو، تندرست ہو، مرد ہو، بالغ ہو، قریش ہو لیکن امت کی مرضی کا کہیں ذکر نہیں کرتا۔ اس فرو گذاشت کا ذمہ دار ماوردی نہیں بلکہ قرونِ وسطیٰ کا معاشرہ تھا۔ فیوڈلزم کے دور میں دنیا کے کسی ملک میں عوام کو اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ جمہوری تصور کہ اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ ملک کے باشندے ہیں۔ دور جدید کی پیداوار ہے۔ قرونِ وسطیٰ میں رعایا کی مرضی معلوم کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ امرائے دربار یا دارالحکومت کے علما و عمائدین کسی موزوں شخص کو ریاست کا سربراہ مقرر کردیں۔ البتہ قرونِ وسطیٰ کے معروضی حالات اور دورِ حاضر کے معروضی حالات کے فرق کو نظر انداز کر کے پرانے زمانے کے طرزِ انتخاب کو بطور آئیڈیل پیش کرنا یا اس کا موازنہ جدید طرز کے جمہوری انتخاب سے کرنا صریحاً غلط ہے۔
ماوردی کو اپنے عہد کی معروضی دشواریوں کا احساس تھا لہذا وہ خلیفہ کے لیے ” اھل العقد و الحل ” کی منظوری کو لازمی قرار دیتا ہے۔ اربابِ حل و عقد سے اس کی مراد علما ہیں۔ مگر مشکل یہ تھی کہ عالم دین کی پہچان کا کوئی پیمانہ نہ تھا۔ ان کی کوئی مرکزی تنظیم نہ تھی نہ وہ ایک مقام پر رہتے تھے لہذا وی علما ” اھل العقد و الحل ” تصور کئے جاتے تھے جو اربابِ اختیار کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ پھر بھی ماوردی کا سیاسی شعور میاں طفیل محمد صدر جماعت اسلامی سے بہتر ہے۔ موصوف جب موجودہ دور کے لیے ” اربابِ حل و عقد” کے ذریعے صدر مملکت کے انتخا ب کی تجویز پیش کرتے ہیں تو اپنا اور اپنی تاریخ د انی دونوں کا مذاق اڑواتے ہیں۔
امام غزالی بھی ماوردی کی طرح خلیفہ کے لیے بالغ ہونے، صاحب عقل و ہوش ہونے، آزاد ہونے، مرد ہونے، قریش ہونے، صاحبِ کفایہ ہونے، صاحب علم و ورع ہونے کی شرطیں مقرر کرتے ہیں لیکن ارشارۃً بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو رعایا کا منتخب شدہ نمائندہ ہونا چاہیے۔ ماوردی ” حاکمیت ” کو ” عہد” سے تعبیر کرتا ہے لہذا اس کی گنجائش رکھتا ہے کہ اگر حاکم وقت معاہدے کی شرطیں پوری نہ کرے تو رعایا اس کو بر طرف کر سکتی ہے۔ امام غزالی غیر مشروط اطاعت پر اصرار کرتے ہیں اور رعایا کو کسی حالت میں بھی حاکم وقت کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ:
” رعایا کا فرض ہے کہ اپنے سلطان کی عزت کرے اور اگر خدا کے حکم کی تعمیل منظور ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں تو کبھی کسی طور پر بھی سلطان کے خلاف بغاوت نہ کرے۔”40
ان کی تھیو کریسی میں ظل اللہ اور صاحبِ امر سے گلو خلاصی کی تمام راہیں بند ہیں۔
امام غزالی بھی ماوردی کی مانند سربراہِ مملکت کے لیے اربابِ حل و عقد کی منظوری ضروری سمجھتے تھے لیکن امام الحر مین جو ینی نے تکلف کا یہ پردہ بھی ہٹا دیا اور فرمایا کہ فقط ایک صالح شخص کی منظوری کافی ہے41 گویاں میں طفیل محمد یا پروفیسر عبدالغفور اگر منظوری دے دیں تو کوئی شخص بھی پاکستان کا صدر ہو سکتا ہے۔
2
ریاست کی ظاہری شکل جمہوری ہو یا آمرانہ اُس کا حقیقی منصب برسرِ اقتدار طبقے کے مفاد کا تحفظ ہے۔ اس فریضے کو نہ اسلامی ریاست نظر انداز کر سکتی ہے اور نہ غیر اسلامی ریاست۔ پاکستانی سیاست کے گزشتہ 35 سال ریاست کے اس طبقاتی کردار کا ناقابل تردید ثبوت ہیں۔
پاکستان کی تحریک قرار داد پاکستان کے بعد ہر چند کہ عوامی تحریک بن گئی تھی اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کی بھاری اکثریت کا اعتماد حاصل تھا لیکن آزادی وطن کی خاطر برطانوی سامراج کے خلاف راست اقدام لیگی سیاست کا مسلک نہ تھا۔ مسلم لیگ کی نظر میں تحریکِ پاکستان کے اصل مخالف انگریز نہ تھے بلکہ کانگریس تھی جس کو لیگی قیادت ہندوؤں کی نمائندہ جماعت خیال کرتی تھی۔ لیگی قیادت کا واحد نعرہ مسلمانانِ ہند کو ہندو اکثریت کے غلبے اور استحصال سے نجات دلانا اور ایک ایسی ریاست قائم کرنا تھا جس میں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہو مگر تحریک ِ پاکستان کے دوران لیگی قیادت سنجیدگی سے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ پاکستان بن جانے کے بعد نئی ریاست کی نوعیت کیا ہوگی ۔ اُس کا سیاسی ڈھانچہ کن اصولوں کے مطابق بنے گا اور ریاست کا اقتصادی یا سماجی نظام کیا ہو گا۔ حالاں کہ مسلم لیگی کی حریف جماعت کانگریس نے انھیں مقاصد کے پیش نظر 1935ء میں صوبائی الیکشنوں سے بھی پہلے ایک نیشنل پلاننگ کمیشن قائم کر دیا تھا جس کے سر براہ پروفیسر کے ٹی شاہ تھے۔ دوسری طرف سوشلسٹ نظریات کے حامی بھی آزاد ہندوستان کے ریاستی ڈھانچے کے متعلق زور و شور سے اپنے اپنے خیالات کی تبلیغ کررہے تھے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کے نئے مجموعے بالِ جبریل اور ضربِ کلیم شائع ہو چکے تھے جن میں اقبال نے جمہوریت اور اشتراکیت کی تائید میں اپنے خیالات بڑی وضاحت سے بیان کردیے تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کے اقتصادی مسائل کی جانب سے مسلم لیگ کی غفلت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے مسٹر جناح کو لکھا تھا:
” لیگ کو بالآخر یہ طے کرنا ہوگا کہ آیا وہ بدستور ہندوستانی مسلمانوں کے اونچے طبقوں کی نمائندگی کرتی رہے گی یا مسلم عوام کی جنھوں نے اب تکک جائز طور پر لیگ میں کوئی دل چسپی نہیں لی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو سیاسی تنظیم عام مسلمانوں کے حالات زندگی کو بہتر بنانے کا وعدہ نہیں کرتی ہمارے عوام کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی۔” 42
لیکن لیگی قیادت کا طبقاتی کردار، اس کی دیرینہ روایت اور اُس کی سوچ کا انداز ریاست کی نوعیت پر غورو فکر کی اجازت نہ دیتا تھا ۔ مسلم لیگ نوابوں، راجاؤں، خان بہادروں، سرداروں اور سروں کے بوجھ تلے اتنی دبی ہوئی تھی کہ خود قائدِ اعظم بھی نئی ریاست کے نقوش کی وضاحت کرنے ہچکاتے تھے کہ مبادا یہ با اثر گروہ ناراض ہو جائے اور لیگ میں پھوٹ پڑجائے لہذا ان سے جب کوئی نئی ریاست کے بارے میں سوال کرتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ پاکستان کی نئی ریاست تھیو کریسی نہیں ہوگی یا یہ کہ ” ملکی پروگرام ار پالیسیوں کا وقت بھی آئے گا لیکن پہلے حکومت تو ملے۔ ابھی تو اس قوم کے پاس نہ کوئی علاقہ ہے نہ حکومت۔”
غرضیکہ لیگی قیادت نے مسلمانوں کی سیاسی تعلیم کی طرف ذرہ برابر توجہ نہ دی بلکہ ان کو سارا وقت جذباتی نعروں کا نشہ پلاتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم عوام ریاست کی تشکیلِ نو کے بارے میں بالکل اندھیرے میں رہے بلکہ دانستہ طور پر اندھیرے میں رکھے گئے لہذا پروفیسر گونر مرڈیل کا یہ خیال کہ ” مسلم لیگی رہنماؤں کے ذہن میں نئی ریاست کی نوعیت کا کوئی واضح تصور نہ تھا درست نہیں”43 قائداعظم جیسا کہ ان کی بعد کر تقریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانوی طرز کی پارلیمانی جمہوریت کے حق میں تھے مگر لیگی قیادت کے فیوڈل عنصر کو جمہوریت سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ جمہوریت اُس کی معاشرتی زندگی کے اخلاقی اصولوں میں شامل نہ تھی نہ جمہوریت سے اس کے طبقاتی مفاد کی توسیع ہوتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لیگی لیڈروں نے پاکستان کی تحریک مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح و ترقی کی غرض سے نہیں شروع کی تھی بلکہ نئی ریاست میں حکومت کرنے کی ہوس ان کو قائد اعظم کے قریب لے گئی تھی۔ یہی وجہ یہ کہ لیگی قیادت نے ریاست کی سماجی اور اقتصادی ترقی کا کوئی پروگرام جان بوجھ کر وضع نہیں کیا۔ مسلم عوام کو فقط طفل تسلیوں سے بہلاتی رہی۔
پاکستان کی نئی ریاست میں نظم و نسق 1935ء کے قانونِ ہند کے تحت شروع ہوا۔ اس قانون کی تشکیل میں کسی مسلمان سیاست داں کا ہاتھ نہ تھا بلکہ اس کو برطانوی حکومت نے اپنے مفاد کے پیش نظر وضع کیا تھا لہذا اس قانون کی رُو سے اقتدارِ اعلیٰ کے مالک پاکستان کے باشندے نہ تھے بلکہ گورنر جنرل تھا۔ تمام اختیارات کا مرکز و منبع اسی کی ذات تھی جو کسی کے رو برو جواب دہ نہ تھی۔ دوئمش اس قانون کے دائرے میں رہ کر ریاست کے سماجی اور اقتصادی ڈھانچے میں کسی بنیادی تبدیلی کی گنجائش نہ تھی بلکہ مروجہ ڈھانچے کو بر قرار رکھنے کی ضمانت دی گئی تھی۔ تیسرے اس قانون کے مطابق انتظامیہ کو قریب قریب مکمل طور پر افسر شاہی کے تابع کر دیا گیا تھا اور انگریزوں کا تربیت یافتہ یہ وہ طبقہ تھا جو جمہور اور جمہوریت دونوں کو بڑی نفرت و حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس قانون میں دفاع کے نام پر فوج کو ایک خود مختار، مطلق العنان اور بر گزیدہ ادارے کی حیثیت دے دی گئی تھی گویا فوج قوم کے تابع نہ تھی بلکہ اس کی حیثیت فاتحِ لشکر کی تھی۔
یہ آمرانہ قانون پاکستان کے حکمران طبقے کے مفاد کے عین مطابق تھا چنانچہ وہ کسی نہ کسی بہانے نو سال تک اس غیر جمہوری قانون کے ذریعے ملک پر حکومت کرتے رہے۔ اسی آئین ِ بےآئین کی آڑ لے کر بعض صوبائی وزراتیں بر طرف کی گئیں۔ ملک کے ایک حصے میں پہلی بار مارشل لا لگایا گیا (1953ء) اور بالآخر گورنر جنرل غلام محمد نے مرکزی حکومت اور قومی اسمبلی دونوں کو توڑ دیا۔
آئین ساز اسمبلی نے بڑی بحث و تحمیص کے بعد جو قرار داد منظور کی اس سے بھی نئی ریاست کی نوعیت واضح نہیں ہوئی۔ نئی ریاست کا نام ” اسلامک ری پبلک آف پاکستان” تجویز پایا۔ ریاست کی حاکمیت ملک کے باشندوں کے بجائے خدا کو سونپ دی گئی اور عہد کیا گیا کہ نیا آئین قرآن اور سنت کی روشنی میں وضع ہوگا۔
لیکن پاکستان دنیا سے الگ تھلگ کوئی جزیرہ نہ تھا جس پر بین الاقوامی حالات اور خیالات کا اثر نہ پڑتا ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے گوشے گوشے سے سوشلزم کی صدائیں آرہی تھیں۔ مشرقی یورپ میں سوشلسٹ ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ چین میں کمیونسٹوں نے ماؤزے تنگ کی قیادت میں چیانگ کائی شیک کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ انڈو نیشیا میں جو سب سے بڑا اسلامی ملک ہے صدر سیکار نو ریاست کو سوشلسٹ خطوط پر تشکیل دے رہے تھے۔ برما نے اپنے سوشلسٹ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ ہندوستان کے نئے آئین میں سو شلسٹ اُصولوں کو نمایاں حیثیت دی گئی تھی اور وزیراعظم نہرو سوشلزم کی حمایت کررہے تھے۔ خود برطانیہ میں جس کے ساتھ دولتِ مشترکہ کے ناتے ہمارا گہرا رشتہ تھا لیبر پارٹی کی حکومت تھی جس کا نصب العین سوشلزم ہے۔ ان حالات میں لیگی قیادت کے لیے سوشلزم سے صرف نظر کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ نواب زادہ لیاقت علی خان نے جو وزیراعظم ہونے کے علاوہ ملک کی سب سے با اثر شخصیت تھے ” اسلامی سوشلزم ” کا نعرہ بلند کیا اور پاکستان کی اسلامی ریاست کی تشکیل و تعمیر کے لیے سو شلسٹ اصولوں کو اپنانے کا خیال ظاہر کیا۔ اگست 1949ء میں لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ:
” ہمارے لیے فقط ایک “ازم ” ہے اور وہ ہے اسلامی سوشلزم ، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس ملک میں روٹی کپڑا، مکان، تعلیم اور طبی سہولتوں کے حصول کا مساوی حق ہے۔ وہ ملک جو اپنے باشندوں کو یہ چیزیں فراہم نہیں کرتے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ اقتصادی پرو گرام جو اب سے 1350 برس پہلے (عہدِ نبویؐ میں) مرتب ہوا تھا ہمارے لیے آج بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ”
نواب زادہ لیاقت علی خان نے اپنے امریکا کے سفر کے دوران بھی اسلامی سوشلزم کا تذکرہ کئی بار کیا لیکن اسلامی سوشلزم کا خواب شرمندہ معنی ہی رہا۔ اُن کو دشمنوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ہر شخص جانتا ہے کہ لیاقت علی خان مرحوم کو راستے سے ہٹانے والے افراد کون تھے اور کس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔
لیاقت علی خان مرحوم کی وفات کے بعد درباری سازشیں ہمارے ملک کا معمول بن گئیں اور عنانِ اختیار مکمل طور پر افسر شاہی کے ہاتھ میں آگئی۔ نیا آئین نافذ ہوا مگر وہ قانون ہند کی شراب تھی جو نئی بوتل میں انڈیل دی گئی تھی۔ جنرل اسکندر مرزا جن کا تحریکِ پاکستان سے دُور کا بھی واسطہ نہ تھا صدر مقرر ہوئے اور ” کنٹرولڈ ڈیما کریسی” کے حق میں گہرا افشانی فرمانے لگے حالاں کہ انہوں نے نئے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا تھا مگر نئے آئین کے تحت ابھی عام انتخابات بھی نہ ہوئے تھے کہ جنرل اسکندر مرزا کی ” کنٹرولڈ ڈیما کریسی” جنرل ایوب خان کے مارشل لا اور فوجی ڈکٹیٹر شپ کی شکل میں ملک پر مسلط ہو گئی۔
جنرل ایوب خان کو اپنے پیش رو جنرل کی تقلید منظور نہ تھی لہذا انہوں نے “کنٹرولڈ جمہوریت” کہ جگہ ” بینادی جمہوریت” کی اصطلاح وضع کی اور دعویٰ کیا کہ اسلامی ریاست کی روح یہی بنیادی جمہوریت ہے۔
” میرا خیال ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید کرنے کے بجائے ہم کو Consensus of opinion کے تصور کے تحت اپنے نمائندہ اداروں کو چلانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر سکے اور نہ کر سکنے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ ہماری تمام تاریخ اور مذہبی روایت اسی پر مبنی ہے تو ہم پارٹی سسٹم کی لعنت سے نجات پا جائیں گے” 44
مگر جنرل موصوف نے یہ نہ بتایا کہ لوگوں کی رائے معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا اور جن ” نمائندہ” اداروں کا انہوں نے ذکر کیا وہ عوام کے انتخاب کے بغیر ” نمائندہ” کہلانے کے مستحق کیوں کر ہوں گے۔ اسلامی تاریخ اور اسلامی روایات کا درس دیتے ہوئے جنرل ایو ب خان نے فلسفہ سیاسیات کے چند نئے کلیے بھی وضع کیے مثلاً انہوں نے کہا کہ جمہوریت فقط سرد ملکوں کے لیے موزوں ہے گر م ملکوں کے لیے نہیں۔ یعنی ان کے بقول جمہوریت کا نازک پودا مری، ایبٹ آباد اور نتھیا گلی میں تو بار آور ہو سکتا ہے لیکن لاہور، ملتان اور کراچی کی گرمی کی تاب نہیں لا سکتا۔
جنرل ایوب خان کا دور ” عشرہ ترقی” ختم ہوا تو 1949ء میں جنرل یحییٰ خان برسرِاقتدار آئے اور ملک میں پہلی بار 23 سال بعد ایک فرد ایک ووٹ کے اصول کے تحت عام انتخابات منعقد ہوئے۔ الیکشن میں عوامی لیگ کو اکثریت حاصل ہوئی مگر مغربی پاکستان کے بعض طاقت ور عناصر جن کو جنرل یحیٰ خان کی فوج اور افسر شاہی کی حمایت بھی حاصل تھی عنانِ اختیار مشرقی پاکستان کے نمائندوں کے حوالے کرنے پر ہر گز تیار نہ تھے۔ نیتجہ یہ ہوا کہ پاکستان کا اکثریتی صوبہ پاکستان سے جدا ہو گیا اور ملک میں مارشل لا دوبارہ نافذ کردیا گیا۔
لیکن جمہوریت اتنی سخت جان ہے کہ افسانوی پر ندققنس کی مانند چتا میں جل کر پھر جی اٹھتی ہے چنانچہ 1973ء میں ایک نیا آئین پارلیمانی جمہوریت کی بنیادوں پر قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور ہوا لیکن اس آئین کا بھی وہی حشر ہوا جو 1956ء کے آئین کا ہوا تھا ع
زبادہ تابہ قدح ریختم بہار گذشت
ہم دائرے کے جس نقطے سے چلے تھے وہیں واپس پہنچ گئے اور یہ سبق پڑھنے میں مصروف ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلامی نظام کس کو کہتے ہیں۔ ان کاموں سے اگر فرصت ملی تو اسلامی ریاست پر بھی غور کر لیں گے۔ جلدی کیا ہے ریاست جس انداز سے چل رہی ہے اُسی کو اسلامی ریاست قرار دینے میں کیا چیز مانع ہے۔
حوالہ جات و حواشی
1۔ ڈاکٹر عبدالسلام، خطبہ صدارت، 13 ویں کل پاکستان سائنس کانفرنس، ڈھاکہ، 11 جنوری 1961ء
2۔Reconstruction of Religious thought in Islam, Lahore
3۔ ایضاً۔ ص 67
4۔ ایضاً۔ ص 70
5۔ ایضاً۔ ص 133
6۔ ایضاً۔ ص 138
7۔ ایضاً۔ ص 164
8۔ ایضاً۔ ص 147
9۔ ایضاً۔ ص 148
10۔ ایضاً۔ ص 151
ایضاً۔
12۔Wattt, Mohammad at Mecca, Oxford, 1965, p. 15 W. Montgonery
13۔ علامہ شبلی نعمانی، سیرۃ النبیؐ، جلد اول۔ کراچی
14۔ Philip Hitti, History of the Arabs. London,1958,p.101
15۔ ابن اصحاق، سیرۃ رسول اللہ ، (انگریزی)، کراچی، 1967ء ص 48،53
16۔ Montgomery Watt, Mohammad Mecca, p. 141
17۔ Montgomery Watt, Mohammad at Medina, Oxfor, 1692, p. 173
18۔ ایضاً
19۔ ابن اصحاق (انگریزی)، ص 197
20۔ ایضاً ۔ ص 198
21۔ ایضاً۔ ص۔ 199
22۔ ایضاً۔ ص۔208
23۔ آنحضرتؐ کی بنی خزرج سے چار پشتوں کی قرابت تھی۔ آپ کے پردادا ہاشم کی شادی سلمیٰ بنتِ عمر (بنی بخار) سے ہوئی تھی۔ ” سلمیٰ کا مرتبہ اپنے قبیلے میں بہت اونچا تھا او ر وہ شادی اس شرط پر کرتی تھیں کہ اپنے معاملات کی دیکھ بھال وہ خود کریں گی اور شوہر پسند نہ آیا تو اس کو چھوڑ دیں گی”۔ (ابنِ اصحاق ص 58) ہاشم سے پہلے وہ ایک شادی کر چکی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے عبدالمطلب کو لے کر مدینے ہی میں رہیں اور ہاشم کے انتقال کے بعد جب ان کے بھائی اپنے بھتیجے کو لینے آئے تو ماں نے پہلے تو صاف انکار کردیا پھر بڑی مشکل سے راضی ہوئیں۔ اس وقت عبدالمطلب کی عمر آٹھ سال تھی۔ عبدالمطلب کی وفات کے بعد بھی بنی ہاشم کے تعلقات مدینے سے منقطع نہیں ہوئے چنانچہ آنحضرتؐ کے والد عبداللہ کا انتقال مدینے ہی میں ہوا اور جب آپؐ چھ سال کے تھے تو حضرت آمنہ آپ ؐ کو لے کر رشتہ داروں سے ملنے مدینے گئیں۔ وہاں ایک ماہ قیام کیا اور وفات پائی لہذا مدینہ آنحضرتؐ کے والدین کا مرقد بھی تھا۔
24۔ سیرۃ النبیؐ، ص 480۔500
25۔ علامہ سید سلیمان ندوی ( مرتب) سیرۃ النبیؐ ، جلد دوم، ص 82
26۔ سیرۃ النبیؐ، ص 572
27۔ سیرۃ النبیؐ، جلد دوم، ص 59
28۔ ایضا۔
29۔ امام غزالی، نصیحت الملوک، لندن 1964ء ص 44
30۔ مطبوعہ ہندیہ، قاہرہ، 1375ء ص 117۔118
31۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی ، اسلامی ریاست ، لاہور، 1974ء، ص 185
32۔ ایضاً، ص 142
33۔ تفسیر، جلد 5 قاہرہ، دارلمعارف، ص 343۔ 346
34۔امام ماوردی، الاحکام السلطانیہ، لاہور، تاریخ ندارد، ص 605
35۔ خلافتِ راشدہ کو آئیڈیل ریاست سمجھنا اور خلفائے راشدین کے طرزِ انتخاب کو دورِ حاضر کے جمہوری طرز انتخاب سے مقابلہ کرنا تاریخی ارتقا سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ساتویں صدی عیسوی میں مدینے میں طرز ِ حکومت کے جو تجربے کیے گئے وہ اس وقت کے معاشرتی حالات کے مطابق تھے مگر موجودہ دور کے معاشرتی حالات ان حالات سے بالکل مختلف ہیں لہذا خلافتِ راشدہ کے تجربوں کو دہرایا نہیں جا سکتا اور نہ وہ فی زمانہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔
36۔ مقالاتِ اقبال، ص 111
37۔ ایتھنز کی شہری ریاست میں سولن (640۔558 ق۔ م) نے جمہوری آئین وضع کیا تھا۔ ایتھنی ریاست کے دورِ عروج میں کل آبادی تین لاکھ پندرہ ہزار تھی۔ اس میں سے 43 ہزار شہریوں کو حق رائے دہی حاصل تھا۔ اقتدارِ اعلیٰ کی نمائندہ ایک اسمبلی تھی جس کا سال بہ سال انتخاب ہوتا تھا اور جس کا اجلاس سال میں چار بار ضرور ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ 500 نمائندوں کی ایک کونسل بھی ہوتی تھی۔ اس کا انتخاب بھی ہر سال ہوتا تھا اور کوئی شخص دوبارہ منتخب نہیں ہو سکتا تھا۔ قانون سازی اورنظم و نسق کی نگراں یہی کونسل تھی جو روز مرہ کے انتظامات کے لیے نو افراد کی کابینہ منتخب کرتی تھی۔ سپہ سالارِ افواج اور عدالت کے جج بھی ہر سال چنے جاتے تھے۔
38۔ ان کے نام یہ ہیں (1) کتاب الخراج ازامام ابو یوسف (797ء) پہلا حصہ (2) کتاب التاج (3) کتاب السلطان از ابن قطیبہ (828۔889ء) (4) الآراء مدینتہ الفاضلہ از فارابی (950ء)(5) عقد الفرید از عبدالربیہ (940ء) (6) المحاسن و المساوی از ابن بہیقی (7) احکام السلطانیہ از قاضی ماوردی ۔ (8) ادب الفرس و العرب از ابنِ مسکویہ (1030ء)۔ (9) قابوس نامہ از کیکاؤس ابنِ سکندر (1082ء)۔ (10) سیاست نامہ از نظام الملک (1018۔1092ء) (11) نصیحت الملوک از امام غزالی (1057۔ 1111ء)
39۔ منقول از
E.I.J. Rosenthal, political thought in Medieval Islam, Cambridge, 1962, p 45
40۔ نصیحت الملوک، ص 104
41۔ کتاب ارشاد، بحوالہ روز نتھال، ص 237
42۔ 28 مئی 1937ء
43۔Gunar Myrdal Asian Drama, London, 1968, vol 1, p. 248
44۔ پاک جمہوریت، 28 اکتوبر 1960۔
باب سوئم: سیکولراِزم
ملائیت
لاہور 13 اپریل 1981ء
مولانا محمد عبداللہ درخواستی ، امیر نظام علمائے پاکستان نے فرمایا کہ سیاسی رہنماؤں ، کارکنوں اور مولویوں کو چاہیے کہ ملک میں سیکولرازم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ وہ کل شام جامعہ مدینہ کریم پارک میں علما سے خطاب کررہے تھے 1 علم و حکمت کا درخت بہتوں کو شجرِ حیات سے گمراہ کردیتا ہے اور جہنم کے عذابوں کی تمہید ہوتا ہے۔ پادری یوناؤن ترا۔ (1221ء۔ 1274ء)
سیکولراِزم
جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ بیماریاں اُڑ کر لگتی ہیں جب کہ شرعی قوانین ان سے انکار کرتے ہیں تو ان کو ہمارا جواب ہے کہ وبائی امراض کا وجود تجربے، تحقیق، حواسِ خمسہ کی شہادتوں اور معتبر روایتوں سے ثابت ہے۔ وبا کی حقیقت اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب کوئی محقق یہ دیکھتا ہے کہ مریض کو چھونے والا خود اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جب کہ دور رہنے والا اس مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ وبائی مرض کپڑوں، برتنوں اور زیوروں کے ذریعے دوسروں کو لگتا ہے۔
(ابن خطیب غرناطوی، 1313ء۔ 1374ء)
کہتے ہیں کہ سقراط جب زہر کا پیالہ پی چکا تو اس کے شاگرد کریٹو نے پوچھا کہ اے استاد بتا کہ ہم تیری تجہیزو تکفین کن رسموں کے مطابق کریں۔ ” میری تجہیزو تکفین؟” سقراط ہنسا اورپھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ ” کریٹو! میں نے تم لوگوں کو تمام عمر سمجھایا کہ لفظوں کو ان کے صحیح معنی میں استعمال کیا کرو مگر معلوم ہوتا ہے کہ تمھیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کریٹو! یاد رکھو کے لفظوں کا غلط استعمال سب سےبڑا گناہ ہے۔”
ہمارے ملک میں ان دنوں سیکولرازم کی اصطلاح کے ساتھ یہی ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ ملاؤں کا تو ذکر ہی کیا اچھے خاصے پڑھے لکھے سیاسی لیڈر اور اخباروں کے ایڈیٹر حضرات بھی لوگوں کو سیکولرازم سے بدگمان کرنے کی غرض سے اس کے معنی و مفہوم کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں گویا سیکولرازم ایک عفریتی نظام ہے جس سے بے دینی، دہریت اور بد اخلاقی پھیلتی ہے اور فتنہ و فساد کے دروازے کھلتے ہیں لہذا سیکولر خیالات کا سدِ باب نہایت ضروری ہے ورنہ اسلام اور پاکسان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ آئیے اس جھوٹ کا جائزہ تاریخی سچائیوں کی روشنی میں لیں۔
سیکولر اور سیکولرازم خالص مغربی اصطلاحیں ہیں۔ لاطینی زبان میں ” سیکولم” Seculum کے لغوی معنی دنیا کے ہیں۔ قرونِ وسطیٰ میں رومن کیتھولک پادری دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک وہ پادری جو کلیسائی ضابطوں کے تحت خانقاہوں میں رہتے تھے۔ دوسرے وہ پادری جو عام شہریوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ کلیسا کی اصطلاح میں آخر الذکر کو ” سیکولر” پادری کہا جاتا تھا۔ وہ تما م ادارے بھی سیکو لر کہلاتے تھے جو کلیسا کے ماتحت نہ تھے اور وہ جائیداد بھی جس کو کلیسا فروخت کردیتا تھا۔ ” آج کل سیکولرازم سے مراد ریاستی سیاست یا نظم ونسق کی مذہب یا کلیسا سے علیحدگی ہے اور سیکولر تعلیم د ہ نظام ہے جس میں دینیات کو تعلیم سے الگ کردیا جاتا ہے۔” 2
انسائکلوپیڈیا امریکا نا میں سیکولرازم کی تشریح اور زیادہ وضاحت سے کی گئی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا امریکانا کے مطابق ” سیکولرازم ایک اخلاقی نظام ہے جو قدرتی اخلاق کے اصول پر مبنی ہے اور الہامی مذہب یا مابعد الطبیعات سے جدا ہے۔ اس کا پہلاکلیہ فکر کی آزادی ہے یعنی ہر شخص کو اپنے لیے کچھ سوچنے کا حق۔ 2۔ تمام فکری امور کے بارے میں اختلافِ رائے کا حق۔ 3۔ تمام بنیادی مسائل مثلاً خدا یا روح کی لافانیت وغیرہ پر بحث مباحثے کا حق۔ سیکولرازم یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ موجودہ زندگی کی خوبیوں کے علاوہ کوئی اور خوبی نہیں ہے۔ البتہ اس کا مقصد وہ مادی حالات پیدا کرنا ہے جن میں انسان کی محرومیاں اور افلاس نا ممکن ہو جائیں۔” 3
ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی انگلش اردو ڈکشنری کے مطابق سیکولرازم اس معاشرتی اور تعلیمی نظام کو کہتے ہیں جس کی اساس مذہب کے بجائے سائنس پر ہو اور جس میں ریاستی امور کی حد تک مذہب کی مداخلت کی گنجائش نہ ہو۔4
سیکولر خیالات بہت قدیم ہیں لیکن سیکو لر ازم کی اصطلاح جارج جیک ہولی اوک George J. Holyoake نامی ایک آزاد خیال انگریز نے 1840ء میں وضع کی۔ وہ شہر برمنگھم کے میکنکس انسٹی ٹیوٹ میں استاد تھا۔ برطانیہ کے مشہور خیالی سوشلسٹ رابرٹ اووین (1771ء۔1857ء) کے ہم نوا ہونے کے جرم میں بر طرف کردیا گیا تھا اور کل وقتی مبلغ بن گیا تھا۔ ان دنوں لندن سے آزاد خیالوں کا ایک رسالہ ” ندائے عقل” نکلتا ہے۔ 1841ء میں جب رسالے کے ایڈیٹر کو دینِ مسیح کی بے حرمتی کے جرمیں ایک سال قید اور سو پونڈ جرمانے کی سزا ہو گئی تو ہولی اوک کو رسالے کا ایڈیٹر مقرر کردیا گیا لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ہولی اوک کو بھی ایک تقریر کی پاداش میں چھ ماہ کی قید کی سزا بھگتنی پڑی۔ جیل سے نکلنے کے بعد آزاد خیالی کے حق میں مسلسل تقریریں کرتا اور رسالے لکھتا رہا۔ 1851ء میں اس نے لندن میں سینٹرل سیکولر سو سائٹی کے نام سے ایک انجمن قائم کی۔ ہولی اوک کا موقف یہ تھا کہ:
1۔ انسان کی سچی رہنما سائنس ہے ۔
2۔ اخلاق مذہب سے جدا اور پرانی حقیقت ہے۔
3۔ علم و ادراک کی واحد کسوٹی او ر سند عقل ہے۔
4۔ ہر شخص کو فکر اور تقریر کی آزادی ملنی چاہیے۔
5۔ ہم کو اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
سیکولر ازم کو معاشرتی نظام کے لیے درست سمجھنے سے دین دار بے دین اور خدا پرست دہریہ نہیں ہو جاتا لہذا سیکو لر ازم سے اسلام کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اور نہ اس سے پاکستان کی بقا و سالمیت پر کوئی ضرب پڑتی ہے بلکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ سیکو لر اصولوں ہی پر چل کر پاکستان ایک روشن خیال ، ترقی یافتہ اور خوش حال ملک بن سکتا ہے۔سیکولرازم کا مقصد معاشرے کی صحت مند سماجی اور اخلاقی قدروں کو پامال کرنا نہیں بلکہ سیکو لر ازم ایک ایسا فلفسہ حیات ہے جو خرد مندی اور شخصی آزادی کی تعلیم دیتا ہے اور تقلید و روایت پرستی کے بجائے عقل و علم کی اجتہادی قوتوں کی حوصلہ افزائی کرتاہے۔ چنانچہ سیکو لرازم کی تبلیغ کرنے والوں کی برابر یہی کوشش رہی ہے کہ انسان کے عمل و فکر کو توہمات کے جال سے نکالا جائے۔ یہ کوئی انوکھا فلسفہ نہیں ہے۔ ہمارے صوفیائے کرام بھی یہی کہتے تھے کہ سچائی کو خود تلاش کرو، خود پہچانو اور جو رشتہ بھی قائم کرو خواہ وہ خالق سے ہو مخلوق سے معرفت حق پر مبنی ہو نہ کہ انعام کے لالچ اور سزا کے خوف پر۔ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک روز وہ بصرے کی سڑک پر سے گزر رہی تھیں اس حال میں کہ ان کے ایک ہاتھ میں مشعل تھی اور دوسرے میں پانی کی صراحی۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو انھوں نے کہا کہ میں جنت کو آگ لگانے اور دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ مسلمان جزا اور سزا کی فکر سے آزاد ہو کر خدا سے بے لوث محبت کرنا سیکھیں۔
جو لوگ عقل و اجتہاد کی جگہ تقلید و اطاعت پر زور دیتے ہیں وہ خود مذہب کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ذرا سوچیے کہ اگر حضرت ابراہیمؑ نے روایت پرستی کا شیوہ اختیار کیا ہوتا، اپنے آبائی مذہب پر قائم رہتے اور اس کو عقلی دلائل سے رد نہ کرتے تو دینِ ابراہیمی کہاں ہوتا۔ غالب نے اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ
بامن میاویز اے پدر! فرزندِ آذر رانگر
ہر کس کہ شد صاحب نظر، دینِ بزرگان خوش نہ کرو
غالب تو خضر کے سے راہبر کی پیروی کو بھی لازم نہیں سمجھتا بلکہ ان کو اپنا ہم سفر خیال کرتا ہے۔
سیکولرازم کی بنیاد اس کلیے پر قائم ہے کہ ضمیر و فکر اور اظہارِ رائے کی آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے لہذا ہر فردِ بشر کو اس کی پوری پوری اجازت ہونی چاہیے کہ سچائی کا راستہ خود تلاش کرے اور زندگی کے تمام مسائل پر خواہ ان کا تعلق سیاسیات اور اقتصادیات سے ہو یا مذہب و اخلاق سے، فلسفہ و حکمت سے ہو یا ادب و فن سے ، اپنے خیالات کی بلا خوف و خطر ترویج کرے۔طاقت کے زور سے کسی کا منھ بند کرنا یا دھمکی اور دھونس سے کسی کو زبردستی اپنا ہم خیال بنانا حقوقِ انسانی کے منافی ہے اور اس بات کا اقرار بھی کہ بحث و مباحثے میں ہم اپنے حریف کی دلیلوں کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔
جبری زبان بندی کے نتائج بھی معاشرے کے حق میں بڑے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ ملک کی فضا میں گھٹن او ر اُمس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، قوم کی کمر جھک جاتی ہے اور اس کے سجدے بقول اقبال طویل ہو جاتے ہیں، خوف اتنا بڑھ جاتا ہے شاخِ گل کا سایہ بھی سانپ بن کر ڈرانے لگتا ہے، لوگ اقتدار کی خوشنودی ہی کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور سوچنا، سوال کرنا، شک کرنا یا انکار کرنا ( جو علم و معرفت کی یہلی شرط ہے) ترک کردیتے ہیں خوف سے بزدلی، بزدلی سے تابعداری اور تابعداری سے غلامانہ ذہنیت جنم لیتی ہے۔ جرات و بے باکی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، تلاش و جستجو اور تحقیق و تفتیش کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے تجربے کے بازو شل اور مشاہدے کی آنکھیں کو ر ہو جاتی ہیں، ایجاد و تخلیق کےسوتے سوکھ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایک ایسی نسل وجود میں آتی ہے جو ذہنی طور پر مفلوج اور عملی طورپر اپاہج ہوتی ہے۔ بھیڑوں کا یہ گلہ جو نہ خودبین ہو نہ جہاں بیں، بقا و ترقی کی جد و جہد میں ان قوموں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جو اپنی تخلیقی قوتوں میں اضافے کی مسلسل کوشش کرتی رہتی ہیں اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں سر گرداں رہتی ہیں۔
فکرو عمل کی قوانینِ قدرت سے ہم آہنگی کا نام سیکولرازم ہے اور اگر قوانینِ قدرت کی خلاف ورزی کی جائے تو انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ انسانی تخلیق کا ہر عمل چوں کہ قوانینِ قدرت کے مطابق ہوتا ہے لہذا شعر کہنا ہو یا تصویر بنانا، کھڈی پر کپڑا بننا ہو یا ہوائی جہاز اڑانا ہم اپنے کاموں کے دوران سیکولر انداز اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ہمارے عمل کی ذمہ داری ہم پر ہے اور اس میں کسی ماورائی طاقت کا دخل نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ کر قتل کے الزام سے ہر گز بچ نہیں سکتے کہ ہم کو خواب میں قتل کرنے کاحکم دیا گیا تھا۔ بیماریوں کا علاج اور حفظانِ صحت کے طور طریقے بھی سیکولر اصولوں ہی پر وضع ہوتے ہیں مگر پرانے زمانے میں انسان قوانینِ قدرت سے بہت کم واقف تھا لہذا مظاہر قدرت سے ڈرتا تھا۔ ان کی پوجا کرتا تھا اور ان کے لطف و کرم کا طالب رہتا تھا۔ کانسی کی تہذیب کے زمانے میں وادی نیل، وادی دجلہ و فرات اور وادی سندھ میں بڑی بڑی تہذیبیں ابھریں اور انسان نے اپنے آرام و راحت کے لیے بے شمار نئی نئی چیزیں بنائیں لیکن اس کا شعور ہنوز تجرباتی تھا۔ استدلالی نہ تھا۔ وہ اپنی ایجادوں اور دریافتوں سے کوئی سائنسی کلیہ یا نظریہ اخذ نہ کرسکا۔ اس کا عمل سیکو لر تھا لیکن اس کی سوچ سیکولر نہ تھی۔
مغرب میں سیکولر خیالات کی ابتدا آئیونا (مغربی ترکی) کے نیچری فلسفیوں سے ہوئی جو یونانی الاصل تھے۔ طالیس، انکسی ماندر، ہرقلاطیس اور دیمقراطیس وغیرہ مظاہر قدرت کی تشریح خود عناصر قدرت کے حوالے سے کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ کائنات کا اصل اصول پانی ہے، کسی نے کہا نہیں آگ ہے، کسی نے کہا ہوا ہے اور کسی نے کہا ایٹم ہے۔ ان میں بیش تر یونانی خداؤں کے قائل تھے لیکن دیناوی حقیقتوں کی تشریح وہ سیکولر انداز میں کرتے تھے۔ یونان کی شہری ریاستوں بالخصوص ایتھنز کا نظام ریاست بھی سیکولر تھا البتہ لوگ دیوتاؤں کی باقاعدہ پرستش بھی کرتے تھے۔
یونان کے زوال کے بعد جب مغربی سیاست کا مرکز روم منتقل ہو گیا تو نظم و نسق کے تقاضوں کے سبب اربابِ اختیار کو وہاں بھی سیکولر طرزِ عمل اختیار کرنا پڑا۔ ابتدا میں قانونی دستاویزیں روم کے پروہتوں کے قبضے میں رہتی تھیں۔ قوانین کی تشریح اور تاویل کا حق انہیں کو حاصل تھا اور قوانین سے متعلق مذہبی مراسم کی ادائیگی بھی انہیں کی اجارہ داری تھی لہذا پروہت جن کا تعلق امرا کے طبقے سے تھا اپنے ان وسیع اختیارات سے خوب فائدے اٹھاتے تھے۔ 451 ق۔م میں جب روم میں پروہتوں کی دراز وستیوں کے خلاف بغاوت ہوئی تو رومن سینٹ نے قوانین کو ” بارہ لوحوں” میں قلم بند کر کے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اور تب ” رومن لا” کا سیکولر دور شروع ہوا۔ ملکی قوانین سینیٹ بنانے لگی۔ تیسری صدی قبلِ مسیح میں پروہتوں کے بجائے وکیل عدالتوں میں پیش ہونے لگے تو امورِ ریاست میں پروہتوں کا اثر اور کم ہوگیا۔
پہلی صدی عیسوی میں رومی معاشرے میں ایک نیا مشرقی عنصر داخل ہوا جس نے یورپ والوں کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ عنصر عیسائی مذہب کا تھا۔ حضرتِ مسیحؑ کا حکم تھا کہ خدا کا حق خدا کو دو اور قیصرِ روم کا حق قیصرِ روم کو دو۔ ان کے شاگردوں نے پیغمبر خدا کی ہدایت پر عمل کیا مگر قیصر روم کو مسیحی تعلیمات کسی صورت گوارہ نہ تھیں چنانچہ پطرس اور پال نے جب روم میں تبلیغ شروع کی تو ان کو صلیب دے دی گئی۔ دوسرے کئی مبلغوں کا بھی یہی حشر ہوا اور عام عیسائیوں پر جو عموماًٍ غریب یا غلام ہوتے تھے ہولناک مظالم توڑے گئے۔ تقریباً تین سو سال تک یہی عالم رہا لیکن اس بیداد کے باوصف عیسائی مذہب کی مقبولیت بڑھتی رہی اور آخر کار شہنشاہ قسطنطین (274ء۔ 337ء) کو اعلان کرنا پڑا کہ ” عبادت کی آزادی سے کوئی شخص محروم نہیں کیا جائے گا اور ہر فردِ بشر کو اختیار ہوگا کہ الوہی امور کا تصفیہ اپنی مرضی سے کرے” مگر 313ء میں جب قسطنطین خود عیسائی ہو گیا تو غیر مسیحی آبادی پر ستم ڈھایا جانے لگا۔ 346ء میں تمام غیر مسیحی عبادت گاہیں بند کر دی گئیں۔ پرانے رومن دیوتاؤں کو قربانی پیش کرنے کی سزا موت قرار پائی اور عبادت گاہوں کی جائیدادیں ضبط کر کے کلیسا کے حوالے کردی گئیں۔ جو کل تک مظلوم و مفلس تھے دفعتاً صاحبِ جاہ و چشم بن گئے۔ روم کلیسا کا صدر مقام قرار پایا کیوں کہ پطرس اور پال کی ہڈیاں وہیں دفن تھیں۔ پاپائے روم پطرس کا جانشین اور عیسائیوں کا روحانی پیشوا تسلیم کر لیا گیا۔ کلیسا کا دور اقتدار شروع ہو گیا۔ شہنشاہ قسطنطین نے اس سے پہلے ہی شمالی یورپ کی وحشی قوموں کے حملے سے بچنے کی غرض سے اپنا دارالسلطنت روم سے قسطنطنیہ (استنبول) منتقل کردیا تھا جو یقیناً زیادہ مرکزی اور محفوظ جگہ تھی۔ اس کی موت کے بعد تاج و تخت کے لیے جھگڑے شروع ہوگئے اور سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ایک قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت اور دوسری مغربی سلطنت جس کا صدر مقام روم تھا۔
مگر مغربی سلطنتِ روما کے قدم ابھی جمے نہ تھے کہ مشرقی یورپ سے گوتھ اور ہن قوموں نے بڑے پیمانے پر ترکِ وطن کر کے مغربی یورپ پر یلغار کردی۔ 410ء میں انھوں نے روم کو بھی تاخت و تاراج کردیا۔ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ پچاس ساٹھ سال تک جاری رہا۔ اس اثنا میں گوتھ قوم نے اسپین ، فرانس اور اٹلی کے کئی علاقوں میں اپنی ریاستیں بھی قائم کرلیں اور شہنشاہ روم گوتھ سرداروں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن گئے۔ 476ء میں ایک سردار نے آخری شہنشاہ آگسٹولس کو تخت سے اُتار دیا اور خود حکومت کرنے لگا۔ مغربی سلطنتِ رومہ ہمیشہ کےلیے ختم ہوگئی۔
ان وحشی قوموں نے کلاسیکی روم کا ہزار سالہ تہذیبی سرمایہ نیست و نابود کردیا اور کچھ عرصے بعد وہاں قدیم علم و ادب کے آثار بھی باقی نہ رہے۔ یورپ بربربیت کے اندھیرے میں ڈوب گیا۔
البتہ سلطنتِ روما کا زوال رومن کلیسا کے حق میں بڑی نعمت ثابت ہوا۔ قسطنطنیہ کی مانند اگر روم میں بھی کوئی مضبوط مرکزی حکومت ہوتی تو رومن کلیسا کی حیثیت وہاں وہی ہوتی جو بازنطینی سلطنت میں پادریوں کی تھی۔ وہ شہنشاہ کی اطاعت پر مجبور ہوتے اور کبھی دعوے کرنے کی جرات نہ کرتے کہ کلیسا ریاست سے ارفع و اعلیٰ ادارہ ہے۔ روم میں شہنشاہیت کے خاتمے اور وحشی قوموں کے حملوں کی وجہ سے یورپی معاشرے میں جو خلا پیدا ہوا اس سے کلیسا کو اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے میں بڑی مدد ملی۔ پادریوں نے اطالوی تہذیب کی بچی کچھی نشانیوں کو وحشی گوتھوں کی دست برد سے بچایا اور اس میں کئی شبہ نہیں کہ ” تاریکی اور خلفشار کے اس دور میں پطرس کے جانشین مغربی یورپ کے طوفانی سمندر میں مینارۂ نور ثابت ہوئے”5 یہ پادری لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ایسٹر اور دوسرے مذہبی تیوہاروں کے دن تاریخ کا حساب کر سکتے تھے۔ پیدائش، شادی بیاہ اور موت کی رسمیں ادا کرتے تھے اور حکام کے رُوبرو مصیبت زدوں کی داد فریاد پیش کر سکتے تھے۔ غرضیکہ عہدِ تاریک میں عوام کا واحد سہارااگر کوئی تھا تو یہی پادری تھے۔ کلیسا نے قرونِ وسطیٰ میں عقیدت مندوں کے دلوں میں اگر گھر کر لیا اور اس کا اثر و اقتدار بڑھا تو اس کے معقول اسباب تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کلیسا نے اس صورت حال سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور آگے چل کر معاشرتی ترقی کی راہ کا روڑا بن گیا۔
یورپ کے نئے حاکموں نے بھی کلیسا سے کوئی تعرض نہ کیا بلکہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی کیوں کہ پادریوں کے تعاون کے بغیر وہ حکومت نہیں کرسکتے تھے۔د وسری طرف کلیسا نے بھی وفاداری ہی میں عافیت سمجھی ( مذہبی پیشواؤں کو اقتدار سے سمجھوتہ کرنے میں عموماً زیادہ دیر نہیں لگتی خواہ اقتدار کسی کے قبضے میں ہو) رومتہ الکبریٰ کے دور میں حکام اور امرا اور رؤسا پادریوں کو بالکل خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اس کے برعکس نئے حاکم جو اُجڈ اور توہم پرست تھے پادریوں کی باتیں بڑی عقیدت سے سنتے تھے۔
مغربی مورخین قرونِ وسطیٰ کو عہدِ تاریک سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک پانچویں صدی اور پندھویں صدی عیسوی کا درمیانی زمانہ معاشرتی اور تہذیبی سرگرمیوں کے لحاظ سے انتہائی پستی کا زمانہ تھا لیکن معاشرتی ادوار کا سن و سال متعین نہیں کیا جا سکتا، معاشرتی دور کوئی تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ارتقائی عمل ہے جس کی ابتدا یا انتہا کی نشان دہی ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرونِ وسطیٰ کی شام آہستہ آہستہ ہوئی اور نئی زندگی کی پو آہستہ آہستہ پھٹی۔ چنانچہ یورپ میں سیکولر اداروں اور فکروں کی نشو و نما تیرھویں صدی عیسوی میں شروع ہو گئی تھی۔ یہ بڑی تاریخ ساز صدی تھی۔ اسی صدی میں اٹلی میں ابھرتے ہوئے سرمایہ داری نظام نے طاقت پکڑی اور سیکولر افکار مسلم اسپین اور سسلی کی راہ سے یورپ میں داخل ہوئے مگر تاریخ کی ستم ظریفی دیکھئے کہ جس مذہب کے عظیم دانشوروں ،ا لکندی، ابوبکررازی، بو علی سینا، ابن ہیثم ، خوارزمی، البیرونی اور ابنِ رشد نے مغرب کو سیکولر خیالات اور نظریات کی تعلیم دی اسی مذہب کے نام لیوا آج سیکولرازم پر اسلام دشمنی کی تہمت لگا رہے ہیں۔
انگریز مورخ پروفیسر فشر کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ سیکولر خیالات اٹلی میں شروع ہوئے جو کلیسائیت کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ تیرھویں صدی کی فکری تحریکوں پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ:
” یہ اُلٹی بات ہے کہ اٹلی جو کلیسا کا مرکز تھا پورے تاریخی دو ر میں مغربی ملکوں میں سب سے زیادہ سیکولر تھا”۔6
لیکن یہ ہر گز اُلٹی بات نہیں بلکہ سیدھی بات ہے اس لیے کہ جنگ صلیبیہ کے دوران صنعت و حرفت اور تجارت نے دوسرے تمام مغربی ملکوں سے پہلے اٹلی میں ترقی کی۔ صلیبی جنگوں کا بظاہر مقصد عیسائیوں کے مقدس شہروں ، یروشلم، بیتِ لحم وغیرہ کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا تھا لیکن اصل مقصد مشرقی بحرِ روم کی تجارت پر اور تجارتی راستوں پر قبضہ کرنا تھا۔ صلیبی سورما فلسطین و شام کو تو آزاد نہ کروا سکے البتہ مشرقی بحر روم کی تجارت پر اٹلی کی ری پبلکن ریاستوں کا غلبہ ہو گیا۔ یہ ریاستیں بالخصوص وینس، میلان، فلورنس اور جینوا شہری ریاستیں تھیں۔ ان کا دارو مدار تجارت اور صنعت و حرفت پر تھا۔ کلیسا کا اثر ان علاقوں میں برائے نام تھا بلکہ کلیسا سے اکثر ان کی ٹکر ہوتی رہتی تھی۔ کلیسا چوں کہ ملک کا سب سے بڑا زمین دار تھا لہذا اس کا مفاد فیوڈلزم سے وابستہ تھا جن کہ ری پبلکن ریاستیں سرمایہ داری نظام کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں۔
سیکو لر درس گاہوں کی ابتدا اگر اٹلی میں ہوئی تو یہ بھی کوئی اتفاقی امر نہ تھا بلکہ صنعت و تجارت کی ترقی کاتاریخی تقاضا تھا۔ اٹلی کے بینکروں، جہاز سازوں اور ریشمی، اُونی ملوں کے مالکوں کو تربیت یافتہ اور ہنر مند کارکنوں کی ضرورت پڑتی تھی مگر تعلیمی ادارے کلیسا کے ماتحت تھے جو فنی تعلیم کے سخت خلاف تھا لہذا سرمایہ دار طبقے کو مجبوراً سیکولر درس گاہیں قائم کرنی پڑیں۔ کلیسا نے اس اقدام کی شدت سے مخالفت کی مگر اس کی ایک نہ چلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اٹلی کے قریب قریب ہر بڑے شہر میں سیکولر یونیورسٹیاں کھل گئیں۔ ” ان یونیورسٹیوں کو سیکولر اداروں نے سیکولر تعلیمات کی غرض سے قائم کیا تھا۔” 7 لہذا ان درس گاہوں کا ماحول قدرتی طورپر کلیسا کے خلاف تھا۔ بولو نیا یونیورسٹی میں تو دینیات کا شعبہ بھی نہ تھا۔ پیڈوایونیورسٹی فکرِ جدید کا سب سےبڑا مرکز تھی۔ فلورنس میں چھ ٹیکنیکل اسکول قائم تھے جن میں طلبا کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی۔ سالر مو یونیورسٹی طبی تعلیم کے لیے پورے یورپ میں مشہور تھی۔ ان یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نوجوانوں کی معاشرتی قدریں سیکولر ہوتی تھیں اور ان کا زاویہ نظر بھی کلیسا کے زاویہ نظر سے مختلف تھا۔
دوسرا اہم رحجان جس سے سیکولر عناصر کو تقویت ملی شرعی قوانین کی جگہ سول قوانین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت تھی۔ اس رحجان کو بھی اٹلی کی جمہوری حکومتوں ہی نے سہارا دیا۔ چوں کہ کلیسا کے وضع کردہ فرسودہ قوانین نئی زندگی کے تقاضوں کو پورا نہین کر سکتے تھے لہذا تیرھویں صدی میں روم، ملان، ویرونا اور بولونیا ہر جگہ لا کالج قائم ہو گئے ۔ ان درس گاہوں میں قدیم رومن لا کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ تعلیم کلیسا کے حق میں بڑی مہلک ثابت ہوئی۔ اس کے سبب سے عدالتوں کا کردار بدل گیا اور پادری سینٹ برنارڈ کو فریاد کرنی پڑی کہ ” یورپ کی عدالتیں جسٹسن کے قوانین سے گونج رہی ہیں، خدائی قوانین کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی ۔ ” اور پروفیسر فشر کو جو کلیسا کا حامی ہے اعتراف کرنا پڑا کہ ” تیرھویں صدی میں سیاست اور معاشرے پر جتنے فکری اثرات پڑے ان میں رومن قانون کا اثر سب سے قوی تھا۔ سلطنت اور کلیسا کی کشمکش میں سول قانون کی تعلیم پانے والوں نے کلیسا کے بجائے سلطنت کاساتھ دیا۔”
اسی زمانے میں فرانس، بیلجیم اور برطانیہ میں بھی تجارت اور صنعت و حرفت کو فروغ ہوا۔ مارسلز، پیرس، ایمسٹرڈیم، ہمبرگ اور لندن میں صنعتی اور تجارتی اداروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ سیکولر درس گاہیں قائم ہوئیں اور پرانی یونیورسٹیوں میں بھی جو کلیسا کے زیر اثر تھیں سیکولر خیالات کا چرچا شروع ہوگیا۔ برطانیہ میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں پر ہنوز کلیسا کا غلبہ تھا لہذا سول قانون کی تعلیم کے لیے لندن کے کاروباری حلقوں نے اپنے شہر میں جداگانہ لا کالج قائم کیے جو آج تک INN ” سرائے” کہلاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے بیرسٹر وہیں سے سند لیتے ہیں۔
زندگی کی اس طرزِ نو میں، جس کی داغ بیل سرمایہ داری نظام نے ڈالی فکرِ کہن کا پیوند نہیں لگ سکتا تھا ۔ مگر یورپ کا معاشرہ ہنوز فکرِنو کی تخلیق کا اہل نہ تھا۔ اس خلا کو اسپین اور سسلی کے عرب مفکرین نے پر کیا ۔ یورپ میں ذہنی انقلاب لانے کا سہرا انہیں کے سر ہے۔ چنانچہ پروفیسر فشر کے سے متعصب مورخ کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ ” تیرھویں صدی میں روشنی کی جو کرنیں یورپ میں پہنچیں وہ یونان سے نہیں بلکہ اسپین کے عربوں کے ذریعے آئیں” اور پروفیسر فلپ حتی لکھتا ہے کہ:
” یورپ کے قرونِ وسطیٰ کی فکری تاریخ میں مسلم اسپین نے انتہائی درخشاں ابواب تحریر کیے۔ آٹھویں اور تیرھویں صدی کے دوران عربی بولنے والے ساری دنیا میں تہذیب و تمدن کے مشعل بردار تھے۔ مزید برآں انہیں کی کوششوں سے قدیم سائنس اور فلسفے کی بازیابی ہوئی۔ انہوں نے اس علم میں اضافہ کیا اور اس کو دوسروں تک اس طرح پہنچایا کہ مغرب نشاۃِ ثانیہ سے آشنا ہوا۔ ان کاموں میں ہسپانوی عربوں کا بڑا حصہ ہے۔انہوں نے یونانی فلسفے کو مغرب میں منتقل کیا۔ مغربی یورپ میں نئے خیالات کا یہ بہاؤ بالخصوص فلسفیانہ خیالات کا یہ زبردست بہاؤ عہدِ تاریک کے اختتام کی ابتدا کا موجب بنا” 8
حقیقت یہ ہے کہ علم و حکمت کا کارواں بڑی پر پیچ راہوں سے گزرا ہے۔ یونانی فکرو فن کا اثاثہ پہلے بطلیموس فرماں رواؤں کے عہد میں (تیسری صدی قبلِ مسیح) اسکندریہ منتقل ہوا۔ اس خزانے سے شام و عراق کے یہودی اور عیسائی علما نے فیض پایا۔ تب عباسیوں کے زمانے میں یونانی تصنیفات اور خلاصوں کے ترجمے عربی میں ہوئے۔ ان ترجموں سے مسلمان حکما اور اطبا نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ عباسیوں کے زوال کے بعد علم و حکمت کا یہ سرمایہ ہسپانوی عربوں کو ورثے میں ملا۔ انہوں نے اس دولت کو محفوظ رکھنے پر اکتفا نہ کی بلکہ اپنی تحقیقی اور تخلیقی کاوشوں سے اس میں بیش بہا اضافے کیے۔ وہ خزانے کے سانپ بھی نہ بنے بلکہ انہوں نے اہلِ مغرب کو اس دولت سے مستفید ہونے کے مواقعے فراہم کیے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے مغرب کی درس گاہیں عربی تصنیفات کے لاطینی ترجموں کی روشنی سے منور ہوگئیں۔ سچ یہ ہے کہ یورپ میں سیکولر خیالات کو فروغ دینے میں عرب مفکرین نے بڑا تاریخی کردار ادا کیا ہے۔
جس طرح نویں صدی عیسوی یونانی، سریانی اور سنسکرت تصنیفات کے عربی ترجموں کی صدی تھی اسی طرح بارھویں اور تیرھویں صدی (1125ء۔1280ء) کو عربی سے لاطینی میں ترجمے کا زمانہ کہتے ہیں۔ اسپین میں ان دنوں یوں تو بے شمار اہل قلم موجود تھے جو عربی ، لاطینی اور فرانسیسی زبانوں پر پورا عبور رکھتے تھے لیکن ترجمہ کرنے والوں میں سر فہرست نام اطالوی عالم جرارڈ آف کری مونا (1114ء۔ 1178ء) کا ہے۔ علم کی پیاس اس کو طولید ولائی اور پھر وہ ہیں کا ہو رہا۔ جرارڈ نے اسّی کتابیں عربی سے لاطینی میں منتقل کیں۔ ان میں بطلیموس کی المجیط، خوارزمی کی حساب الجبرو المقابلہ ، بوعلی سینا کی قانون الطب (جو مغربی یونیورسٹیوں میں صدیوں تک داخل نصاب رہی) حکیم ابوبکر رازی کی کتابِ سرالاسرار (جو ڈھائی سو سال تک کیمسٹری کی سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی رہی) اور جابرابنِ افلاح کی کتاب الحیات قابلِ ذکر ہیں۔
ان کے علاوہ الجاخط کی کتاب الحیوان ، ابوبکررازی کی کتاب الطب المنصوری (جو دس جلدون میں تھی) خوارزمی اور البطانی کی کتاب زج، ابن بیطار اورابن ماجہ کی تصنیفات اور الحادی کی کتاب جو یونانی ، ایرانی اور ہندی طب کی قاموس تھی لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں۔ بعض عرب حکما براہِ راست لاطینی زبان میں لکھتے تھے مثلاً ابو جعفر احمد بن محمد غفیقی جو قرطبہ کا مشہور طبیب تھا۔ اس نے الادویہ مفردہ، عربی، بربر اور لاطینی تینوں زبانوں میں لکھی۔ اس کتاب کے سلسلے میں غفیقی نے اسپین اور افریقہ کے دورے کیے اور آٹھ سو سے زیادہ مفردات کے نام اور ان کے خواص اکٹھا کیے۔ یہ سب حکما جن کا ہم نے ذکر کیا ہے پیشے کے اعتبار سے طبیب تھے یعنی اپنی عہد کے سائنس داں جبھی تو پروفیسر لانگے مشہور جرمن مفکر ہمبولٹ کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ “عربوں کو طبیعاتی سائنسوں کا حقیقی بانی سمجھنا چاہیے۔”
قرونِ وسطیٰ کے جن مسلمان حکما نے مغربی فکر کو سب سے زیادہ متاثر کیا ان میں ابو بکر رازی (وفات 925ء) اور ابنِ رشد (1126ء۔1198ء) کے نام سر فہرست ہیں۔ رازی رے (تہران ) کا رہنے والا تھا مگر بغداد منتقل ہو گیا تھا۔ وہ نہایت آزاد خیال اور روشن فکر سائنس دان تھا۔ البیرونی اس کی 56 تصنیفات کا ذکر کرتا ہے لیکن اس کی کتابوں کی تعداد سو سے بھی زیادہ ہے (33 نیچرل سائنس پر، 22 کیمسٹری پر، 17 فلسفے پر، 14 مذہبیات پر، 10 ریاضی پر، 8 منطق پر، 6 مابعد الطبیعات پر اور 10 متفرقات ) رازی کی تصنیفات پہلے جرارڈ نے لاطینی میں ترجمہ کیں پھر بادشاہ چارلس آف انجو کے حکم سے تیرھویں صدی میں ترجمہ ہوئیں۔ یورپ میں اس کا نام Rhaze تھا۔ وہ اکثریتِ مطالعہ کی وجہ سے آخری عمر میں اندھا ہوگیا تھا۔
رازی اسلاف پرستی کے سخت خلاف ہے۔ وہ منقولات کی حاکمیت کو نہیں تسلیم کرتا بلکہ عقل اور تجربے کو علم کا واحد ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کی سوچ کا انداز عوامی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عام لوگ بھی اپنے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سائنسی سچائیوں کے ادراک کے اہل ہیں۔ اس کا قول تھا کہ ہم کوفلسفے اور مذہب دونوں پر تنقید کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ وہ معجزوں کا منکر تھا کیوں کہ معجزے قانونِ قدرت کی نفی کرتے ہیں اور خلافِ عقل ہیں۔ وہ مذاہب کی صداقت کا بھی چنداں قائل نہیں کیوں کہ مذاہب عموماً حقیقتوں کو چھپاتے ہیں اور لوگوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ وہ معاشرے کے بارے میں افلاطون کی کتاب تماؤس کے ارتقائی تصور سے اتفاق کرتا ہے اور اقتصادی پہلو کو اہمیت دیتے ہوئے تقسیمِ کار کی افادیت پر زور دیتا ہے۔
رازی ارسطو کا پیرو نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ارسطو سے بڑا مفکر سمجھتا ہے۔ وہ ارسطو کی ” طبیعات” کو رد کرتا ہے اور دیمقراطیس اور ایپی قورس کے ایٹمی فلسفے کے حق میں دلیلیں دیتا ہے۔ اس کے خیال میں تمام اجسام مادی ایٹموں پر مشتمل ہیں اور خلا میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ارسطو کے برعکس وہ خلا کے وجود بالذات کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کی رائے میں پانچ قوتیں ابدی اور لافانی ہیں، خدا، روح، مادہ، زبان و مکان۔ وہ کہتا تھا کہ سائنس میں حرف آخر کوئی نہیں بلکہ علوم نسلاً بعد نسل ترقی کرتے رہتے ہیں لہذا انسان کو لازم ہے کہ اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھے اور منقولات کے بجائے حقیقی واقعات پر بھروسہ کرے۔9
طبیبِ توابنِ رشد بھی تھا لیکن یورپ میں اس کی شہرت کی وجہ فلسفہ تھا بالخصوص ارسطو کی شرحیں۔ ” ابن رشدیت بارھویں صدی سے سولھویں صدی تک یورپ میں سب سے غالب مدرسہ فکر تھا حالاں کہ عیسائی پادری اس کے سخت خلاف تھے۔ ” ابنِ رشد کی تعلیمات کا لب لباب یہ تھا کہ (1) کائنات اور مادہ ابدی اور لافانی ہے (2) خدا دنیاوی امور میں مداخلت نہیں کرتا (3) عقل لافانی ہے اور علم کا ذریعہ ہے۔
ارسطو کی تصانیف بالخصوص ” طبیعات” اور ” مابعد الطبیعیات” پر ابنِ رشد کی شرحیں پیرس پہنچیں تو کلیسائی عقاید کے ایوان میں ہلچل ملچل مچ گئی۔ معلم اور منعلم دونوں مسیحی عقیدۂ تخلیق، معجزات اور روح کی لافانیت پر علانیہ اعتراض کرنے لگے۔ حالات اتنے تشویشناک ہو گئے کہ 1210ء میں پیرس کی مجلسِ کلیسا نے ارسطو کی تعلیمات بالخصوص ابنِ رشد کی شرحوں کی اشاعت ممنوع قرار دے دی مگر کسی نے پرواہ کی لہذا 1215ء میں پوپ نے پوری عیسائی دنیا میں ان کتابوں پر پابندی لگا دی۔ پابندیوں کی وجہ سے ابنِ رشد کی مقبولیت اور بڑھ گئی۔ پوپ اسکندر چہارم نے رشدیت کےابطال کے لیے پادری البرٹس مغنوس سے ایک کتاب لکھوائی مگر وہ بھی قریب قریب ہر صفحے پر بو علی سینا کا اقتباس پیش کرتا ہے اور مسلمان مفکرین کے حوالے دیتا ہے۔ 1269ء میں ابنِ رشد سے منسوب تیرہ مقولوں کی تعلیم مذہب کے خلاف قرار پائی ان میں سے بعض یہ ہیں: سب انسانوں کے دماغ کی ساخت یکساں ہے، دینا لافانی ہے، آدم کی تخلیق افسانہ ہے، انسان اپنی مرضی میں آزاد ہے اور اپنی ضرورتوں سے مجبور، خدا کو روزمرہ کے واقعات کا علم نہیں ہوتا اور انسان کے اعمال میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ مگر ابنِ رشد کی مقبولیت کم نہ ہوئی۔ تب 1277ء میں ابنِ رشد کے 219 مقولوں کے خلاف فتویٰ صادر ہوا مثلاً تخلیق محال ہے، مردے کا جسم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، قیامت کا اعتقاد فلسفیوں کو زیب نہیں دیتا، فقہائے مذہب کی باتیں قصے کہانیاں ہیں، دینیات سے ہمارے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دینِ مسیحی حصول علم میں حارج ہے۔ مسرت اسی دینا میں حاصل ہو سکتی ہے نہ کہ آخرت میں۔
فرانس میں رُشدیت کا سب سے بڑا علم بردار پیرس یونیورسٹی کا پروفیسر سیگر (1235ء۔1271ء) تھا۔ اس پر 1277ء میں مذہبی عدالت میں مقدمہ چلا اور عمر قید کی سزا ملی۔ اسیری کے دن اس نے روم میں گزارے اوروہیں قتل ہوا۔ ان سختیوں کے باوجود ابنِ رشد کے خیالات ذہنوں کو متاثر کرتے رہے یہاں تک کہ ول ڈیورنت کے بقول ” تیرھویں صدی کے وسط میں ابن رشدیت تعلیم یافتہ طبقے کا فیشن بن گئی 10 اور ہزاروں افراد ابن رشد کے اس خیال سے اتفاق کرنے لگے کہ قوانینِ قدرت کے عمل میں خدا بالکل مداخلت نہیں کرتا، کائنات لافانی ہے اور جنت دوزخ عوام کو بہلانے کے بہانے ہیں۔
معتزلہ کے زیر اثر فرانس میں، ایسے مفکر بھی پیدا ہونے لگے جو کہتے تھے کہ خدا نے کائنات کی تخلیق کے بعد نظامِ کائنات کو قوانینِ قدرت کے سپرد کردیا ہے لہذا معجزہ محال ہے کیوں کہ معجزوں سے قوانیںِ قدرت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ دعاؤں، تعویذوں سے عناصر قدرت کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ التجاؤں سے نہ طوفان کو روکا جا سکتا ہے نہ بارش لائی جا سکتی ہے اور نہ بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بناتات اور حیوانات کی نئی قسمیں عملِ تخلیق کا کرشمہ نہیں بلکہ قدرتی ارتقا کا نتیجہ ہیں اور یہ عقیدہ کہ قیامت کے دن مردے جی اٹھیں گے درست نہیں کوں کہ روح اور جسم دونوں فانی ہیں۔ اس کےسا تھ قدیم یونانی فلسفی ایپی قورس (341۔270 ق۔ م ) اور اس کے روحانی شاگرد لوکری شیش (99۔ 55 ق۔م)کا ایٹمی فلسفہ مقبول ہونے لگا اور یہ خیال عام ہوا کہ حقیقی دنیا یہی ہے۔ آخرت محض افسانہ ہے۔
یورپ میں سائنسی تجربوں کا دور عربی تصانیف کے لاطینی ترجموں کے بعد شروع ہوا۔ اس دور کے سائنس دانوں میں سب سے ممتاز روجر بیکن (1214ء۔ 1294ء) ہے تحصیلِ علم کے شوق میں وہ آکسفورڈ سے فرانس ، اٹلی اور غالباً اسپین بھی گیا۔ وہیں وہ مسلمان سائنس دانوں کے خیالات سےس واقف ہوا۔ وہ اسلامی سائنس اور فلسفے کے احسانات کا اعتراف اپنی کتابوں میں بار بار کرتا ہے۔ روجر بیکن کے نزدیک علم و آگہی کا واحد ذریعہ تجربہ ہے۔ ” جو شخص مظاہر قدرت کی سچائیوں تک بلا شک و شبہ پہنچنا چاہتا ہو اس کو لازم ہے کہ تجربوں پر وقت صرف کرے کیوں کہ نیچری سائنس میں تجربہ ہی واحد ثبوت فراہم کرتا ہے”۔آکسفورڈ واپس جا کر اس انے ابنِ ہیثم کی بصریات پر تجربے شروع کیے تو کلیسا کی طرف سے اس کی باقاعدہ نگرانی ہونے لگی اور پادری یوناون ترا(1221ء۔1274ء) نے دھمکی دی کہ ” علم و حکمت کا درخت بہتوں کو شجرِ حیات سے گمراہ کردیتا ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کی تمہید ہوتا ہے۔” اس جرم کی پاداش میں کہ “تمھاری تحریروں میں عجیب و غریب خیالات کا اظہار ہوتا ہے” روجر بیکن کو مذہبی عدالت کے حکم سے قید کردیا گیا اور وہ پندرہ سال بعد رہا ہوا ۔
چودھویں صدی میں قومی ریاستوں کے قائم ہونے سے سیکولر خیالات خوب پھلے پھولے۔ قومی ریاستوں کو کلیسا کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے جن دلیلوں کی ضرورت تھی وہ سیکولر مفکر ہی فراہم کر سکتے تھے۔ مثلاً پیڈو وا یونیورسٹی کے استاد مارسی لیو نے اٹلی کی شہری ریاستوں کو نمونہ بنا کر 1334ء میں سیکو لر ریاستوں کا ایک مبسوط نظریہ پیش کیا۔ اس نے شرعی قوانین اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا کہ ” شہریوں کے حقوق ان کے عقاید سے متعین نہیں ہوتے لہذا کسی شخص کو اس کےمذہب کی بنا پر سزا نہیں ملنی چاہیے۔ ” کلیسا کی قائم کردہ مذہبی عدالتوں پر یہ کھلا حملہ تھا۔
کلیسا کا زوال اب دورنہیں تھا۔ چنانچہ جلد ہی ایسی تحریکیں اٹھیں اور پے درپے ایسے اہم واقعات پیش آئے جو سیکولر خیالات کے حق میں بے حد سازگار ثابت ہوئے: یورپ میں نشاۃ ثانیہ کا ظہور، مارٹن لوتھر، کالون اور زونیگلی وغیرہ کی پوپ کے خلاف بغاوتیں، برطانیہ میں ہنری ہشتم کا رومن کلیسا سے تصادم، سائنسی ایجادوں میں اضافہ، صنعت حرفت کا بڑے پیمانے پر فروغ ، امریکہ اورہندوستان کی دریافت اور اس کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت و صنعت میں اضافہ، برطانیہ میں خانہ جنگی اور جمہوریت پسندوں کے ہاتھوں بادشاہ چارلس اول کا قتل، اُلوہی استحقاقِ ملوکیت کے نظریے سے عام بیزاری اور پارلیمانی نظام سے وابستگی غرضیکہ معاشرتی اور سیاسی شعبوں میں سیکولر میلان عام ہوگیا۔ سترھویں صدی میں جو عقلیت کا عہد کہلاتا ہے سیکولر رحجانات کو مزید تقویت ملی۔ اسی بنا پر پروفیسر آرنلڈ ٹوائن بی نے لکھا ہے کہ ” سترھویں صدی مغربی زندگی پر سیکولر ازم کی بالادستی کی صدی ہے۔ سیکولر ازم ہی کے طفیل مغربی معاشرے میں معاشی مفاد نے اور تحقیق و تفتیش کے دائرے میں سائنس نے مذہب کی جگہ لے لی۔”11
اٹھارویں صدی یورپ میں صنعتی انقلاب ، سیاسی انقلاب اور روشن خیالی کے عروج کی صدی تھی۔ والتیر، روسو، مان تس کیو، اولباخ، ایلواتیس، دیدرو، کانٹ بے شمار ایسے مفکر پیدا ہوئے جنھوں نے معاشرتی اقدارو افکار کا رخ ہی بدل دیا اور جب عوام کی انقلابی جدو جہد (امریکہ اور فرانس میں ) شروع ہوئی تو سیکولر خیالات نے عملی پیراہن پہن لیا۔
امریکی جنگِ آزادی کی قیادت وہاں کے صنعت کارون اور تاجروں نے کی تھی۔ ان طبقوں پر اور ان کے فکری نمائندوں پر جیمس میڈیسن، تھامس جیفر سن، ٹام پین اور بنجامن فرینکلین کے علاوہ برطانوی سیاسی مفکر جان لاک اور فرانسیسی خرد افروزوں کا گہرا اثر تھا۔ انہوں نے امریکی ری پبلک کی بنیاد سیکولر اصولوں پر رکھی۔ چنانچہ امریکہ کا نیا آئین جو 1789ء میں منظور ہوا خالص سیکولر آئین تھا۔ یہ آئین ہنوز رائج ہے۔ اس کے مطابق اقتدارِ اعلیٰ کا سرچشمہ ملک کے باشندے ہیں۔ آئین کی دفعہ چھ کے مطابق ریاست کے کسی عہدے کے لیے مذہب کی کوئی شرط نہیں۔ آئین کی سیکولر نوعیت کی مزید تشریح کی غرض سے صدر میڈیسن کی تحریک پر کانگریس نے 1793ء میں آئین میں پہلی ترمیم منظور کی جس میں طے پایا کہ ” کانگریس مذہب کے قیام یا مذہب کی آزادی پر پابندی کے سلسلے میں کوئی قانون پاس نہیں کرے گی۔” صدر جیفرسن نے اس ترمیم کی وضاحتت کرتے ہوئے کہا کہ ” امریکی قوم کے اس فیصلے کو میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مقنّنہ مذہب کے قیام یا مذہبی رسوم کی ادائیگی کی ممانعت کے بارے میں کوئی قانون وضع نہیں کرے گی۔ اس طرح انہوں نے ریاست اور کلیسا کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔”
تاریخی اعتبار سے امریکہ عہدِ جدید کی پہلی سیکولر ریاست ہے مگر جس سماجی انقلاب کی وجہ سے سیکولر اداروں اور فکروں کے اثرات یورپ اور ایشیا میں نمایاں ہوئے وہ فرانس کا عظیم انقلاب تھا۔ اس کے باعث یورپ میں ملوکیت ، فیوڈل ازم اور کلیسا کی بالا دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور دنیا سرمایہ داری نظام کے عہد میں داخل ہو گئی۔
سرمایہ داری نظام ہر اعتبار سے جاگیری نظام کی ضد ہوتا ہے۔ یہ تضاد یورپ میں اس وقت کھل کر سامنے آیا جب بین الاقوامی تجارت کے بحری راستے دریافت ہوئے۔ جاگیری دور میں آلاتِ پیداوار، ہل بیل، ہنسیا، ہتھوڑا، چرخہ کھڈی، سبھی ذرائع پیداوار (زمین) کی مانند افراد کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں لہذا زرعی او ر صنعتی پیداوار بہت محدود ہوتی ہے۔ چنانچہ انگریز، ولندیزی اور پرتگالی بیوپاریوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ پیداوار کس طرح بڑھائی جائے۔ ان کو ہندوستان ، لنکا، جاوا اور ملایا وغیر ہ میں مصالحہ جات و مصنوعات سونے چاندی کے عوض نقد خریدنی پڑتی تھی۔ کیوں کہ مغربی مصنوعات کی مقدار بہت کم تھی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی وہ مشرقی بازاروں میں فروخت کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ وہاں تو فیکٹریوں اور کارخانوں کے مزدور بھی نہیں ملتے تھے کیوں کہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ فیوڈل نوابوں کی زمینوں سے بندھے تھے۔ ان شہروں میں جا کر کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس کے علاوہ جاگیرداروں اور نوابوں نے تجارتی مال کی نقل و حرکت پر طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی تھیں جن کی موجودگی میں تجارت ترقی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تھے وہ اقتصای تضادات جو جاگیری نظام کو نیست و نابود کیے بغیر حل نہیں ہو سکتے تھے۔
مگر جاگیریت فقط پسماندہ طریقہ پیداوار ہی کی علامت نہیں ہوتی بلکہ ایک فرسودہ ضابطہ حیات کی نشان دہی بھی کرتی ہے۔ لوگوں کا رہن سہن ، سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز، ان کی سماجی اور اخلاقی قدریں، رسم و رواج اور تعصبات و میلانات سب جاگیری ضابطوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان ضابطوں کی گرفت معاشرے پر اتنی سخت ہوتی ہے کہ ان کو توڑے بغیر جاگیری دور کے طریقہ پیداوار کو بدلا نہیں جا سکتا ۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے سرمایہ دار طبقوں کو مطلق العنان ملوکیت کے علاوہ، جو جاگیری نظام کا مرکز تھی جاگیری عہد کے ضابطہ حیات سے بھی لڑنا پڑا۔ سیکولر ازم یعنی جمہوریت اور مساوات، آئینی اور نمائندہ حکومت، فکر و ضمیر کی آزادی، سائنسی سوچ اور شہری حقوق کی جد و جہد جاگیریت اور سرمایہ داری کے درمیان نظریاتی جنگ ہی کی مختلف شکلیں تھیں۔ اس جنگ میں ملوکیت کے علم برداروں کی طرح کلیسا نے بھی ظلم و استبداد کا ساتھ دیا اور ہر روشن خیال، خرد افروز اور ترقی پسند تحریک کی شدت سے مخالفت کی مگر تاریخ کے دھارے کو نہ ملوکیت روک سکی نہ کلیسائیت۔ فرانس میں زبردست انقلاب آیا جس نے ملوکیت ، نوابیت اور کلیسا یعنی جاگیری نظام کے تینوں ستون گرادیے۔ اس کے بعد یورپ کے قریب قریب ہر ملک میں معاشرے اور ریاست کی تشکیل سیکولر خطوط پر ہونے لگی لیکن سیکولرازم کو پوری طرح رواج پانے میں ایک صدی لگی اور مغربی قوموں نے بڑی جد وجہد کے بعد پہلی بار وہ حقوق حاصل کیے جو سیکولرازم کی جان ہیں۔ مثلاً تحریرو تقریر کی آزادی، ضمیر و فکر کی آزادی، پریس کی آزادی، تنظیمیں بنانے کی آزادی اور اختلافِ رائے کی آزادی ورنہ جاگیری دور میں تو کسی نے ان حقوق کا نام بھی نہ سنا تھا۔
یورپ اور امریکہ میں سیکولر ریاستوں کے قیام سے لوگ لامذہب نہیں ہو گئے۔ نہ گرجا گھر ٹوٹے اور نہ پادریوں کی تبلیغی سرگرمیوں میں چنداں فرق آیا البتہ ہر شخص کو پہلی بار اس بات کا موقع ملا کہ دو دوسرے مسائل کی مانند مذہبی مسائل پر بھی بلا خوف و خطر غور کرے اور جو عقاید و رسوم خلافِ عقل نظر آئیں ان کو رد کردے۔ سیکولر ازم کے رواج پانے سے کلیسا کی قائم کی ہوئی خوف و دہشت کی فضا بھی ختم ہو گئی۔ کلیسائی دور میں لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی بھیانک قسم کی جسمانی ایذائیں دی جاتی تھیں اور ان کو توبہ کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ سیکولرازم کے دور میں یہ وحشانہ مظالم بند کر دیے گئے اور پادری حضرات کو بھی اپنا طرزِ عمل بدلنا پڑا۔ اب وہ لوگوں سے اخلاق و محبت سے پیش آنے پر مجبور ہوئے اور ڈارانے دھمکانے کے بجائے ان کو عقلی دلیلوں سے اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرنے لگے۔
(2)
مشرقی ملکوں میں سیکولر خیالات کے نشو ونما اٹھارویں صدی میں ہوئی۔ روشن خیالی کی یہ لہر ترکی اور ایران میں براہِ راست مغربی روابط سے آئی۔ مصر میں نپولین کے حملے کے دوران اور ہندوستان میں بنگال، بہار اور آگرہ دہلی پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے بعد۔ اس مضمون میں ہم فقط ترکی اور برصغیر کی سیکولر تحریکوں سے بحث کریں گے۔
سلطان سلیمان اعظم (1520ء۔1560ء) کا عہد سلطنتِ عثمانیہ کا نقطہ عروج تھا۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا فرماں روا تھا جو ہنگری سے یمن اور بغداد سے مراکش تک پھیلی ہوئی تھی، اس کی رعایا میں مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ ترک، عرب، کرد، سلاف، میجیار، بربر، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ عروج کا یہ دور تقریباً دو سو سال تک جاری رہا۔ 1683ء میں وینا (آسٹریا) پر ترکوں کے دوسرے حملے کی ناکامی زوالِ سلطنت کی تمہید ثابت ہوئی۔ پہلے ہنگری ہاتھ سے نکلا (1699ء) پھر کریمیا اور گرجستان، اس کے بعد بلغاریہ، یوگو سلاویہ، یونان، البانیہ، قبرص، الجزائر، لیبیا، کریٹ اور مصر۔ پہلی جنگِ عظیم کے بعد مغرب کی سامراجی طاقتوں نے عراق، عرب ، شام اور فلسطین پر بھی قبضہ کرلیا۔ اب ترکی کے پاس اناطولیہ کے علاوہ سالونیکا کا تھوڑا سا ساحلی علاقہ پرانی تسخیرات کی واحد نشانی رہ گیا ہے۔
عثمانی سلطنت میں اقتدارِ اعلیٰ کی مالک سلطان کی ذات تھی۔ وہ تمام اختیارات کا سر چشمہ ہوتا تھا۔ اس کا ” ارادہ” شریعت کے تابع نہ تھا مگر شریعت سے متصادم بھی نہ تھا۔ اس کو ” تقدیر و تعزیر” کا پورا استحقاق حاصل تھا۔ ارکانِ سلطنت تین طبقوں پر مشتمل تھے۔ 1۔ اصحابِ قلم جن کے تین مدارج تھے۔ اول رجال جن سے وزرا اور اعیانِ سلطنت مراد تھے۔دوئم خوجہ جو سرکاری دفتروں میں کام کرتے تھے۔ سوئم آغا یعنی شاہی محلات کے ملازم و محافظ۔ 2۔ اصحابِ سیف یعنی صوبوں کے فوجی گورنر اور “سپاہی” جن کو افواج شاہی کے لیے لشکری فراہم کرنے کے عوض جاگیریں (تیمار ) دی جاتی تھیں اور ” جاں نثار” یہ وہ شاہی فوج تھی جس میں اقلیتی علاقوں کے عیسائی لڑکے کمسنی میں بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان کو مسلمان بنایا جاتا تھا۔ ان کو شادی کرنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ان کا اپنا گھر بار ہوتا تھا۔ 3۔ اصحابِ مذہب، کلیسائی نظام دنیائے اسلام میں اگر کہیں تھا تو وہ ترکی تھا جہاں شیخ الاسلام کو صدر اعظم کے مساوی اختیارات حاصل تھے۔ وہ سلطنت کا سب سے بڑا قاضی اور مفتی ہوتا تھا۔ قاضی العسکر رومالیہ، قاضی العسکر اناطولیہ، قاضیِ استنبول، ملاء مکہ و مدینہ اور ملاء بروسا، ایدریانوپل، قاہرہ دمشق سب اس کے ماتحت ہوتے تھے۔ سلطنت کی تمام مساجد او ر اوقاف تمام عدالتیں اور درس گاہیں شیخ الاسلام کے تابع تھیں مگر وہ بیک وقت وزیرِ تعلیم، وزیرِِ قانون اوروزیرِ مذہبی تھا۔ اور عدالتِ عدلیہ کا چیف جسٹس بھی ۔ ” اصناف ” اور “رعایا” دو طبقے اور بھی تھے مگر ان کو امورِ سلطنت میں کوئی حق و اختیار نہ تھا۔ اصناف سے مراد تجارت پیشہ لوگ، دکاندار، دست کار اور اہلِ حرفہ تھے اور رعایا سے مراد کاشت کار۔ ارکانِ سلطنت کا فرض سلطنت یعنی سلطان کی طاقت کو مستحکم اور محفوظ کرنا تھا نہ کہ رعایا کی فلاح و بہبود کی تدبیریں اختیار کرنا۔
سلطنت کی اس طرزِ تعمیر ہی میں اس کی خرابی کی صورت مضمر تھی۔ سترھویں صدی میں جب یورپ میں جدید صنعت و تجارت نے بڑے پیمانے پر ترقی کی اور فیوڈل نظامِ فکر و عمل کی جگہ نیشنلسٹ جمہوری اور سیکولر اداروں نے قوت پکڑی تو عثمانی سلطنت جس کی بنیاد فیوڈل ازم اور عسکری طاقت پر قائم تھی یورپ کی ابھرتی ہوئی سرمایہ دار طاقتوں کا مقابلہ نہ کرسکی۔ نہ معاشرتی طورپر نہ فکری طورپر۔ خالدہ ادیب خانم ترکی کی ذہنی پسماندگی اور قدامت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ:
جس وقت مغرب نے روایت پرستی کی زنجیروں کو توڑنے اورنئے علم اور سائنس کی طرح ڈالی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا کی شکل بدل گئی مگر اسلام کا مذہبی جسد اپنے تعلیمی فرائض کی ادائیگی میں سراسر ناکام رہا۔ علما اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ انسانی علم و حکمت تیرھویں صدی سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ ان کا یہ اندازِ فکر انیسویں صدی تک بدستور قائم رہا۔ عثمانی علما نے ترکی میں نئی فکر کو ابھرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ جب تک مسلم قوم کی تعلیم کے نگراں رہے انہوں نے اس کا پورا پورا بندوبست کیا کہ تعلیم کے نصاب میں کوئی نئی فکر داخل نہ ہونے پائے لہذا علم پر جمود طاری ہو گیا۔ مزید برآں یہ حضرات ملکی سیاست میں اس درجہ الجھے ہوئے تھے کہ ان کو اصلاحات پر غور کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ مدرسے وہیں رہے جہاں وہ تیرھویں صدی میں تھے۔12
اٹھارویں صدی کی ابتدا میں مغربی طاقتوں کے ہاتھوں پے درپے شکست کے بعد جب ترکی یورپی اقوام کو تجارتی، قانونی اور مذہبی مراعات دینے پر مجبور ہوا، ترکی میں ا ن کے دفاتر اور تجارتی مرکرز قائم ہوے، مغربی حکومتوں سے ترکی کی روہ رسم بڑی تو اس بدی سے نیکی کی صورتیں بھی پیدا ہونے لگیں۔ مغربی سیاست کو سمجھنے کے لیے مغربی زبانوں بالخصوص فرانسیسی زبان اور تہذیب سے واقفیت ضروری ہو گئی۔ اس طرح اصحابِ سیف اور اصحابِ مذہب کے مقابل ” اصحابِ قلم” کا ایک نیا گروہ آہستہ آہستہ پیدا ہوا جو مغربی افکار و علوم سے قدرے آگاہ تھا اور مغربی تمدن کو قبول کرنے ہی میں ترکی کی نجات دیکھتا تھا۔ یہ گروہ صدقِ دل سے محسوس کرتا تھا کہ مشرقی اور اسلامی ورثہ نئے حالات اور نئے خطرات کا مقابلہ کرنے میں عثمانیوں کی مدد نہیں کرسکتا لہذا ہم کو مغربی تمدن و تہذیب اختیار کرلینا چاہیے۔ یہ رحجان سلطان احمد (1707ء۔ 1730ء) کے دور میں جس کو ” عہد لالہ” کہتے ہیں سلطان کے داماد اور صدرِ اعظم ابراہیم پاشا کی کوششوں سے ابھرا۔ اس نے 1717ء میں سائنسی کتابوں بالخصوص جغرافیہ، طب اور طبیعات کی کتابوں کا ترکی میں ترجمہ کرنے کی غرض سے 25 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی مقرر کی۔ 1720ء میں سلطان نے محمد فیضی چیلپی کو پیرس سفیر بنا کر بھیجا اور ہدایت کی کہ فرانس کے قلعوں اور فیکٹریوں کا معائنہ کرے، وہاں کے تہذیبی اداروں کی سرگرمیوں کو غور سے دیکھے اور جو جو چیزیں ترکی میں رائج کی جا سکتی ہوں ان کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرے۔ چیلپی نے واپس آکر ایک کتاب بھی لکھی جس میں وہ فرانس کے ٹیکنیکل فنون، فوجی اداروں اور ہسپتالوں ،ا سکولوں کی تعریف کرتا ہے اور عورتوں کی آزادی کو خوب سراہتا ہے۔
چیلپی کا بیٹا سعید محمد پہلا ترک ہے جس نے فرانسیسی زبان سیکھی۔ وہ فرانس کی آزادی فکر کا بڑا مداح تھا ۔ پیرس سے دوسری بار واپس آنے پر اس نے ہنگری کے ایک نو مسلم ابراہیم متفرقہ (1670ء۔ 1754ء) کے ساتھ مل کر 1727ء میں پہلا ترکی چھاپہ خانہ قائم کیا (ترکی میں پریس کا رواج 1587ء میں شروع ہو گیا تھا لیکن شیخ الاسلام کے فتوے کے مطابق صرف عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنی مذہبی کتابیں چھاپنے کی اجازت تھی) ابراہیم متفرقہ بڑا روشن خیال شخص تھا۔ وہ فرانسیسی، اطالوی، جرمن، لاطینی اور ترکی زبانیں جانتا تھا۔ نیازی برکس کے بقول ” ابراہیم وہ شخص ہے جس نے ترکی کو جدید سائنسی فکر سے روشناس کیا اور تبدیلی اور ترقی کی راہ دکھائی” 13 اس نے 1726ء میں ایک دستاویز ” وسیلتہ الطباعت” لکھی اور صدرِ اعظم داماد کو پیش کی۔ دوسرے سال اس کو پریس لگانے کی اجازت مل گئی لیکن کاتبوں نے سخت شور مچایا کہ اسلام خطرے میں ہے حالاں کہ اسلام نہیں بلکہ ان کی روزی خطرے میں تھی۔ کاتبوں کے احتجاج پر شیخ الاسلام نے فتویٰ صادر کیا کہ قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ کی کتابیں مطبع میں نہیں چھپ سکتیں۔ پہلی کتاب جو دنیائے اسلام کی پہلی مطبوعہ کتاب تھی 31 جنوری 1769ء کو چھپ کر شائع ہوئی۔ ابراہیم متفرقہ نے مغرب کی ترقی اور ترکی کی پسماندگی کے اسباب پر بھی ایک کتاب ” اصول الحکم فی نظام الااُمم” لکھی اور سلطان کو بھی پیش کی۔ اس کتاب میں وہ جمہوریت کے حق میں فیصلہ دیتا ہے ۔ اس کتاب کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس موضوع پر کسی اسلامی ملک میں پہلی بار اظہارِ خیال کیا گیا تھا۔وہ بار بار برطانیہ اور ہالینڈ کے حوالے دیتا ہے۔ وہ امورِ مملکت میں فوجی مداخلت کے سخت خلاف ہے اور فوج کی دقیانوسی تنظیم پر کڑی تنقید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ” مسیحی قوموں میں حکومت اب احکام اِلہٰیہ کے تابع نہیں رہی نہ اوامرو نواہی خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ وہاں اختلافات کا فیصلہ شریعت نہیں کرتی بلکہ حکومت کے فیصلے عقل سے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط کرتے ہیں۔ ” ابراہیم متفرقہ نے جغرافیہ، طبیعات اور فوجی حکمتِ عملی پر بھی کتابیں لکھیں۔ اسی نے پہلی بار کوپرنیکس اور دیکارٹ کے نظریات کا ذکر کیا اور ارسطا طالیسی طبیعات کی رد میں گلیلو کی دلیلوں کی حمایت میں لکھا۔ اس کی کتابیں ” فیوضاتِ مقناطیسیہ” اور ” مجموعہ حیاتِ قدیم و جدید” بہت پسند کی گئیں۔
مگر سیکولر خیالات کی نشرو اشاعت روایت پرست ملاؤں کو سخت ناگوار گزری۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ عوام میں اپنے اچھے برے کا شعور پیدا ہو او ر وہ عقل سے کام لیں۔ انھوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جدید علوم کی تعلیم کا مقصد لوگوں کو دراصل عیسائی بنانا ہے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا ہے۔ اسی اثنا میں سلطان احمد نے فوج میں بھی اصلاحات شروع کردیں۔ یہ اصلاحات ” جاں نثاروں” کے مفاد کے خلاف تھیں لہذا انھوں نے ملاؤں کی شہ پا کر بغاوت کردی، سلطان احمد برطرف ہوا۔ صدرِ اعظم ابراہیم داماد اور امیر البحر مصطفیٰ پاشا کو گلا گھونٹ کر ہلاک کردیا گیا۔ محمد فیضی چیلپی اور سعید محمد قبرص میں جلا وطن کردیے گئے، ابراہیم متفرقہ کا چھاپہ خانہ بند ہو گیا۔
خالدہ ادیب خانم کے بقول ترکی نشاۃِ ثانیہ کا آغاز سلطان سلیم سوئم (1787ء 1807ء) کے عہد میں ہوا ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انقلابِ فرانس کے نعروں سے سارا یورپ اور امریکا گونج رہا تھا۔ معاشرتی اور فکری ہیجان انتہا کو پہنچ چکا تھا اور فرانسیسی روشن خیالوں کے نظریات کا ہر طرف ڈنکا بج رہا تھا۔ سلطان سلیم انقلابِ فرانس سے بے حد متاثر تھا مگر اصلاحات ہی اس کا مقصد نہ تھیں بلکہ وہ جدید اصولوں پر نئی ریاست قائم کرنے کا خواہش مند تھا۔” 14
سلطان سلیم نے تخت نشین ہوتے ہی یہ محسوس کر لیا کہ پرانی فوج کی موجودگی میں کسی قسم کی اصلاح ممکن نہیں لہذا اس نے ” نظامِ جدید” کے نام سے ایک متوازی نئی فوج کھڑی کی۔ مدرسے چوں کہ اصحابِ مذہب کی نگرانی میں تھے لہذا اس نے فوج، بحریہ اور انجینئرنگ کے اسکول ان مدرسوں سے الگ قائم کیے۔ انجینئرنگ اسکول میں تو وہ خود لیکچر دیتا تھا۔ اس نے ملک کے نظم و نسق میں رعایا کو شریک کرنے اور سول افسروں کی مطلق العنانی میں تخفیف کی غرض سے یہ حکم دیا کہ مقامی معاملات کا تصفیہ لوگ آپس میں مل کر خود کیا کریں۔ اس نے تیماری نظام اور کرنسی کی اصلاح کی بھی کوشش کی۔ پہلی بار مغربی ملکوں میں مستقل سفارت خانےکھولے اور فرانسیسی زبان، فرانسیسی لباس اور فرانسیسی طرزِ زندگی کی حوصلہ افزائی کی مگر سلطان سلیم نے ان اصلاحی تدبیروں سے پرانی فوج، افسر شاہی اور علما تینوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ 1807ء میں جن دنوں سلطان کی نئی فوج بلقان مین بغاوت فرو کرنے میں مصروف تھی پرانی فوج نے علما اور اعیان کی مدد سے قسطنطنیہ میں بغاوت کردی اور سلطان کو قتل کردیا۔
سلطان محمود دوئم (1808ء۔1839ء) سلطان شہید کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کے خیالات سے پورا پورا اتفاق کرتا تھا البتہ وہ سلطان سلیم سے زیادہ دور اندیش ثابت ہوا۔ وہ سترہ برس تک ” جاں نثاروں” سے نباہ کرتا رہا۔ اس اثنا میں اس نے عام لوگوں سے ربط ضبط بڑھانے کی کوشش کی ۔ وہ ان میں گھل مل کر ان کی فریاد سنتا اور ان کی دل جوئی کرتا چنانچہ لوگ اس کو پیار سے محمود عدلی کہنے لگے۔ تب اس نے موقع پا کر 1862ء میں جاں نثاروں کا قلع قمع کردیا اور حکومت کا نیا ڈھانچہ بنایا جس کی رُو سے صدرِ اعظم کا عہدہ منسوخ ہو گیا، نظم و نسق کے مختلف شعبوں کے لیے الگ الگ وزرا (وکیل) مقرر ہوئے اور ان کے مجموعے کو ” باب عالی ” کا لقب دیا گیا۔ شیخ الاسلام کو اس نئی وزراتی تنظیم میں شامل نہیں کیا گیا بلکہ فرمان صادر ہوا کہ علما آئندہ سیاست میں حصہ نہ لیں۔ 1838ء میں سلطان نے مدرسوں کے متوازی نئے اسکول مغربی طرز پر قائم کیے جن میں ذریعہ تعلیم فرانسیسی زبان تھی اور سائنسی علوم کی تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ اس نے جدید طرز کی ملٹری اکیڈمی اور میڈیکل کالج بھی قائم کیے اور ان کے لیے استاد وینیا (آسٹریا) سے بلوائے مگر علما نے سرجری کی تعلیم کی سخت مخالفت کی اور مردہ جسموں کی چیر پھاڑ کو ناجائز قرار دے دیا۔ لہذا سرجری سکھانے کے لیے موم کے مجسمے استعمال کرنے پڑے۔ ملاؤں نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ یہ بحث چھڑ دی کہ زمین گول ہے یا نہیں۔ وباؤں سے بچنا چاہیے یا تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ کہ چیچک کا ٹیکہ جائز ہے یا ناجائزلیکن سلطان نے ان اڑنگوں کی پروا نہ کی۔ اس نے پہلی بار ڈیڑھ سو نوجوانون ترکوں کو یورپ بغرض تعلیم بھیجا۔ ایک دارالترجمہ قائم کیا جس میں سید عثمان صائب اور مصطفیٰ بہجت کی نگرانی میں سائنسی علوم کی مغربی کتابیں ترکی میں ترجمہ ہونے لگیں۔ سلطان نے دُخانی کشتیوں کو رواج دیا اور لوگوں کی ہیبت دور کرنے کی خاطر خود ان میں بیتھ کر سیروتفریح کرنے لگا۔ کوٹ پتلون اور قمیض کا استعمال بھی اسی کے زمانے میں عام ہوا اور ہیٹ اوڑھنے پر جب قدامت پرستوں نے بہت شور مچایا تو 1820ء لال ترکی ٹوپی وضع کی گئی۔ ترکی زبان میں پہلا اخبار جس کا نام ” تقویم وقائع” تھا سلطان محمود ہی کے حکم سے 1831ء میں جاری ہوا۔ اس کا ایڈیٹر اسد بے تھا اور چیف ایڈیٹر مصطفیٰ سمیع (وفات 1855ء)۔
اس عہد کے بدلتے ہوئے مزاج کا اندازہ مصطفیٰ سمیع کے ” سفر نامہ اَرد پارسالسی” (1838ء) سے ہوتا ہے۔ یہ سفر نامہ روم، فلورنس، وینیا، پراگ، برلن، پیرس اور لندن کے مشاہدات و تاثرات پر مشتمل ہے۔ مصطفیٰ سمیع مغرب میں سائنس کے فروغ کا، مذہبی آزادی کا اور جدید و قدیم تخلیقات کو عجائب گھروں میں محفوظ کرنے کے شوق کا خاص طورپر ذکر کرتا ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ مغرب میں وہ صنعتیں ترقی پر ہیں جن کی مسلمانوں کوسخت ضرورت ہے۔ مثلاً کاغذ، سوتی کپڑے، شیشہ اور گھڑی بنانے کی صنعتیں۔ ملاؤں نے مصطفیٰ کو کافر اور ملحد کا لقب عطا کیا۔
س دور کا دوسرا روشن فکر مصنف صادق رفعت (1807ء۔ 1856ء) ہے جس نے بعد میں ” تنظیمات” کے اصول مرتب کیے۔ 1837ء میں وہ آسٹریا میں سفیر مقرر ہوا۔ وہاں قیام کے دوران اس نے یورپ کے حالات کا ترکی سےے موازنہ کرتے ہوئے دو کتابیں تصنیف کیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ” یورپ میں حکومتیں شہریوں کی بہبودی کےلیے ہیں نہ کہ شہری حکومت کی بہبودی کے لیے۔ لہذا حکومتیں ملت کے حقوق اور مروجہ قوانین کے مطابق چلتی ہیں”۔ صادق رفعت پہلا شخص ہے جس نے ترکوں کو مغربی تہذیب و تمدن، آزادی، ملت اور انسانی حقوق کے تصورات سے متعارف کیا اور لکھا کہ مغربی تمدن جدید سائنس کی پیداوار ہے اور اس کی ٹیکنالوجی بہت اعلیٰ ہے۔
ترک مورخ سلطان محمود کو ترکی کا پیٹرا اعظم کہتے ہیں جس نے مغربی تہذیب و تمدن کو ترکی میں رائج کیا مگر نیازی برکس کے بقول ” یہ مغربی اصلاحات سلطان کے من کی موج کا نتیجہ نہ تھے بلکہ روایتی اداروں کی شکست و ریخت اور لبرل اور سیکولر خیالات کا فروغ مغربی طرز کی اصلاحات کا سبب بنے۔”
سلطان عبدالمجید (1839ء۔1861ء) نے باپ کی اصلاحی سرگرمیوں میں اور اضافہ کیا۔ ” تنظیمات” کا تاریخی دو اسی کے عہد میں شروع ہوا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی 3 نومبر 1839ء کو ایک فرمان جو ” گلشنِ خطِ ہمایوں” کے نام سے مشہور ہے خود اپنے قلم سے لکھا اور شیخ الاسلام کی منظوری کے بغیر براہِ راست جاری کردیا۔ فرمان میں سلطان نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ ہر شخص کو جان و مال اور عزت و آبرو کا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ مسلم اور غیر مسلم رعایا قانون کی نظر میں مساوی ہوں گے۔ ” قوانینِ جدید” کے خلاف بابِ عالی سے کوئی احکام صادر نہیں ہوں گے اور ایک مجلسِ شوریٰ قائم ہوگی (سلطان کی نامزد کردہ) جو قوانین وضع کرے گی البتہ قوانین کا نفاذ سلطان کی صوابدید پر منحصر ہوگا۔ خطِ ہمایوں میں یہ تو تسلیم نہیں کیا گیا کہ اقتدارِ اعلیٰ کی مالک قوم ہے البتہ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ سلطان کی ذات اقتدارِاعلیٰ کی مالک نہیں ہے۔
تنظیمات کے دور میں (1839ء۔ 1876ء) بظاہر بہت سی اصلاحیں ہوئیں: کابینہ کے اصول پر نئی طرز کی وزارتیں قائم کی گئیں۔ انتظامیہ، مقنّنہ اور عدلیہ کے شعبے کسی حد تک الگ ہوئے۔ شیخ الاسلام کے ماتحت عدالتوں کے پہلو بہ پہلو سیکولر عدالتیں اور روایتی مدرسوں کے پہلو بہ پہلو سیکولر اسکول کھلے جن میں گلا تاسرائے کا ایک اسکول سب سے بڑا تھا۔ وہاں تعلیم فرانسیسی زبان میں ہوتی تھی۔ ٹیجرز ٹریننگ کالج اور استنبول یونیورسٹی (1870ء) بھی اسی زمانے کی یادگاریں ہیں۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں کو بہت سی مراعات دی گئیں اور جزیہ منسوخ ہوا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر سلطنت کا اقتصادی ڈھانچہ نہ صرف بدستور فیوڈل رہا بلکہ اس پر مغربی سامراج مسلط ہو گیا۔ نہ جدید طرز کی فیکٹریاں قائم کی گئیں اور نہ معدنیات سے فائدہ اٹھانے کا کوئی منصوبہ بنا۔ بازاروں میں مغرب کی سستی مصنوعات کی بھرمارسے ترکی کی رہی سہی گھریلو صنعتیں بھی برباد ہو گئیں۔تجارت اور جہاز رانی کو فروغ ہوا مگر ان شعبون پر غیر ترک قوموں۔۔۔۔ یونانیوں اور ارمینوں۔۔۔ کا قبضہ تھا اور وہ برطانیہ اور فرانس کے اشاروں پر چلتی تھیں۔ ان سامراجی طاقتوں کے دباؤ کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ درآمدی مال پر ڈیوٹی کم اور برآمدی پر ڈیوٹی برائے نام لگتی تھی۔
“عثمانی سلطنت ایک طرح کی یورپی کالونی بن گئی جس کا کام مغربی ملکوں کو سستا خام مال اور وہاں کی مصنوعات کے لیے ایک وسیع بازار فراہم کرنا تھا۔ اسی دوران میں مغربی سرمائے کی کھپت بھی بڑھ گئی اور اس کو نہایت نفع بخش مراعات دے دی گئیں۔ جو کمی رہ گئی تھی اس 1854ء میں شاہی قرضوں نے پورا کر دیا۔ یہ قرضے بے حد تباہ کن شرطوں پر برطانیہ اور فرانس سے حاصل کیے گئے تھے۔ سرکاری آمدنی کے کئی اہم زرائع سود کی ادائیگی کے لیے ان طاقتوں کے ہاتھ رہن رکھ دیے گئے۔” 15
اِدھر مغربی قوتیں ترکی کی معیشت کا آخری قطرہ خون کشید کرنے میں مصروف تھیں اُدھر یورپ میں آزادیِ وطن، آئینی حکومت اور جمہوریت کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ ہنگری، چیکو سلوواکیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی میں لوگوں نے اسلحہ سنبھال لیا تھا اور دشمن کی فوجوں سے جم کر لڑ رہے تھے۔فرانسیسی روشن فکروں کی تعلیمات رنگ لا رہی تھیں۔ تنظیمات کی بدولت ترکی میں جو نیا ترقی پسند درمیانہ طبقہ نمودار ہوا اس نے یورپ کی انقلابی سرگرمیوں سے بھرپور اثر قبول کیا اور قوم میں فکرو عمل کی نئی روح پھونکی۔ وطن پرستوں کی ایک تحریک میں کچھ سرکاری ملازم تھے ، کچھ فوجی افسر اور چند کاروباری لیکن تحریک کے روحِ رواں ترکی کے روشن خیال ادیب اور دانشور تھے۔ جدید ترکی ادب اور “نوجوان ترک تحریک” دونوں کے بانی وہی تھے۔ جس طرح ہندوستان میں سرسید اور ان کے رفقا، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابو الکلام آزاد، علامہ اقبال، مولانا حسرت موہانی اور دوسرے محب وطن ادیبوں کے نزدیک ادب اور سیاست ایک ہی حقیقت کے دورُخ تھے اور وہ بیک وقت دونوں کی خدمت کرتے تھے اسی طرح ترکی میں بھی جدید ادب اور جدید سیاست کے دھارے مل کر بہتے تھے۔ ادیب ملکی سیاست سے نہ صرف وابستہ تھے بلکہ اس کی قیادت بھی انھوں ہی نے کی ۔ ان میں ابراہیم شناسی ، نامق کمال ، ضیا پاشا اور مصطفیٰ فاضل پاشا خاص طورپر قابلِ ذکر ہیں۔
” نوجوان ترکوں” کا مطالبہ تھا کہ سلطنت کا آئین رعایا کی مرضی سے وضع ہو۔ ملک میں آئینی حکومت قائم کی جائے اور عوام کے نمائندوں کو بھی نظم و نسق میں شرکت کا موقع ملے۔ مدرسے کے فرسودہ نظامِ تعلیم کی جگہ مغربی طرزِ تعلیم کو اپنایا جائے، امورِ سلطنت میں علما کی مداخلت بند کی جائے اور مغربی طاقتوں کے اثرو اقتدار کو ختم کرنے کی غرض سے مغربی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا جائے۔ عثمانی تہذیب درحقیقت ترک تہذیب نہ تھی بلکہ ایرانی تہذیب کا چربہ تھی۔ سلطنت کی دفتری زبان فارسی تھی اور عثمانی خواص کی زبان میں فارسی اور عربی الفاظ اور محاورے اس کثرت سے داخل ہو گئے تھے کہ عام ترک جن کی مادریج زبان کو سرکار دربار میں بڑی حقارت سے دیکھا جاتا تھا عثمانیوں کی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایرانی اور عربی میں ایسی کوئی تازہ فکر بھی موجود نہ تھی جو جدید ترکی کو ذہنی خوراک مہیا کرتی یا ان کو مستقبل کی راہ دکھاتی لہذا انھوں نے ” شرقی” تہذیب پر ” غربی تہذیب” کو ترجیح دی۔ ان دنوں چوں کہ ہر طرف فرانسیسی فکر و فن کا غلبہ تھا لہذا ترک ادیبوں نے بھی فرانس سے ربط و ضبط بڑھایا اور فرانسیسی فلسفیوں ، ڈرامہ نویسوں، ناول نگاروں اورشاعروں کی تحریروں سے استفادہ کیا۔
اگر کسی فردِ واحد کو ” نوجوان ترک تحریک” اور جدید ترکی فکر و ادب کا بانی کہا جا سکتا ہے تو وہ ابراہیم شناسی آفندی (1824ء۔ 1871ء) تھا۔ ابراہیم شناسی استنبول میں پیدا ہوا۔ ایک سال کا تھا کہ باپ فوج میں لڑتا ہوا مارا گیا لہذا پرورش نانہیال میں ہوئی۔ لکھنے پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں شاہی اسلحہ خانہ میں کلرک بھرتی ہوا۔ وہاں اس نے راشد بے نامی ایک نو مسلم فرانسیسی افسر سے، جس کی بیوی ترک تھی فرانسیسی زبان سیکھی۔ ابراہیم کی ذہانت سے متاثر ہو رکر راشدے بے نے اس کو فرانس جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ اتفاق سے انھیں دنوں صدرِ اعظم معائنے پر آئے تو ابراہیم نے سرکاری وظیفے پر فرانس جانے کی درخواست پیش کردی۔ درخواست منظور ہو گئی اور وہ پیرس روانہ ہوگیا۔ پیرس میں وہ چار سال رہا اور فرانسیسی فلسفے، سائنس اور ادب کا مطالعہ کرتا رہا۔
ابراہیم شناسی 1852ء میں استنبول واپس آیا۔ اس نے تھوڑے دنوں سرکاری ملازمت کی اور سلطان عبدالمجید کی قائم کردہ سائنس و ادب کی اکیڈمی “انجمنِ دانش” کا رکن منتخب ہوگیا لیکن اس کے مزاج میں لچک بالکل نہ تھی اور نہ اس کی مضطرب روح سرکاری ملازمت کی پابندیاں برداشت کر سکتی تھی۔ اس نے نئے صدرِ اعظم کے خلاف جو آئینی اصلاحات کا جانی دشمن تھا کئی طنزیہ تحریریں شائع کیں لہذا ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اب اس نے اخبار نویسی شروع کی۔ پہلے اخبار ” ترجمان” شائع کیا اور پھر ” تصویرِ افکار” خالدہ ادیب خانم کے بقول جدید ترکی صحافت کا بانی ابراہیم شناسی ہی ہے۔ تصویرِ افکار، کا پہلا شمارہ شائع ہوا تو سلطان عبدالعزیز (1861ء۔1874ء) نے پانچ سو پونڈ بطور تحفہ بھجوائے لیکن شناسی نے رقم یہ کہہ کر واپش کر دی کہ ” میں ایسی کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا جس کی قیمت پانچ سو پونڈ ہو۔”
ابراہیم شناسی نے خالدہ ادیب خانم کے بقول ” جدید ترکی کی زندگی اورفکر میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔” 16 اس نے حقوقِ شہریت، حقوقِ انسانی، حریت، قومی شعور، آئینی حکومت، جمہوریت اور اس قبیل کی دوسری اصطلاحوں کو نہ صرف رائج کیا بلکہ ان کے معنی و مفہوم اخبار میں بڑی شرح و بسط سے لکھے۔ وہ پہلا ادیب ہے جس نے ملت کا لفظ قوم یعنی ” نیشن” کے معنی میں استعمال کیا۔ اس نے لوک کہانیوں اور جانوروں کی کہانیوں کے مجموعے اور فرانسیسی ادیبوں کے ترجمے شائع کیے۔سماجی ڈرامے لکھے جن میں “شاعر کی شادی” میں روایتی معاشرے پر کڑی تنقید کی۔ وہ توہم پرستی کا شدت سے مخالف اور جمہوریت کا شدت سے حامی تھا۔ لہذا ملاؤں نے اس کو دہریہ اور لامذہب کہنا شروع کردیا۔
عثمانیوں نے ترکی زبان کی طرف سے جو غفلت برتی تھی ابراہیم شناسی کو اس کا بڑا تلخ تجربہ صحافتی سرگرمیوں کے دوران ہوا کیوں کہ مروجہ تحریری زبان جدید مغربی خیالات کو ادا کرنے سے قاصر تھی لہذا اس نے چودہ جلدون میں ایک جامع ترکی لغت مرتب کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن وہ فقط حرف “ط” تک مکمل کرپایا تھا کہ تشدد دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس کے رفقا گرفتار کر لیے گئے اور اس کو مجبوراً ترکِ وطن کر کے پیرس میں پناہ لینی پری ( 1864ء) چھ سال بعد وہ استنبول واپس آیا اور اپنے چھاپے خانے کے ایک گوشے میں رہنے لگا اوروہیں نہایت عسرت کی حالت میں انتقال کرگیا۔
نامق کمال (1840ء۔1888ء) اس دور کی دوسری نہایت اہم شخصیت ہے۔ وہ جوانی میں ابراہیم شناسی سے وابستہ ہو گیا اور اس کا سچا جانشین ثابت ہوا۔ وہ سیاست داں تھا، مورخ تھا، شاعر تھا، ناول نویس تھا اور ڈرامے لکھتا تھا۔ اس نے بیکن ، مان تس کیو، روسو اور دوسرے کئی روشن خیال مصنفوں کے ترجمے شائع کیے۔ ” اورفکرِ جدید کی جو مشعل ابراہیم شناسی نے جلائی تھی اس کو ادب اور سیاست کے میدان میں لے کر آگے بڑھا۔” وطن سے والہانہ محبت اور حب الوطنی کا مخلصانہ جوش اس کی تحریروں کا امتیازی نشان ہے۔ اس کا ڈرامہ “وطن” جس رات پہلی بار استنبول میں اسٹیج پر کھیلا گیا تو تماشائی وفورِ جذبات سے بے قرار ہو کر سڑکوں پر نکل آئے اور تمام رات مظاہرے کرتے رہے۔ دوسرے دن نامق کمال گرفتار ہوگیا۔
نامق کمال فرد کے انسانی حقوق کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جو حکومتیں عوام کی مرضی و منشا سے نہیں قائم ہوتیں وہ جبرو استبداد کی مظہر ہوتی ہیں لہذا ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے شہری حق کے لیے آخر وقت تک لڑتا اور قربانیاں پیش کرتا رہے۔ اس ضمن میں اس کے شاہ کار ” قصیدہ حریت” کا یہ ٹکڑا قابل غور ہے۔
” حالات کی رونے اگرچہ دیانت او ر صداقت سے مُنھ موڑ لیا ہے لیکن انسان اگر انسان ہے تو وہ خدمتِ خلق سے کبھی نہیں تھکے گا۔ افتاد گانِ خاک اور ستم رسیدِ گانِ استبداد کو سہارا دے کر اٹھانا اس کا فرض ہے۔ جو رو جبر کے حامیوں کے دل و دماغ میں فساد پرورش پاتا ہے۔ کتے خوں خوار شکاری کے حکم کی تعمیل میں خوش ہوتے ہیں۔ جلاد کی رسی موت کا اژدہا سہی مگر غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی زندگی سے یہ موت ہزار بار، صدہزار بار زیادہ گوارہ ہے۔ حُریت کا میدان آگ اور خون کا میدان سہی لیکن انسان اس سے فقط جینے کی خاطر گریز نہیں کرے گا۔مقدر اپنے تمام استبدادی حربے استعمال کرلے مگر تف ہے مجھ پر اگر میں خدمت خلق اور جدوجہد کی راہ سے ہٹ جاؤں۔ اور حریت! تجھ میں کیا جادو ہے کہ ہم نے تمام زنجیریں توڑ ڈالیں لیکن تیرے غلام ہیں۔”
نامق کمال 1870ء میں یورپ سے وطن واپس آیا۔ وہاں کی معاشرتی زندگی کے مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یورپ کی ترقی اور کامیابی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگوں نے توکل اور تقدیر پرستی کے زہریلے عقاید کو ذہنوں سے خارج کردیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ترکی کا اصل مسئلہ اقتصادی ہے لہذا ہم کو جدید صنعت و حرفت کو ترقی دینا چاہیے اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنا لینا چاہیے۔ آزاد پریس قائم کرنا چاہیے اور تعلیم کی از سرِ نو تنظیم کرنی چاہیے۔ نامق کمال اور اس کے ہم خیال نوجوان ترکوں کا مطالبہ تھا کہ ملک میں ” قانونِ اساسی” کی حکومت قائم ہو (یہ آئینی دستاویز خود نامق کمال نے پیرس میں تیار کی تھی)۔ نظم و نسق کی ذمہ داریاں ” مجلسِ مبعوثوں اور مجلسِ شوریٰ اُمت” کے حوالے کی جائیں اور سلطان کی حیثیت آئینی سربراہ مملکت کی ہو۔یہ وہ زمانہ تھا جب فرانس میں شہنشاہ نپولین سوئم کی مہم جوئیوں سے عوام عاجز آچکے تھے۔ جرمنی نے فرانس کو میدانِ جنگ میں شکست دے دی تھی اور نپولین کو قید کر کے فرانس کو نہایت ذلت آمیز شرائط پر صلح کرنے پر مجبور کردیا تھا مگر پیرس کے انقلابی مزدوروں نے ان شرطوں کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ احتجاجاً اپنی پنچایتی حکومت قائم کر لی تھی ( پیرس کمیون 1870ء۔ 1871ء) ان حالات نے سلطان عبدالعزیز کو بے حد خوف زدہ کردیا۔ اس کو اندیشہ تھا کہ کہیں حُریت پسند عناصر ترکی میں بھی اس قسم کی شورش برپا نہ کردیں لہذا بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ شروع ہو ئی۔ نامق کمال اور کئی دوسرے ممتاز افراد قید کردیے گئے اور بے شمار ادیبوں اور محبِ وطن ترکوں نے یورپ میں پناہ لی۔ جب تشدد بہت بڑھ گیا تو مدحت پاشا نے جو صوبہ ڈینوب اور عراق کا گورنر رہ چکا تھا اور نوجوان ترکوں کےنصب العین سے ہمدردی رکھتا تھا سلطان عبدالعزیز کو تخت سے اتار کر اس کے بھتیجے سلطان عبدالمجید دوئم (1876ء۔ 1909ء) کو تخت پر بٹھا دیا۔ مدحت پاشا صدرِ اعظم مقرر ہوا اور ترکی میں پہلی بار 23 دسمبر 1864ء کو قانونِ اساسی سلطان کے دستخط سے ناٖفذ کیا گیا۔ سلطان نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر حلفِ وفاداری اٹھایا اور عہد کیا کہ میں آئین سے کبھی انحراف نہیں کروں گا۔ تب آئین کے مطابق دو ایونوں پر مشتمل مجلسِ شوریٰ ملی منتخب ہوئی اور پورے ملک میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔
لیکن یہ خوشیاں چند روزہ تھیں۔ کیوں کہ ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ سلطان اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہوگیا۔ مدحت پاشا کو طائف میں قید کردیا گیا اور بعد میں قتل ۔ نامق کمال جزیرے میں نظر بند ہوا اور سلیمان پاشا کو بغداد جیل میں بند کردیا گیا جہاں کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہوگیا۔ آئین معطل ہوگیا، پارلیمنٹ توڑ دی گئی اور ترقی پسندوں کے خلاف داروگیر کی ملک گیر مہم شروع ہوئی۔ اس کارِ خیر میں علمائے کرام نے سلطان کے ساتھ پوراپورا تعاون کیا۔ شیخ الاسلام نے فتویٰ صادر کیا کہ آئین پسند “سرخے” ہیں یعنی پیرس کمیون کے ایجنٹ ہیں۔ سُرخ روئی کی خاطر شہاب الدین احمد ربیعی کی کتاب “سلوک الممالک فی تدبیر الممالک” سلطان کی خدمت میں بطور سند پیش کی گئی۔ لُب لُباب یہ تھا کہ ” آئین پسند مفسدہیں۔ وہ آزادی تقریر اور جمہوریت کے پردے میں سیکولرازم اور الحاد کا پروپیگنڈا کرتے ہین اور یہ کہ آزادی تقریر مہمل اصطلاح ہے۔ اسلامی ریاست کی اساس نہ اشرافیہ ہے نہ جمہوریت بلکہ خلافتِ عثمانیہ ہے لہذا اقتدارِ اعلیٰ کا مالک خدا ہے اور خدا کا نائب سلطان خلفیہ۔”
سلطان عبدالمجید کے عہدِ ظُلمت پرست میں مُلائیت اور مخبری کا کاروبار خوب چمکا۔ سلطان نے محل کے اندر ایک مخصوص مہمان خانہ مُلاؤں کی خاطر تواضع کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ زیادہ مقتدر علما کے قیام کے لیے عالی شان کوٹھیاں مخصوص تھیں۔ احمد فریس الشریاق، سید جمال الدین افغانی، شیخ محمد ظفر مکی، شیخ جواد، شیخ فضل حضرموتی،امیر مسقط، عبدالہدیٰ سیدی جلی جو روحانی طاقت کے شعبدے دکھاتا تھا سلطان کے مشیرو مصاحب بنے۔ نقش بندی شاذلی، رفاعی اور تجانی سلسوں کے دامے درمے سرپرستی ہونے لگی اور احکامِ شریعت پر لوگوں سے زبردستی عمل کروانے کی خاطر پولیس کو وسیع اختیارات دے دیے گئے تھے۔ ان ظاہر پرستیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے نیازی برکس لکھتا ہے کہ “ترکی میں غالباً کسی عہد میں دین کا تذکرہ اور شریعت کی باتیں اس کثرت سے کبھی نہیں ہوئیں لیکن بیش تر علمائے دین منافقت کا بے مثال نمونہ تھے۔” اپنے اس بیان کی تائید میں وہ موسی کاظم کا قول نقل کرتا ہے جو سلطان عبدالمجید کی برطرفی کے بعد شیخ الاسلام مقرر ہوا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ:
“مشاہیرِ سلطنت اپنی بد عنوانیوں اور سیہ کارویوں پر پردہ ڈالنے کی خاطر عبادت کو خاص طورپر استعمال کرتے تھے۔ وہ جہاں جاتے ملازم ان کی جاء نماز بغل میں دبائے پیچھے پیچھے چلتا تھا حتیٰ کہ وہ دفتروں میں بھی اپنی ان نمائشی حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ محل کی خوشنودی کے لیے مذہبی بھیڑیوں کی صف میں شامل ہونا ضروری تھا ۔ خلیفہ کو خدا کا درجہ دیا گیا تھا۔” 17
سلطان کے حکم سے اخباروں، رسالوں اور کتابوں پر کڑی سنسرشپ عائد کر دی گئی ۔ بعض سیاسی اصطلاحوں مثلاً حُریت ، وطن ، آئین،جمہوریت کا استعمال ممنوع قرار پایا، حتیٰ کہ ان الفاظ کو لغت سے بھی خارج کردیا گیا۔18 تنظیماتی دور کا تمام لٹریچر جس میں نامق کمال کی تصنیفات بھی شامل تھیں ضبط ہوگیا۔ تنظیماتی لٹریچر کا اگر ایک صفحہ بھی کسی کے پاس مِل جاتا یا کسی شخص کی زبان سے ممنوعہ الفاظ نکل جاتے تو اس کو سخت سزا ملتی یا جلا وطن کردیا جاتا تھا۔۔۔۔ چنانچہ ہزاروں نوجوانوں نے نامق کمال کی تصنیفات کے خفیہ مطالعے اور تشہیر کی پاداش میں جان سے ہاتھ دھویا۔ استنبول سے جہاز کے بعد جہاز نوجوانوں کو لادے جن میں اکثر اسکول کے کمسن لڑکے ہوتے تھے، یمن اور فزان کے ریگستانوں کو جو جلاوطنی کے کاسیکی مرکزتھے روانہ ہوتے رہتے تھے۔19
تشدد، جسمانی اذیت کے خوف اور سنسرشپ کی پابندیوں سے عاجز آکر بعض ادیبوں نے فرار کی راہ اختیار کرلی اور قنوطیت کا شکار ہو گئے۔ بعضوں نے مایوس ہو کر خودکشی کر لی لیکن بیش تر ادیبوں نے سیاسی امور پر لکھنے کے بجائے تہذیبی اور معاشرتی مسائل پر طبع آزمائی شروع کردی۔ بالزک، زولا، فلابیر اور ستاندال کے ترجمے شائع کیے۔ اور عثمانی زبان کے بجائے کلاسیکی ترکی کی ترقی اور ترویج پر زور دینے لگے۔ ضیا پاشا نے روسو کی ایمیل کا ترجمہ کیا اور لکھا کہ ہماری حقیقی زبان اور شاعری وہ ہے جو ترک عوام میں زندہ ہے۔ ہماری قدرتی شاعری لوک شاعری ہے۔ مدحت آفندی نے عثمانی زبان پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ:
” ہماری قوم اپنی مادری زبان سے محروم ہو گئی ہے۔ اس کے بجائے ہم کو عثمانی زبان سیکھنی پڑتی ہے۔ یہ زبان نہ عربی ہے نہ فارسی اور نہ ترکی بلکہ ایک مخصوص اقلیت کی زبان ہے جو اکثریت پر حکومت کرتی ہے اور اس کو بے زبان بنا رہی ہے۔”20
ترکی زبان کے حامیوں میں ایک حلقہ ان ادیبوں کا بھی تھا جو عربی زبان اور رسم الخط کے سخت خلاف تھے۔ مثلاً طاہر منیف، حسین ثابت، توفیق فکرت اور حسین رحمی وغیرہ۔ طاہر منیف نے ایک تنظیم ” جماعتِ علمیہ، عثمانیہ” کے نام سے قائم کی تھی اور ایک رسالہ ” مجموعہ فنون” شائع کرتے تھے جس میں سائنسی معلومات پر تبصرہ ہوتا تھا۔ اُن کے نزدیک ترکوں کی ناخواندگی اور پسماندگی کا ذمہ دار عربی رسم الخط تھا لہذا وہ لاطینی اپنانے کے خواہاں تھے۔
سلطان کے جبرواستبداد کا مقابلہ کرنے کی غرض سے استنبول کے فوجی کالج کے طلبا نے 1889ء میں ایک خفیہ جماعت ” عثمانی لی اتحادو ترقی” کے نام سے بنائی۔ یہی گر وہ بعد میں ” نوجوان ترک” کہلایا۔ اتحاد سے اُن کی مراد سلطنت کی مختلف قوموں میں اتحاد اور ترقی سے مراد مغربی تمدن کو فروغ دینا تھا۔ 1896ء میں حکومت کو اس تنظیم کا سراغ مل گیا لہذا جو بھاگ سکے اُنھوں نے فرانس میں پناہ لی۔ بقیہ گرفتار ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد انجمن نے اپنے ٹوٹے ہوئے تار پھر جوڑے مگر اب کے اتحاد و ترقی کا مرکز سالونیکا(یورپی ترکی) میں قائم ہوا۔ کمال اتاترک سالونیکا کے اسی فوجی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔
حمیدی دور میں سرکاری طورپر تین رحجانات کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ 1۔ روایتی اندازِ فکر۔2۔ مغربی خیالات کی شدت سے مخالفت۔3۔ اتحادِ اسلام۔ روایت پرست حلقوں کاکام یہ تھا کہ ماضی کے کارناموں کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کریں، اسلاف پرستی کو ہوا دیں، مناظرے کا لٹریچر شائع کریں اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت کریں کہ سلطان کی اطاعت مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے۔ خالدہ ادیب خانم لکھتی ہیں کہ اس گروہ نے سرکاری خرچ پر بے شمار کتابیں اور رسالے شائع کیے اور کتب فروشی کی دکانیں ان کے لٹریچر سے بھر گئیں مگر پڑھنے والوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا البتہ مانگ اگر تھی تو اس خفیہ لٹریچر کی جو چوری چھپے یورپ سے آتا رہتا تھا۔ مغربی علوم و افکار کے خلاف مہم دو متوازی خطوط پر چلائی گئی۔ اول یہ ثابت کرنا کہ مغربی علوم اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں لہذا مسلمانوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ مغربی خیالات کی روک تھام کے لیے اخباروں کو ہدایت کردی گئی کہ مغربی پارلیمنٹوں کی رُوداد ہر گز نہ چھاپیں، وہاں کی سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کا بھُولے سے بھی ذکر نہ کریں اور وہاں حکومت میں جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ان کی خبریں یا جلسوں، جلوسوں اور دہشت پسندوں کی خبریں بالکل شائع نہ کریں۔ اس کے علاوہ ” ماویئین اور طبیعون” کے ابطال کی طرف بھی خاص توجہ دی گئی اور ہرشخص کو دہریہ اور ملحد کہہ کر مطعون کرنے کی کوشش کی گئی جو اصلاح یا تبدلی کا خواہاں تھا۔ اس “فکری” مہم میں سید جمال الدین افغانی کی تحریریں بہت کام آئیں۔ اُنھوں نے ہندوستان کے قیام کے دوران 1878ء میں سر سید کے خلاف فارسی میں ایک کتاب ” ردِ نیچریہ” لکھی تھی۔ 1885ء میں محمد عبدہ نے اس کا عربی ترجمہ “الردالاالدہریون” کے نام سے بیروت سے شائع کیا (جو عثمانی سلطنت میں شامل تھا)” اس کتاب میں یونان کے ایٹمی فلسفیوں سے ڈارون تک، مزدک سے روسو تک، یہودیوں سے فری میسن تک، اسماعیلیوں سے مور منوں تک اور لبرل سیاست سے سوشلزم اور کمیونزم تک ہر فکر، ہر تحریک کو نیچری قرار دیا گیا تھا اور فتویٰ صادر کیا گیا تھا کہ “اس ملعون گروہ نے ہمیشہ مذہب اور معاشرے سے غداری کی ہے، خدا سے انکار کیا ہے اور قانون و اخلاق کو برباد کیا ہے۔”21 اس کتاب کا ترکی میں ترجمہ ہوا تو اس میں مدحت پاشا ، سلیمان پاشااور دوسرے ترقی پسندوں کے ناموں کا بھی (جو سزاپاچکےتھے)اضافہ کردیا گیا اور لکھا گیا کہ “ان غداروں کو انصاف پسند ہاتھوں نے وہ سزائیں دیں جن کے وہ مستحق تھے۔”
مغرب کی طرف دوسرا رویہ فاخرانہ اور سرپرستانہ تھا جو ان دنوں ہمارے ملک میں بھی بہت عام ہے یعنی اس بات پر بغلیں بجانا کہ ہزار برس پہلے مغرب کو تہذیب و تمدن کا درس ہم نے دیاتھا اور یہ دعویٰ کرنا کہ نظامِ شمسی ہو یا نظریہ ارتقا، برقی قوت ہو یا ایٹم بم، خلا میں پرواز ہو یا چاند کا سفر تمام سائنسی ایجادوں اور دریافتوں کا ذکر ہماری مقدس کتابوں اور علماء و حکماء کی تصنیفات میں پہلے سے موجود ہے لہذا ہم کو مغرب سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہاسبھائی ہندو بھی وید اور پُران کے حوالے سے اسی قسم کے بے بنیاد دعوے کرتے رہتے ہیں۔
رہا اتحادِ اسلام کا خوش آئند نعرہ سو اس کھلونے سے مسلمانوں کو بہلانے کی کوشش تقریباً دو سو سال سے ہو رہی ہے۔ بپولین 22 سلطان عبدالحمید، انگریز سیاست داں، مسولینی، فرانکو اور ہٹلر سب نے اسلام بے چارے کو باری باری تختہ مشق بنایا اور یہ مشغلہ ہنوز جاری ہے۔ جس صاحبِ اقتدار کو مسلمانوں کے جمہوری حقوق غضب کرنے ہوتے ہیں اس کی نگاہِ لطف و کرم کا پہلا شکار اسلام ہوتا ہے۔
اتحادِ اسلام اور احیائے اسلام کے تذکرے اگرچہ سلطان عبدالعزیز ہی کے عہد میں (1872ء) شروع ہو گئے تھے لیکن اس کو سیاسی حربے کے طور پر سلطان عبدالحمید نے استعمال کیا۔ اس کا خیال تھا کہ شام ، لبنان، فلسطین، البانیہ، نجد، عراق اور یمن میں خود مختاری کی جو تحریکیں چل رہی ہیں اور خود ترکوں میں حکومت سے جو نفرت پھیل رہی ہے اس پر اتحادِ اسلامی کے نعروں کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے اور خارجی سیاست میں بھی اس حربے سے کام لیا جا سکتا ہے کیوں کہ ہندوستان، مصر، سوڈان، ترکستان، الجزائر، لیبیا اور تونس وغیرہ میں جو کروڑوں مسلمان برطانیہ، فرانس اور زار روس کے زیرِ نگیں تھے اُن کی نظر میں سلطنتِ عثمانیہ دنیا میں لے دے کر ایک ہی آزاد اسلامی مملکت باقی بچی تھی لہذا مسلمانوں کو اس مملکت سے بڑا جذباتی لگاؤ تھا۔ ہندوستان میں تو نمازِ جمعہ کا خطبہ سلطان کے نام سے پڑھا جاتا تھا۔ ایسی صورت میں سلطان اگر اتحاد اسلام کا علم بردار بن کر سامنے آئے تو مسلمان سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں سلطان کا ضرور ساتھ دیں گے ۔
سلطان عبدالحمید ایک طرف اتحادِ اسلام کا نعرہ لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں سامراجی طاقتوں کا دشمن ہوں اور دوسری طرف اس نے ملک کی ساری معیشت سامراجی طاقتوں ہی کے پاس رہن رکھ دی تھی۔ چنانچہ 1882ء میں ریلوے لائن، ٹیلی گراف لائن اور بندرگاہوں اورپُلوں کے تمام ٹھیکے انگریزوں ، فرانسیسوں اور جرمنوں کو دے دیے گئے۔ معدنیات اور بینکوں پر یورپی ساہو کاروں کا قبضہ ہو گیا اور ریاست کی مالیات کا ساراانتظام ان کے حوالے کردیا گیا۔ سامراجی تسلط کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ قرضوں پر جو سُود واجب الادا تھے فقط ان کی وصولی پر نو ہزار افراد ملازم تھے جو سب کے سب عیسائی اور یہودی تھے۔ اس کے علاوہ سلطان نے مغربی طاقتوں کا یہ مطالبہ بھی تسلیم کرلیا تھا کہ کسی ملکی یا غیر ملکی عیسائی یا یہودی پر ترکی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چل سکے گا۔ مغربی طاقتوں نے ترکی کے اندر اپنی آزاد ریاست قائم کی لی تھی۔
آخرکار حالات اتنے ناقابلِ برداشت ہو گئے کہ جولائی 1907ء میں فوج کی تیسری کور نے جس میں کمال اتاترک بھی شامل تھے بغاوت کردی۔ سلطان عبدالحمید کو برطرف کردیاگیا۔ 1874ء کا آئین بحال ہوا۔ حکومت کی باگ ” نوجوان ترکوں” نے سنبھال لی اور نیا سلطان محمد شاد پنجم برائے نام سلطان رہ گیا۔
نوجوان ترکوں کے عہد میں (1908ء۔1919ء) ترکی کی فکر اور ترکی کی سیاست میں تین رحجان نمایاں ہوئے۔ 1۔ روایتی رُحجان جس کے بااثر ترجمان پرنس سعید حلیم پاشا تھے۔ ان کی رائے تھی کہ “اسلام کو جمہوریت کی ضرورت نہیں اور آئین لغوبات ہے۔” یہ حضرت 1913ء سے 1916ء تک ترکی کے صدرِاعظم رہے۔ ان کا دستِ راست مصطفیٰ صابری تھا جو 1918ء سے 1923ء تک شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز رہا۔ اسی نے کمال اتاترک اور ان کے رفقا پر کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا اور بالآخر انگریزوں سے مل گیا تھا۔ دوسرا گروہ توران پسندوں کا تھا جو عثمانی سلطنت کو نسلی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان تمام علاقوں کو جہاں ترک آبا د تھے (وسطی ایشیا اور مغربی ایران) ترکی کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس گروہ کے سرغنہ انور جمال پاشا تھے۔ تیسرا حلقہ نیشنلسٹوں کاتھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی کی بقا کی بس یہی صورت ہے کہ عربوں کے حق خود اختیاری کو تسلیم کرلیا جائے اور ترکی کی نئی ریاست کو خالص ترک وطنیت کی بنیادوں پر منظم کیا جائے۔ نیشنلسٹوں کا سیاسی مفکر اور نظریاتی ترجمان ضیا گو کلپ (1875ء۔1924ء) تھا۔ کمال اتاترک، عصمت انونو، خالدہ ادیب خانم، رؤف بے اور ڈاکٹر عدنان وغیرہ پر، جنھوں نے بعد میں انقلابِ ترکی کی رہنمائی کی ضیاءگوکلپ کے خیالات کا گہرا اثر تھا۔
ضیاءگوکلپ جنوب مشرقی اناطولیہ کے تاریخی شہر دیار بکر میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں نامق کمال اور توفیق فکرت کی تقلید میں شعر لکھتا رہا، پھر استنبول جا کر انجمنِ اتحاد و ترقی میں شامل ہوگیا اور صحافت کا پیشہ اختیار کرلیا۔ وہ جلد ہی اس نتیجے پر پہنچا کہ فقط سیاسی تبدیلیاں کافی نہیں بلکہ ترکی کو سماجی اور تمدنی انقلاب کی بھی ضرورت ہے۔ وہ مغربی تمدن کو اختیار کرنے کے حق میں تھا بشرطیکہ استمدن کو ترکی کی دو تاریخی روایات ترکی تہذیب اور اسلام سے ہم آہنگ کرلیا جائے۔ یعنی ترکی کا تمدن مغربی ہو، مذہب اسلام اور تہذیب خالص ترکی اور تینوں کو آپس میں گڈ مڈ کیا جائے۔
ضیاگوکلپ کا خیال تھا کہ روایت پرست حلقے تہذیب اور تمدن میں فرق نہیں کرتے حالاں کہ دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ تہذیب کسی قوم یا ملت کی سماجی قدروں کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ قومی یا ملی ہوتی ہے جب کہ تمدن نام ہے معاشرتی تنظیم اور سماجی اداروں کے مجموعے کا مثلاً نظم و نسق کے اصول، ضروریاتِ زندگی کے حصول کے طریقے، صنعت و حرفت، شہری حقوق، جمہوریت اور ملوکیت وغیرہ۔ تمدن معاشرے کا شعوری عمل ہے۔ اس کے برعکس تہذیب افراد کے شعوری عمل کا نتیجہ نہیں ہوتی نہ مصنوعی طورپر پیدا کی جا سکتی ہے۔ گوکلپ کے نزدیک کسی قوم کی تہذیب کی روح اس کی زبان ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ زبان کے حوالے سے تہذیب اورتمدن کے فرق کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ ” فقروں کی بناوٹ کے اصول اور افعال (کھانا ، پینا، سونا، جاگنا) تہذیب کی علامتیں ہیں جو افراد کی مرضی کے تابع نہیں البتہ اصطلاحیں مصنوعی ہوتی ہیں جو تمدن کی پیداوار ہوتی ہیں۔”
ضیاگوکلپ روایت پرستوں کے اس دعوے کو بھی تسلیم نہیں کرتا کہ اسلام ایک تمدن ہے اور یہ کہ مغربی تمدن اور عیسائیت ایک ہیں کیوں کہ مذہب کا کوئی تعلق تمدن سے ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمدن اخلاقی قدروں کا پابند نہیں ہوتا بلکہ واقعاتی حقیقت ہوتا ہے لہذا مغربی تمدن کا کوئی واسطہ مذہب سے نہیں ہے۔ مغربی تمدن ایک بین الاقوامی حقیقت ہے جو برطانیہ، فرانس ، جرمنی، امریکا ہر ملک میں برتا جاتا ہے البتہ فرانس، برطانیہ، اٹلی اور جرمنی کی تہذیبیں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔
ضیاگوکلپ کہتا ہے کہ اسلام نے ہم کو پوری آزادی دے رکھی ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کے پیشِ نظر جو تمدن چاہیں اختیار کریں۔ علمائے دین پر تنقید کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ حضرات جو شریعت کی بحالی پر اصرار کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اسلامی فقہ تمدنی معروضے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ قرونِ وسطیٰ کے تھیو کریٹک تمدن کی ضرورتوں کو پورا کرتی تھی۔ یہ حضرات اسلام کی آفاقی سچائیوں اور ان حقیقتوں کے درمیان فرق کرنے میں ناکام رہے ہیں جن کا تعلق اُمت کی وقتی ضرورتوں سے تھا۔ جدید تمدن صنعتی انقلاب کا آوردہ پروردہ ہے لہذا فقہ جو پرانے تمدن کی نمائندہ ہے جدید تمدن سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کو اُمت کے تصور کو بھی ملت کے ساتھ گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اُمت بین الاقوامی مذہبی جمعیت ہے جب کہ ملت کی بنیاد وطن ہے (ترک اور ایرانی دانش ور ملت کی اصطلاح کو قوم اور وطن کے معنی میں استعمال کرتے ہیں) وہ ترکوں کو ایک ملت قرار دیتا ہے اور اس ملت میں عربوں کو شامل نہیں کرتا اور نہ اُن ترکوں کو جو ترکی کی حدود سے باہر ترکستان یا ایران میں آباد ہیں کیوں کہ ضیاگو کلپ کے نزدیک ملت کی بنیاد نسل نہیں ہے بلکہ وطنی تہذیب ہے۔
ضیاگو کلپ آخر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ترکوں کو عربی اور ایرانی تہذیبوں سے کنارہ کش ہو کر ترکی کی نئی تہذیب کو ترکی زبان اور ترکی لوک ادب کی بنیادوں پر فروغ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ترکوں کا مذہب اسلام ہو گا اور تمدن مغربی۔
” ہم کو مغربی تمدن کو اپنا لینا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو مغربی طاقتیں ہم کو اپنا غلام بنا لیں گی۔ ہم کو دو میں ایک کو چُننا ہے: مغربی تمدن پر پورا عبور یا مغربی طاقتوں کا مکمل غلبہ، مغربی تمدن عبارت ہے سائنسی علوم سے، جدید صنعتی تکنیک سے اور سماجی تنظیمات سے (جمہوریت، شہری حقوق، پارلیمانی انتخابات، ذمہ دار حکومت) یورپ اپنی تمدنی فوقیت ہی کہ وجہ سے مسلمان قوموں کو شکست دینے میں کامیاب ہوا اور دنیا کا آقا ہوگیا۔”23
“نوجوان ترکوں” نے 1908ء میں جس وقت سلطان عبدالحمید کو برطرف کر کے ملک میں آئینی حکومت قائم کی تو انجمنِ اتحاد و ترقی میں اتحادِ اسلام کے داعی، توران پسند اور نیشنلسٹ تینوں عناصر شامل تھے مگر جنوری 1913ء میں انور پاشا ، طلعت پاشا اور جمال پاشا نے جوا تحادِ اسلام اور تورانیت کے سرغنہ تھے تمام اختیارات خود سنبھال لیے، قومی اسمبلی توڑ دی جس میں نیشنلسٹوں کی اکثریت تھی ( وہ یورپ کی سامرجی سیاست میں کسی فریق کا ساتھ دینے کے خلاف تھے) جرمنی کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر لیااور جنگ چھِڑی تو جرمنی کی طرف سے جنگ میں شریک ہو گئے۔
جنگ میں شریک ہو کر ترکی کی قیادت نے بڑی عاقبیت نا اندیشی کا ثبوت دیا۔ انور پاشا اور اس کے رفیقوں کو امید تھی کہ فتح کے بعد جرمن حکومت روسی ترکستان، مصر، لیبیا، تونس اور الجزائر کو اِتحادی طاقتوں سے چھین کر ترکی کے حوالے کردے گا۔ وہ اس غلط فہمی میں بھی تھے کہ مغربی مقبوضات کے مسلمان ترکی کے حق میں بغاوت کردیں گے اور سلطنت کے عرب مسلمان ترکوں سے پورا پورا تعاون کریں گے لیکن ترکی حکومت کی یہ خواہشیں پوری نہ ہوئیں اور جب شکست ہو گئی تو انورپاشا اور اس کے رفقا ترکی حکومت کی یہ خواہشیں پوری نہ ہوئیں اور جب شکست ہو گئی تو انورپاشا اور اس کے رفقا ترکی کو اس کے حال پر چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گئے اور حکومت پر سلطان کا قبضہ ہوگیا۔ برطانوی فوجوں نے استنبول پر قبضہ کرلیا اور سلطان انگریزوں کا تابع ہوگیا۔ مشرقی اناطولیہ کے ارمنی علاقے کو آزاد ریاست کا درجہ دے دیا گیا اور یونانی فوجوں نے اسمرنا کے مقام پر اتر کر قتل عام شروع کردیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ سلطان نے ترکی فوجوں کو جو اناطولیہ میں بکھری ہوئی تھیں ہتھیار ڈال دینے کا حکم دے دیا۔ تب حُریت پسند ترکوں کی غیرت و حمیت نے نے جوش مارا۔ ان کی آزادی، ان کا قومی وجود، ان کی زندگی سب خطرے میں تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ عورتیں مرد، جوان بوڑھے، شہری ، دیہاتی، ہتھیار بند اور نہتے۔ حُب الوطنی کے اس جوش ، اس ولولے کی قیادت کمال اتاترک نے کی۔ وطن فروش سلطان نے جو سامراجی طاقتوں کے ہاتھ میں کٹھ پُتلی تھا، کمال اتاترک، علی فواد پاشا، ڈاکٹر عدنان بے اور ان کی مجاہد بیگم خالدہ ادیب خانم سمیت سات رہنماؤں کو ان کی غیر حاضری پر موت کی سزا دے دی مگر موت کے فرشتے ان کا بال بیکانہ کرسکے۔ شیخ الاسلام نے فتویٰ صادر کیا کہ جو شخص ان ساتوں کو قتل کرے گا اس کو جنت میں انعام ملے گا لیکن کوئی ترک شیخ الاسلام کی جنت میں جانے پر راضی نہ ہوا۔ آزادی کی جنگ دو سال تک جاری رہی۔ یونانی فوجوں نے شکست کھائی۔ اتحادی فوجیں اطاطولیہ، استنبول اور سالونیکا سے واپس جانے پر مجبور ہوئیں۔ سلطان نے برطانوی جنگی جہاز میں پناہ لی اور مالٹا بھاگ گیا۔ انقلابِ ترکی کا سرخ پرچم سُرخ رُو ہوا۔ کمال اتاترک جمہوریہ ترکی کے صدر منتخب ہوئے اور تب قومی اسمبلی نے نومبر 1922ء میں اتفاقِ رائے سے بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کردیا۔ 2 اگست 1923ء کو نئی مجلسِ آئین ساز منتخب ہوئی۔ اکتوبر 1923ء میں نیا آئین منظور ہوا۔ مارچ 1924ء میں اسمبلی نے خلافت کا عہدہ منسوخ کردیا اور مذہب کو ریاست سے الگ کرنے کی غرض سے متعدد قانون منظور کیے۔ شیخ الاسلام کا عہدہ توڑ دیا گیا اور امورِ مذہبی کا شعبہ وزیرِاعظم کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اوقاف کی زمینوں کو قومی ملکیت قرار دے دیاگیا۔ ترکی کی نئی ریاست سیکولر ہو گئی چنانچہ ترکی کے نئے آئین میں وضاحت کردی گئی کہ:
“ترکی ری پبلک ایک نیشنلسٹ، جمہوری، سیکولر اور سوشل ریاست ہے جس پر انسانی حقوق پر مبنی قانون کی حاکمیت ہے۔” (دفعہ2)
آج کل تو خیر سے ہم نے ہیرو سازی کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں لیکن بیسوی صدی کی دوسری اور تیسری دہائی میں دنیائے اسلام کی سب سے ہر دل عزیز شخصیت کمال اتاترک کی تھی۔ وہ انقلابِ ترکی کے قائد اور جدید جمہوریہ ترکی کے بانی ہی نہ تھے بلکہ پورے مشرق کی آبرو سمجھے جاتے تھے۔ اُنھوں نے مغربی طاقتوں کو شکست دی تھی۔ لہذا محکوم ملکوں کے لوگ ان کے کارناموں میں اپنی خواہشوں کا عکس دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے میں ان کی اصلی اور فرضی تصویریں پنواڑیوں، درزیوں، حجاموں اور خوردہ فروشوں کی دکانوں میں لٹکی رہتی تھیں۔ اخباریین طبقہ ترکی کے حالات بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ مقررین جلسوں میں بہادر ترکوں کی سرفرشیوں کا ذکر کر کے حاضرین کو جوش دلاتے تھے۔ ترکی ادیبوں کی تحریریں ہمارے رسالوں کی زینت بنتی تھیں اور برصغیر کا شاید ہی کوئی ممتاز اہلِ قلم تھا جس نے جدید ترکی کا خیر مقدم نہ کیا ہو۔ کمال اتاترک کے انقلابی اقدامات سے علامہ اقبال بھی بہت متاثر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ترکی میں ایک نیا انسان پیدا ہو رہا ہے اور ترکوں کی بیداری تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے حیاتِ نو کا مژدہ ثابت ہوگی۔ ان کی آخری دنوں کی ایک نظم ” غلاموں کی نماز” ہے جس میں اُنھوں نے ترکوں کی روشن خیالی کو خوب سراہا
کہا مجاہدِ ترکی نے مجھ سے بعدِ نماز
طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمھارے امام
وہ سادہ مردِ مجاہد، وہ مومنِ آزاد!
خبرنہ تھی اسے کیا چیز ہے نمازِ غلام
ہزار کام ہیں مردانِ حُر کو دنیا میں
انھیں کے ذوقِ عمل سے ہیں اُمتوں کے نظام
بدن غلام کا سوزِ عمل سے ہے محروم
کہ ہے مرورغلاموں کے روز و شب پہ حرام
طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے
دُرائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام
خطباتِ مدراس میں جدید ترکی کے تاریخی کردارپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
“سچ تو یہ ہے کہ دورِ حاضرکی مسلم قوموں میں فقط ترکی نے اعتقاد کی نیند کو جھٹک دیا ہے اور شعورِ ذات حاصل کرلیا ہے۔ ترکی واحد ملک ہے جس نے ذہنی آزادی کے حق کا دعویٰ کیا ہے۔ ترکی جانتا ہے کہ حرکت کرتی اور پھیلتی ہوئی زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگیاں یقیناً نئے حالات پیدا کریں گی اور نئے نقطہ ہائے نظر کی دعوت دیں گی اور ان اصولوں کی ازسرِ نو تفسیر کی متقاضی ہوں گی جو روحانی کُشادگی کی مسرت سے ناآشنا حضرات کے لیے فقط مجلسی دل چسپی کا باعث ہوتے ہیں۔ میراخیال ہے کہ وہ انگریز مفکر ہابس تھا جس نے یہ بلیع بات کہی تھی کہ ہو بہو یا یکساں خیالات و جذبات کی متواتر تکرار کے معنی تو یہی ہوئے کہ خیالات ہیں نہ جذبات۔ فی زمانہ مسلمان ملکوں کا یہی حال ہے۔ وہ میکانکی طورپر پرانی قدروں کو دہرائے جارہے ہیں جب کہ ترکی نئی قدروں کی تخلیق پر آمادہ ہے۔ اس کی زندگی حرکت کرنے، بدلنےاور پھیلنے لگی ہے۔اس میں نئی خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں جو اپنے ہمراہ نئی دشواریاں لاتی ہیں اور نئی تشریحوں کی دعوت دیتی ہیں۔”24
کیا سیکولرازم کی اس سے بہتر تشریح ممکن ہے۔ مگر ہماری قوم اتنی طویل سجدہ ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتیں۔ نہ مرحلہ شوق کی جستجو باقی رہی ہے نہ ہر لحظہ نئے طُور اور نئی برقِِ تجلی کی آرزو۔ نہ موجِ تحقیق سے دریا میں تلاطم پیدا کرنے کا حوصلہ ہے اور نہ اپنے اعجارِ ہنر سے فطرت کو شرمندہ کرنے کا ولولہ۔
کمال اتاترک نے ترکی کو ایک ترقی پسند اور ترقی پذیر مملکت بنانے کی پوری کوشش کی۔ اس نے وہ تمام مراعات منسوخ کردیں جو سامراجی طاقتوں کو ترکی میں حاصل تھیں۔ ترکی میں سوئزر لینڈ کے نمونے پر سِول ضابطہ قوانین، اطالوی نمونے پر فوجداری ضابطہ قوانین اور جرمن نمونے پر تجارتی ضابطہ قوانین رائج کیے گئے۔ ترکی زبان کا رسم الخط عربی کے بجائے لاطینی ہوگیا۔ عورتوں کو مردوں کے برابر شہری حقوق ملے اور پردے کا رواج ختم ہوگیا۔ یورپ کے ” مردِ بیمار” نے بالآخر شفا پائی اور اس کا شمار دنیا کی معزز اور باوقار قوتوں میں ہونے لگا۔
مگر کمال اتاترک کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کے جانشینوں نے انقلابِ ترکی کے نصب العین کو بالائے طاق رکھ دیا۔ وہ ملک کو صنعتی اعتبار سے خود کفیل نہ بنا سکے۔ وہ یہ بھول گئے کہ مغربی تمدن کوٹ پتلون پہننے اور کانٹے چھری استعمال کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ مغربی تمدن کا انحصار جیسا کہ نامق کمال اور ضیاگوکلپ نے بار بار تنبیہہ کی تھی جدید صنعت و حرفت اور سائنسی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے پر ہے، شہری حقوق کو عام کرنے پر ہے، جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے پر ہے۔ ترکی کے نئے حکمرانوں نے ان فرائض کی بجا آوری کے بجائے یورپ کی فاشسٹ قوتوں سے ناتا جوڑا اور ترقی پسند عناصر پر تشدد کرنے لگے۔ ترکی ہٹلر کے گماشتوں کا اڈا اور سازشوں کا مرکز بن گیا۔ دوسری جنگِ عظیم میں فاشسٹوں کو شکست ہوئی تو ترکی سیاست نے امریکہ کی حلقہ بگوشی اختیار کرلی اور ترکی معیشت امریکہ کی فوجی اور مالی امداد کی دست نگر ہو گئی۔ اب ہر جگہ امریکہ کے فوجی اور ہوائی اڈے قائم ہیں اور ترکی کی خارجی اور داخلی پالیسی کا دامن امریکہ سے بندھا ہوا ہے۔ اسی عاقبت نا اندیشی کا نتیجہ ہے کہ ترکی گزشتہ چوتھائی صدی سے مسلسل سیاسی اور اقتصادی بحران میں مبتلا ہے۔ اقتدار پر فوج کا قبضہ ہے، شہری آزادی مفقود ہے، جمہوریت کا نام و نشان باقی نہیں اور سیکولرازم کے مخالفین کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔
(4)
برصغیر پاک و ہند کی تاریخ 27 مئی 1498ء کی وہ ساعت کبھی نہ بھولے گی جس وقت پرتگالی جہاز رانوں نے واسکوڈی گاما کی قیادت میں ساحل ملا بار پر لنگر ڈالے اور کالی کٹ کے راجہ زمورن سے تجارتی تعلقات قائم کیے۔ پرتگالیوں نے جلد ہی گواپر قبضہ کرلیا جو سلطنتِ بیجاپور کی اہم بندرگاہ تھی اور رفتہ رفتہ دمن، سایست، بسین، چول، بمبئی اور بنگال میں ہگلی کے بھی مالک ہو گئے۔ اُنھوں نے گوا میں اپنا پریس لگایا جس میں مذہبی کتابیں چھپتی تھیں اور لوگوں کو زبردستی عیسائی بنانے لگے۔ مقامی باشندوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک نہایت ظالمانہ تھا کیوں کہ ان کی آمد سے پیش تر بحرِ ہند کی تجارت صدیوں سے عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ بالآخر وہ اپنے تجارتی حریفوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے اور بحرِ ہند میں ان کا عمل دخل اتنا بڑھا کہ سولھویں سترھویں صدی میں مغل شہزادوں، شہزادیوں اور عمائدینِ سلطنت کو بھی حج و زیارت کے لیے پرتگالی جہازوں ہی میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود مغلوں کو اپنی بحری طاقت بڑھانے کا خیال نہ آیا نہ اُنھوں نے پرتگالیوں کی سیاسی ریشہ دوانیوں کو در خورِ اعتنا سمجھا۔ پرتگیز پادریوں نے چھاپے خانے کا نمونہ شہنشاہ اکبر کو دکھایا تھا مگر اُس دوراندیش فرماں روا نے بھی اس انقلابی ایجاد کی اہمیت و افادیت کو محسوس نہ کیا اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پریس لگا تو ہمارے خوش نویسوں کی روزی ماری جائے گی۔
انگریزوں نے پُرتگالیوں کے سو سال بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ اُنھوں نے 31دسمبر 1600ء کو لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ ان کا تجارتی نمائندہ، کپتان ہاکنس 1608ء میں یہاں آیا اور جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوا۔ مگر انگریزوں کو پانچ سال کی دوڑ دھوپ کے بعد 1613ء میں سُورت میں فیکٹری (تجارتی کوٹھی) کھولنے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ اُنھوں نے مغل بادشاہوں سے مختلف مراعات حاصل کرلیں اور احمد آباد، بھڑوچ، آگرہ، لکھنو، مسولی پٹم، ہگلی، قاسم بازار، پٹنہ اور مدراس میں بھی ان کی فیکٹریاں کُھل گئیں۔ رفتہ رفتہ اُنھوں نے شاہی دربار میں بھی رسوخ پیدا کرلیا۔ ڈاکٹر برنیئر اورنگ زیب کے عہد میں بارہ سال دہلی میں رہا۔ وہ نواب دانش مند خان کا طبیب تھا ۔ برنیئر کی سرگزشت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے نواب کو فرانس کے روشن خیال مفکروں بالخصوص ڈیکارٹ اورگے سندی کا فلسفہ بھی پڑھایا تھا مگر نئی روشنی کی یہ ٹِمٹماتی لَو برنیئر کے جاتے ہی بجھ گئی اور اس چراغ سے دوسرا کوئی چراغ نہ جلا۔
ایسٹ انڈیا کمپنی نے بمبئی اور مدراس میں قدم جمانے کے بعد جلد ہی محسوس کرلیا تھا کہ مرکزی حکومت کی کمزوری اور صوبوں کی خود مختار حکومتوں کی بد نظمیوں کی وجہ سے ملک میں جو ابتری پھیلی ہوئی ہے اس کے پیشِ نظر تجارت کے تحفظ و فروغ کے لیے سیاسی اقتدار حاصل کرنا نہایت ضروری ہے چنانچہ سرجارج آک زندن گورنر سورت نے 1669ء میں کمپنی کے ڈائریکٹروں کو مشورہ دیا تھا کہ ” حالات کا اب یہی تقاضا ہے کہ آپ اپنی تجارت کا انتظام بزورِ شمشیر کریں” اور کمپنی نے اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1687ء میں مدراس کے گورنر کو لکھا تھا کہ ” ایسی سِول اور فوجی حکومت قائم کی جائے اور دونوں شعبوں کی کفالت کے لیے اتنی آمدنی کا بندوبست کیا جائے جو ہندوستان میں ایک وسیع اور پائیدار برطانوی مقبوضے کی بنیاد بن سکے۔” واضح رہے کہ یہ یادداشت اس زمانے کی ہے جب شہنشاہ اورنگ زیب مدراس سے چند سو میل کے فاصلے پر دکن فتح کرنے میں مصروف تھا اور مغلیہ سلطنت بہ ظاہر متحدو مستحکم تھی۔
اورنگ زیب کی وفات کے بعد سلطنت کا شیرازہ جس طرح بکھرا اس کی عبرت ناک داستان سے ہر شخص واقف ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے پہلے حیدرآباد دکن کا رخ کیا اور وہاں درباری سازشوں کے ذریعے آصف جاہی خاندان کو ہمیشہ کے لیے اپنا تابعدار بنالیا۔ پلاسی اور بکسر کی لڑائیوں کے بعد کمپنی بنگال، بہار اور اڑیسہ کی بھی مالک ہو گئی اور 1765ء میں شاہ عالم ثانی (1759ء۔1804ء) نے فرمان کے ذریعے ان صوبوں کے دیوانی کے اختیارات کمپنی کو سونپ کر کمپنی کے قبضہ مخالفانہ کی توثیق بھی کردی۔ تسخیر ہند کا عمل شروع ہوگیا۔
اس بیرونی اقتدار نے یوں تو مقبوضہ علاقوں کی معاشرتی زندگی کے سب ہی شعبوں پر اثر ڈالا لیکن روایتی تہذیب و تمدن کے تین عناصر خاص طورپر متاثر ہوئے۔ 1۔ عدالتی نظام ۔2۔ تعلیمی نظام۔3۔ فکری اور اعتقادی نظام۔
مغلوں کے عہد میں حکومت کا نظم و نسق دیوانی اور نظامت دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ محکمہ دیوانی کے سپرد مال گزاری اور محصولات کی وصولی تھی اوران مقدموں کا فیصلہ جن کا تعلق وراثت، زمینوں کے جھگڑے، لین دین کے معاہدوں اور شادی بیاہ سے ہوتا تھا۔ دیوانی کے مالیاتی شعبوں میں اکثریت ہندو کائستھوں کی تھی جن کو فارسی آتی تھی اور جو حساب کتاب میں بھی ماہر تھے۔ مسلمان عموماً ان پیشوں کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ اس طرزِ عمل کا خمیازہ ان کو انگریزوں کے عہد میں بُھگتنا پڑا۔ دیوانی عدالتوں میں ہندوؤں کے مقدموں کے فیصلے دھرم شاستر کی رُو سے پنڈت کرتے تھے اور مسلمانوں کے فیصلے شریعت کے مطابق قاضی۔ ناظم دراصل صوبے کا گورنر ہوتا تھا۔ شاہی فوج اس کے ماتحت تھی۔ صوبے میں امن و امان قائم رکھنا، شاہی قوانین کو نافذ کرنا اور نظم و نسق کی نگرانی کرنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ فوجداری کے قوانین (قتل، ڈاکہ، چوری، بلوہ فساد وغیرہ) جو حنفی فقہ پر مبنی تھے ہندو مسلمانوں دونوں کے لیے یکساں تھے۔ لہذا فوجداری عدالتوں کے حاکم مسلمان ہوتے تھے اور فوجداری کے دوسرے محکموں میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہوتی تھی۔
جہاں تک تعلیمی نظام کا تعلق ہے اٹھارویں صدی میں ہندوستان کیا دنیا کے کسی حصے میں بھی رعایا کی تعلیم ریاست کی ذمہ داری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ہندوؤں کے راج میں راجے، مہاراجے اور دھن دولت والے پاٹھ شالوں کو جو عموماً مندروں سے ملحق ہوتے تھے زمینیں دان پن کردیتے تھے تاکہ پاٹھ شالوں کا خرچ چلتا رہے۔ ان کے علاوہ کاشی، متھرا، ہر دوار اور دوسری تیرتھ گاہوں میں بڑے بڑے ودوان پنڈٹ اور سادھو سنت بھی تھے جو اپنے چیلوں کو وید، پُران، بھگوت گیتا اور دھرم شاستر کی شِکسا دیتے تھے۔ مسلمان بادشاہوں کی پرانی روایت بھی یہی تھی۔ وہ ممتاز علما اور معلمین کو مکتبوں، مدرسوں کے مصارف کی خاطر ” مددِمعاش” کے طورپر زمینیں دے دیتے تھے۔ (ایک اندازے کے مطابق صوبہ ٹھٹھہ کی تقریباً ایک تہائی زمینیں علما کو مفت ملی ہوئی تھیں) علم دوست شہزادے اور امرا بھی اپنے خرچ سے مدرسے قائم کرتے رہتے تھے۔ صوفیائے کرام کے اپنے حلقے اور دائرے تھے جن میں مُریدوں کی تعلیم و تربیت اور کھانے رہنے کا انتظام مفت تھا۔ پہلا سرکاری مدرسہ سلطان شہاب الدین غوری نے 1191ء میں اجمیر میں قائم کیا تھا۔ پھر بختیار خلجی نے بنگال میں بہت سے مدرسے کھولے۔ سلطان التمش نے 1227ء میں اُچھ میں اور 1237ء میں دہلی میں مدرسے قائم کیے 25؎ مغلوں کے دور میں ملتان، ٹھٹھہ، سیالکوٹ، جون پُور، پٹنہ اور دہلی تعلیم کے بڑے مرکزتھے لیکن شاید ہی کوئی شہر یا بستی ایسی تھی جہاں مدرسے اور مکتب موجود نہ ہوں۔
مسلمانوں کے عہد میں ذریعہ تعلیم فارسی تھا۔ مکتبوں میں حروف ہجا کی پہچان سکھائی جاتی تھی۔ لکھنے کی مشق لکڑی کی تختیوں پر سرکنڈے کے قلم اور چاول گیہوں کو جلا کر گھر کی بنی ہوئی سیاہی سے ہوتی تھی لہذا تعلیم کے مصارف برائے نام تھے۔ حروف شناسی کے بعد بچوں کو بغدادی قاعدے کی گردانیں اور پارہ عم کی چند سورتیں یاد کرا دی جاتی تھیں اور فارسی کے کچھ مصاد رو الفاظ بھی پڑھا دیے جاتے تھے۔ شاید گلزارِ دبستان قسم کی کوئی آسان کتا ب تھی۔ مدرسوں کے نصاب میں جہاں اعلیٰ تعلیم کا انتظام تھا فقہ، اصولِ فقہ، بلاغتِ نحو، علم کلام، تصوف اور تفسیر کی کتا بیں داخل تھیں جو صدیوں پہلے ایران اور عراق میں لکھی گئی تھیں۔ زیادہ زور فقہ پر دیا جاتا تھا کیوں کہ عدالتوں میں ملازمت کے لیے فقہ سے واقفیت ضروری تھی۔ اکبر کے عہد میں جہاں اور بہت سی اصلاحیں ہوئیں وہاں پرانے تعلیمی نظام کے پہلو بہ پہلو سیکولر تعلیم رواج دینے کی کوشش بھی کی گئی۔ چنانچہ مفتی انتظام اللہ شہابی آئینِ اکبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اکبر کے عہد میں ایسی درس گاہیں بھی تھیں جن میں ” طالب علموں کو ریاضی، اخلاقیات، زراعت، مساحت، جیومیٹری، نجومیات، اصولِ حکومت، طب، منطق، کیمسٹری، طبیعات اور تاریخ کی تعلیم دی جاتی تھی۔”26
ڈاکٹر عابد حسین لکھتے ہیں کہ
” اکبر نے بہت سے سرکاری اسکول کھولے جن میں ہندو اور مسلمان لڑکوں کو ایک ساتھ فارسی میں تعلیم دی جاتی تھی۔ مضامین خالص سیکولر ہوتے تھے مثلاً منطق، اخلاقیات، جیومیٹری، طبیعات، طب، سیاسیات، تاریخ اور فارسی ادب۔”27
مگر سیکولر تعلیم کی پالیسی کو اکبر کے جانشینوں نے ترک کردیا اور روایتی تعلیم پھر سے رائج ہو گئی۔ البتہ اورنگ زیب کو مروجہ نصابِ تعلیم کی فرسودگی کا احساس تھا۔ اس کا اندازہ اورنگ زیب کی ایک تقریر سے ہوتا ہے جو اس نے اپنے سابق استاد کے رُو برو کی تھی۔ موصوف اورنگ زیب سے جب وہ بادشاہ ہوا تو اپنے حق استادی کا انعام مانگنے گئے تھے ۔ا ورنگ زیب نے ان کی جغرافیہ دانی اور کمالِ علمِ تاریخ کو پول کھولنے کے بعد کہا کہ:
” کیا استاد کو لازم نہ تھا کہ دنیا کی ہر ایک قوم کے حالات سے مجھے مطلع کرتا مثلاً ان کی حربی قوت سے، ان کے وسائلِ آمدنی اور طرزِ جنگ سے، ان کے روسم و رواج اور مذاہب اور طرزِ حکمرانی سے اوران خاص خاص امور سے جن کو وہ لوگ اپنے حق میں زیادہ مفید سمجھتے ہیں بہ تفصیل مجھ کو آگاہ کرتا اور علمِ تاریخ مجھے ایسا سلسلے وار پڑھاتا کہ میں ہر ایک سلطنت کی جڑ، بنیاد اور اسبابِ ترقی و تنزل اور ان حادثات و واقعات اور غلطیوں سے واقف ہو جاتا جن کے باعث ان میں ایسے بڑے بڑے انقلاب آتے رہے ہیں۔۔۔۔ اور باوجود یکہ بادشاہ کو اپنی ہمسایہ قوموں کی زبانوں سے واقف ہونا ضروری ہے بجائے ان کے آپ نے مجھ کو عربی لکھنا پڑھنا سکھایا اگرچہ اس زبان کے سیکھنے میں میری عمر کا ایک بڑا حصہ ضائع ہوا۔۔۔۔۔ آپ نے بغیر یہ سوچے کہ ایک شہزادے کو زیادہ ترکن کن علوم کی ضرورت ہے فقط صرف و نحو اور ایسے فنون کی تعلیم کو جو ایک قاضی کے لیے ضروری ہیں مقدم جانا اور ہماری جوانی کے ایام کو بے فائدہ اور لفظی بحثوں کے پڑھنے پڑھانے میں ضائع کیا۔”28
مگر افسوس ہے کہ مُلا نظام الدین سیوہالوی نے جو نصابِ تعلیم سلطان ذی فہم کے حکم سے مرتب کیا (درسِ نظامی) اس میں اُن علوم کا ذکر تک نہیں جن کی افادیت پر سلطان نے اپنی تقریر میں زور دیا تھا بلکہ اُنھیں علوم پر اصرار کیا گیا جن پر سلطان معترض تھا۔ مثلاً منقولات میں تجوید اور قرات، تفسیر، حدیث، فقہ اور اصولِ فقہ، فرائض (وراثت ) کلام اور تصوف، معقولات میں صرف و نحو، بلاغت، عروض، منطق، حساب، ہیئت، حکمت اور مناظرہ۔ مفتی انتظامِ اللہ شہابی اس نظام تعلیم کے بڑے ثنا خواں ہیں مگر ان کو بھی دبی زبان سے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ” ہر چند کہ اسلام نے قرونِ وسطیٰ میں عظیم مفکر اور سائنس داں پیدا کیے مگر (درسِ نظامی) ان علوم کی عدم موجودگی حیرت انگیز ہے۔ اسلام کے ممتاز مفکر۔۔۔۔ الکندی، الفارابی، ابنِ سینا، البیرونی اور ابنِ رشد وغیرہ سرے سے غائب ہیں۔” لطف یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں ابھی تک اسی قسم کا فرسودہ نصاب رائج ہے۔
اسلامی مفکر میں جمود کا بنیادی سبب تو یہ تھا کہ خود مسلم معاشرہ جمود کا شکار ہوگیا تھا۔ تلاش و تحقیق، تجربہ اور مشاہدہ، اجتہادی تفکر اور نامعلوم کرنے کے شوق کی پرانی روایت کو علمائے دین اور صوفیائے کرام نے نہ صرف ترک کردیا تھا بلکہ قرونِ وسطیٰ کے روشن خیال مسلمان مفکروں کو کافر، ملحد اور زندیق کے لقب سے نوازتے تھے اور ان کی تصنیفات کا مطالعہ ممنوع کردیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اربابِ علم منقولات کی دلدل میں ایسے پھنسے کہ پھر کبھی نکل نہ سکے۔ بس مکھی پر مکھی مارتے رہے۔ پرانی کتابوں کی شرحیں اور حاشیے لکھتے رہے بلکہ حاشیوں پر حاشیے۔ نہ اپنی بصیرت و آگہی میں اضافہ کیا نہ بد نصیب قوم کی اور بقول اقبال یہ اُمت خرافات میں کھو گئی۔ چنانچہ گزشتہ سات سو سال کے طویل عرصے میں مسلمان حکومتوں کی سر پرستی کے با وصف کسی بزرگ کے قلم سے ایسی ایک طبعِ زاد تصنیف بھی نہ نکلی جس کو ہم آج دنیا کے سامنے فخر سے پیش کرسکیں۔ اس “لوچہ زُہاد” سے اگر کوئی ثابت نکلا ہے تو وہی “رندانِ قدح خوار” جن کا شعری کلام ہنوز زندہ ہے۔ تاریخ کی کتابیں بے شمار لکھی گئیں لیکن ان کو لکھنے والے بھی فلسفہ تاریخ سے بابلد تھے۔ وہ وقائع نویس ہیں نہ کہ مورخ۔ ان کو ابنِ خلدون کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔ کیا عجیب کہ اُنھوں نے ابنِ خلدون کا نام بھی نہ سنا ہو۔
شاہ عالم نے دیوانی اختیارات کمپنی کو سونپتے وقت چوں کہ یہ شرط رکھ دی تھی کہ صوبوں کے نظم و نسق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یعنی دفتری زبان فارسی ہوگی اور عدالتوں کا پرانا نظام بھی بدستور قائم رہے گا لہذا گورنر جنرل وارن ہسٹینگز(1774ء۔1785ء) کو ایسے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی فوراً ضرورت پڑی جو ملکی قوانین سے بخوبی واقف ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنی یادداشت میں لکھا کہ:
” ہماری پالیسی ہے کہ دیوانی اور فوجداری کی اہم اسامیوں پر اور پولیس کے عہدوں پر مسلمانوں کو مقرر کیا جائے۔ یہ فرائض عربی اور فارسی زبانوں او ر اسلامی قوانین کی ٹھوس اور جامع لیاقت ہی سے ادا ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ علوم اور علما آہستہ آہستہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم اقتدار کے زوال کے بعد مسلمان خاندان تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو تعلیم دینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔” 29
وارن ہسٹینگز نے ” ان اسباب کی بنا پر 1781ء میں مدرسہ عالیہ (کلکتہ مدرسہ) قائم کیا تاکہ مسلمانوں کو نظم و نسق میں شرکت کا پورا پورا موقع ملے۔” اس نے ضلع 24 پرگنے کی کچھ آراضی بھی مدرسے کے مصارف کے لیے مخصوص کردی۔
وارن ہسٹینگز ہندوستان میں عرصے سے مقیم تھا۔ وہ فارسی زبان پر پورا عبور رکھتا تھا اور مشرقی علوم والسنہ کا بڑا دل دادہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ برطانوی طرزِ حکومت اور ہندوستانی تہذیب میں کسی نہ کسی طرح مفاہمت اور ہم آہنگی پیدا کی جائے تاکہ کمپنی کو اپنے مقاصد کے حصول میں دشواری نہ ہو۔ اُن دنوں اتفاق سے کمپنی کے اعلیٰ عہدے داروں میں بھی ایک حلقہ ایسا تھا جو وارن ہسٹینگز کے خیالات سے اتفاق کرتا تھا اور مشرقی علوم اور زبانوں سے گہری دل چسپی رکھتا تھا۔ مثلاً سرولیم جونس جج سپریم کورٹ، سرچارلس وِل کِنس، نَے تَھے نیل ہال ہیڈ، سرجان شور جو بعد میں گورنر جنرل ہوا، فران سِس گلیڈون، جان کارناک، جان گِل کرسٹ، جوناتھن ڈن کن اور ولیم چَیم برس وغیرہ۔
سرولیم جونس 1783ء میں سپریم کورٹ کا جج ہو کر کلکتہ آیا اور دس سال بعد 47 سال کی عمر میں وہیں وفات پاگیا۔ اس نے ہندوستان آنے سے پہلے ہی عبرانی، یونانی، لاطینی، عربی، فارسی، فرانسیسی، ہسپانوی، اطالوی، جرمن، ترکی اور چینی زبانوں میں مہارت حاصل کرلی تھی۔ یہاں آکر اس نے سنسکرت بھی سیکھ لی اور اپنے لسانی نظریوں کی بدولت دنیا میں بڑا نام پیدا کیا (اس نے زبانوں کے تقابلی مطالعے سے یہ ثابت کیا کہ سنسکرت فارسی اور یورپین زبانیں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں) اس نے فقہ کی کتاب “السر آجیہ” اور دھرم شاستر کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا اور 1784ء میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال قائم کی جو اب تک موجود ہے۔ سوسائٹی کا مقصد اس کے بقول “انسان اور نیچر اور نیچر جو کچھ ایشیا میں پیدا کرتا ہے اور انسان جو کچھ محنت سے تخلیق کرتا ہے اس کا مطالعہ اور تحقیق تھا۔” 30
سر چارلس وِل کنس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بنگالی، اردو اور ناگری کے ٹائپ بڑی محنت و کاوش سے خود تیار کیے۔ فورٹ ولیم کالج کی اردو کتابیں اسی کے بنائے ہوئے نستعلیق ٹائپوں پر چھپتی تھیں۔ سرچارلس اور دوسرے مستشرقین نے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا، ادب، گرامر، لغت، قانون، تاریخ، فقہ اور مذہب کی بہ کثرت کتابیں فارسی، عربی اور سنسکرت سے انگریزی میں ترجمہ کیں اور یہاں کے معاشرتی حالات کے بارے میں انگریزی میں طبع زاد کتابیں بھی لکھیں۔
وارن ہسٹینگز اور سر ولیم جونس وغیرہ کی مشرقی علوم اور زبانوں سے دل چسپی فقط کمپنی کی انتظامی ضرورتوں کا تقاضا نہ تھی بلکہ یہ دل چسپی اٹھارویں صدی کے انقلابی عہد میں اہلِ مغرب کا مزاج بن گئی تھی۔ پرنگالی، برطانوی، فرانسیسی کمپنیوں کی تجارتی سرگرمیوں کے تذکروں نے مشرقی منڈیوں کی تلاش میں ان کمپنیوں کے گماشتوں کی دوڑ دھوپ کی داستانوں نے، سیاحوں اور طالع آزماؤں کے سفر ناموں، مشرق کی دولت مندی کے چرچوں نے اور یہاں کی پُر اسرار تہذیب کی جھوٹی سچی حکایتوں نے مغرب کے دلوں اور دماغوں کو مسحور کردیا تھا۔ فارسی کی تقلید میں گوئٹے کا ” دیوان” شیلی کی ” اسلام کی بغاوت” بائرن کی نظمیں، سوئفٹ کا ” گلی ورکاسفر” (1726ء) رابن سن کروسو کے تجربات، رمبراں اور گویا کی تصویریں، والٹیئر کے افسانے اور فرانسیسی روشن خیالوں کی تصنیفات میں اسلامی مفکرین کی تحسین و تعریف غرضیکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا یورپ والوں کو ایک نئی دنیا ایک نئی حقیقت کا انکشاف ہوگیا ہے۔ وارن ہسٹینگز، سرولیم جونس اور کمپنی کے بیش تر حکام اسی مشرق زدہ ذہنیت کے پروردہ تھے۔ اٹھارویں صدی میں کمپنی کی انتظامی پالیسی پر انھیں عناصر کا غلبہ رہا۔
لیکن ان ” اورینٹلسٹوں” کے مقابل کمپنی کے ملازمین میں ایک حلقہ ان افراد کا بھی تھا جو ہندوستانیوں کو انگریزی زبان اور ولایتی تہذیب کے ذریعے ” مہذب” بنانے پر مُصر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں برطانوی قوانین نافذ ہوں، یہاں کی سرکاری زبان انگریزی کردی جائے اور اسکولوں میں انگریزی پڑھائی جائے۔ ان خیالات کا اظہار سب سے پہلے کمپنی کے ایک افسر چارلس گرانٹ نے کیا۔ اس کی رائے میں ” سماجی برائیاں اور اخلاقی خرابیاں نتیجہ میں گہری جہالت او ر وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی لا علمی کا اور یہ نقص انگریزی تعلیم ہی سے دور ہو سکتا ہے۔” اس کی بات جب یہاں کسی نے نہ سنی تو اس نے انگلستان جا کر اپنی تجویزیں کمپنی کے ڈائریکٹوں کے رُو برو پیش کیں مگر کمپنی ڈائریکٹر بھی ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم دلوانے کے سخت خلاف تھے چنانچہ 1792ء جب انگریزی کے ٹیچروں کو ہندوستان بھیجنے کی تجویز رکھی گئی تو ایک ڈائریکٹر نے کہا کہ ” ہم اپنی حماقت سے امریکا میں اسکول اور کالج کھول کر ملک کھو چکے ہیں اور اب ہم اس حماقت کو ہندوستان میں دہرانا نہیں چاہتے۔”31
البتہ انگریزی پادری اور انگریزی زبان کے اخبار، جو وارن ہسٹینگز کے سخت مخالف تھے انگریزی زبان کی ترویح و اشاعت کے حق میں تھے۔ پادریوں کا انگریزی زبان میں تعلیم دینے کا تجربہ بمبئی اور مدراس میں کامیاب ہو گیا تھا لہذا اُنھوں نے بنگال میں بھی جگہ جگہ اپنے اسکول کھولے، چھاپے خانے قائم کیے اورتبلیغی کتابیں شائع کرنےلگے۔ اُنھوں نے سی رام پور میں کاغذ سازی کا کارخانہ بھی قائم کیا۔ یہ کاغذ سستا اور اچھا ہوتا تھا اس لیے اخباری ضروریات کے موزوں تھا۔ پادری انگریزی زبان کے ساتھ مغربی علوم کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ مسلمانوں نے جو بجا طور پر انگریزوں سے ناراض تھے اوران کے ہر اقدام کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے مشن اسکولوں میں پڑھنا یا انگریزی سیکھنا گوارا نہیں کیا مگر ہندو لڑکے انگریزی اسکولوں میں پڑھنے لگے۔ یہ تعلیم آگے چل کر ان کے بہت کام آئی اور وہ مسلمانوں پر سبقت لے گئے۔
اخبار کو معاشرے کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے کیوں کہ لوگوں کے سیاسی اور سماجی شعور کی تشکیل میں اخبار بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جابر حکمراں پریس سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں اور سب سے پہلے پریس کی آزادی سلب کرتے ہیں۔ ہندوستان میں پہلا اخبار جو انگریزی میں تھا 1780ء ہکی نامی ایک انگریز نے کلکتہ سے شائع کیا تھا۔ اس ہفتہ وار اخبار کا نام “بنگال گزٹ” تھا (اس سے پہلے ایسٹ اندیا کمپنی نے سرکاری طورپر ایک انگریزی اخبار” انڈیا گزٹ” کے نام سے 1774ء میں جاری کیا تھا مگر اس میں فقط کمپنی کی خبریں چھپتی تھیں) ہِکی ایسٹ انڈیا کمپنی اور اُس کے ملازمین کا جانی دشمن تھا اور ان کی سیہ کاریوں اور زراندوزیوں کے قصے خوب نمک مرچ لگا کر بیان کرتا تھا۔ اسی کی پاداش میں وہ دو بار قید ہوا اور بالآخر ملک بدر کردیا گیا۔ بنگال گزٹ کے بعد جلد ہی کلکتہ، بمبئی اور مدراس سے تقریباً ایک درجن ہفت روزہ انگریزی اخبارات شائع ہونے لگے۔ ان اخباروں میں ہندوستان کے علاوہ سمندر پار کی خبریں بھی چھپتی تھیں جو لندن سے آنے والے اخباروں سے نقل کی جاتی تھیں۔ ” انگریزی اخباروں کے اجرا سے ہندوستانیوں میں اخبار بینی کا شوق اور اخبار نویسی کا مذاق پیدا ہوا۔” اور وہ بین الاقوامی حالات سے بھی واقف ہونے لگے ( یادرہے کہ یہ زمانہ انقلابِ فرانس کا تھا)۔
وارن ہسٹینگز اور لارڈ کارنوالس کے زمانے میں اگرچہ اِکا دُکا آزاد خیال انگریز ایڈیٹروں پر سختیاں ہوئیں اور وہ ملک بدر کیے گئے لیکن پریس آزاد رہا مگر لارڈویلزلی نے انقلابِ فرانس کے حالات سے خوف زدہ ہوکر خود اپنے ہم وطنوں کے پریس کی آزادی چھین لی اور 1799ء میں سخت سنسر شپ نافذ کردی۔ انگریز ایڈیٹروں نے بہتیرا احتجاج کیا اور پارلیمنٹ میں سنسر شپ کے خلاف تقریریں بھی ہوئیں مگر سنسر شپ قائم رہی البتہ لارڈ ہسٹینگز (1813ء۔1833ء) نے 1817ء میں سنسر شپ ختم کردی۔ تب ہندوستانیوں کو بھی دیسی زبانوں میں اخبار جاری کرنے کا حوصلہ ہوا۔ سب سے پہلے دیسی اخبار بنگلہ زبان میں نکلے اوران کی تعداد میں بہت جلد اضافہ ہوگیا۔ چنانچہ 1830ء میں کلکتہ سے بنگلہ کے تین روزنامے، ایک دو روزہ، دو تین روزہ، سات ہفت روزہ، دو پندرہ روزہ، ایک ماہانہ پرچے شائع ہوتے تھے۔32
فارسی میں پہلا اخبار 1822ء میں شائع ہوا اور اردو میں ایک سال بعد۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ فارسی کے پہلے اخبار ” مراۃ الاخبار” کے مالک و ایڈیٹرراجہ رام موہن رائے اور اردو کے پہلے اخبار ” جامِ جہاں نُما” کے ایڈیٹر و مالک منشی سدا سُکھ دونوں غیر مسلم تھے۔ راجہ رام موہن رائے نے ” مراۃ الاخبار” کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ انگریزوں کے اخبار تو موجود ہیں مگر
“ان سےوہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو انگریزی سے واقف ہیں لیکن ہندوستان کے سب حصوں کے لوگ انگریزی نہیں جانتے۔ جو انگریزی نے نابلد ہیں وہ یا تو انگریزی دانوں سے اخبار پڑھوا کر سنتے ہیں یا خبروں سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ اس خیال سے مجھ حقیر کو فارسی میں ایک ہفتہ وار اخبار جاری کرنے کی خواہش ہوئی ہے۔ دیسی برادری کے سب معززین اس زبان سے واقف ہیں۔ اس اخبار کی ذمہ داری لینے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ عامتہ الناس کے سامنے ایسی چیزیں پیش کی جائیں جن سے ان کے تجربوں میں اضافہ اور ان کی معاشرتی ترقی ہو سکے۔ اربابِ حکومت کو رعایا کا صحیح حال بتلایا جائے اور رعایا کو ان کے حاکموں کے قانون اور رسم و رواج سے آگاہ کیا جائے تاکہ حکمرانوں کو اپنی رعایا کی تکلیفیں دور کرنے کا موقع ملے اور رعایا کی داد رسی ہو سکے۔”33
راجہ رام موہن رائے کمپنی کے عہد میں برصغیر کے سب سے بڑے مصلحِ قوم، عربی فارسی کے عالم اور مغربی تمدن کے پاسدار تھے۔ وہ 24 مئی 1774ء کو رادھا نگر بنگال میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان پانچ پشتوں سے صوبے کے مغل حاکموں سے وابستہ تھا۔ رواج کے مطابق ان کی ابتدائی تعلیم بھی عربی فارسی میں ہوئی۔اعلیٰ تعلیم کے لئے ان کو پٹنہ بھیج دیا گیا جو ان دنوں اسلامی تعلیمات کا بڑا مرکز تھا۔ وہاں اُنھوں نے قرآن شریف، فقہ، اسلامی دینیات اور علمِ مناظرہ پر عبور حاصل کیا نیز ان کو ارسطو کے عربی تراجم اور معتزلہ کی تصانیف کے مطالعے کا بھی موقع ملا ۔ اُنھوں نے صوفیوں کی کتابیں بھی پڑھیں اور وحدت الوجود کے فلسفہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ بُت پرستی کی مخالفت ان کی زندگی کا مشن بن گئی۔ اُنھوں نے سولہ برس کے سِن میں ایک کتاب ” تحفتہ الموحدّین” فارسی میں لکھی (دیباچہ عربی میں تھا) اور ہندو بت پرستی پر سخت اعتراضات کیے۔ اتفاق سے کتاب کے مسودے پر ان کے باپ کی نظر پڑی تو وہ آگ بگولہ ہو گئے اور کشیدگی اتنی بڑھی کہ رام موہن رائے کو گھر چھوڑنا پڑا۔ اس کے باوجود رام موہن رائے کو باپ کے جذبات کا اتنا احترام تھا کہ رسالے کو ان کی زندگی میں شائع نہیں کیا۔
رام موہن رائے کو برطانوی اقتدار سے سخت نفرت تھی لیکن کلکتہ میں قیام کے دوران جب ان کو انگریزی قوانین اور طریقِ حکومت کے مطالعہ کا موقع ملا تو اُنھوں نے محسوس کر لیا کہ ” غیر ملکی غلامی کا طوق” انگریزی تعلیم اور مغربی علوم کی تحصیل کے بغیر گلے سے اتار نہیں جا سکتا لہذا اُنھوں نے انگریزی زبان سیکھی جس سے واقفیت کے باعث مغربی علم و حکمت کے دروازے ان پر کُھل گئے۔ وہ پندرہ برس تک کمپنی سے وابستہ رہے مگر 1815ء میں پنشن لے لی اور سارا وقت سماجی کاموں میں صرف کرنے لگے۔ وہ ذات پات کی تفریق، بُت پرستی اور ستی کے بے حد خلاف تھے چنانچہ ہندو مذہب میں اصلاح کی غرض سے اُنھوں نے برہمو سماج کی تنظیم قائم کی اور ہندو معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کے خلاف سخت مہم شروع کردی۔
1813ء میں جب پارلیمنٹ نے کمپنی کے چارٹر کی تجدید کی تو ” ادب کی بحالی اور ترقی اور صاحبِ علم ہندوستانیوں کی حوصلہ افزائی اور برطانوی مقبوضاتِ ہند کے باشندوں کو سائنسی علوم سے روشناس کرنے اور ان کو فروغ دینے کی خاطر ایک لاکھ روپے سالانہ کی رقم مخصوص کردی گئی۔ ” مگر کمپنی کے حکام نے دس سال تک اس ہدایت کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ البتہ 1823ء میں جب پہلی بار تعلیمی کمیٹی بنی تو اس نے اٹھارویں صدی کی روایت کے مطابق یہ رقم مشرقی علوم والسنہ پر خرچ کرنا چاہی اور کلکتہ مدرسے کی طرز پر ایک سنسکرت کالج قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ راجہ رام موہن رائے نے اس تجویز کی شدت سے مخالفت کی۔ اُنھوں نے گورنر جنرل لارڈ ایمبرسٹ کے رُو برو جو محضر پیش کیا وہ ترقی پسند ہندوستانی حلقوں کی نئی ذہنیت کی پوری ترجمانی کرتا ہے۔ راجہ رام موہن رائے ُ( راجہ کا خطاب ان کو اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا مگر انگریزوں نے اس خطاب کو کبھی تسلیم نہیں کیا) نے اس تاریخی دستاویز میں لکھا تھا کہ “سنسکرت کالج کے طالب علم وہی دو ہزار برس پرانی دقیانوسی باتیں سیکھیں گے جن میں رعونت آمیز اور کھوکھلی موشگافیوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر برطانوی پارلیمنٹ کی منشا ہے کہ یہ ملک اندھیرے میں رہے تو سنسکرت نظامِ تعلیم سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا لیکن حکومت کا مقصد چوں کہ دیسی آبادی کی اصلاح و ترقی ہے لہذا ایسے کسی روشن خیال اور آزاد نظامِ تعلیم کو فروغ دینا زیادہ مناسب ہو گا جس میں ریاضی، نیچرل فلسفہ، کیمسٹری، علم الابدان اور دوسری مفید سائنسیں پڑھائی جائیں۔ مجوزہ رقم سے یورپ کے تعلیم یافتہ لائق اور فاضل استاد ملازم رکھے جائیں اور کالج کو ضروری کتابیں، آلات اور دوسری چیزیں فراہم کی جائیں۔
لارڈ ایمبرسٹ نے راجہ موہن رائے کی یہ تجویزیں مسترد کردیں اور سنسکرت کالج قائم ہو گیا لیکن بعض روشن خیال افراد نے مشنریوں کی مدد سے مغربی طرز کے کئی اسکول اور کالج کھولے اور انگریزی کتابوں کی اشاعت و فروخت کی غرض سے ایک ” اسکول بُک سوسائٹی” بھی قائم کی۔ بُک سو سائٹی نے دو سال کے عرصے میں 31ہزار سے زائد انگریزی کتابیں فروخت کیں جب کہ سرکاری کمیٹی تین برس میں عربی اور سنسکرت کی اتنی جلدیں بھی فروخت نہ کرسکی کہ طباعت کے اخراجات تو الگ رہے گودام کا دو مہینے کا خرچ ہی ادا ہو جاتا۔ برصغیر میں افکارِ تازہ کی نموداگر سب سے پہلے بنگالیوں میں ہوئی تو یہ ان کی صحافتی اور تعلیمی سرگرمیوں ہی کا فیض تھا۔ صرف ظاہر تھا کہ لوگ اندھیرے سے نکلنے کے لیے بے تاب ہیں اور پرانے علوم والسنہ ان کے ذوق کی تسکین کرنے سے قاصر ہیں۔
اسی اثنا میں انگریزوں نے 1803ء میں آگرہ اور دہلی کو بھی فتح کرلیا۔ اکبر شاہ ثانی کو کمپنی سے آٹھ لاکھ سالانہ پنشن ملنے لگی اور دہلی میں برطانوی عمل داری شروع ہو گئی۔ لہذا وہاں بھی انگریزی زبان اور مغربی علوم کا چرچا ہونا قدرتی بات تھی۔ یہ خدمت دہلی کالج نے سرانجام دی۔ دہلی کالج ابتدا میں روایتی طرز کا ایک مدرسہ تھا جس کو نظام الملک آصف جاہ کے بیٹے نواب غازی الدین نے 1792ء میں قائم کیا تھا۔ 1825ء میں کمپنی کی تعلیمی کمیٹی کی ہدایت پر مدرسے کو کالج میں تبدیل کردیا گیا۔ پانچ سو روپیہ ماہانہ امداد مقرر ہوئی اور ایک انگریز مسٹر ٹیلرپو نے دو سَو روپے ماہانہ تنخواہ پر اس کے پرنسپل بنائے گئے۔تین سال بعد دہلی کے ریذیڈنٹ کمشنر سر چارلس مٹکاف کی سفارش پر انگریزی جماعت کا بھی اضافہ ہوگیا۔ مولوی عبدالحق کے بقول کالج میں انگریزی کے اضافے سے ” لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی اور ہندو مسلمان دونوں نے اس کی مخالفت کی۔ دیں دار بزرگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے مذہب بگاڑنے اور اندر ہی اندر عیسائی مذہب کے پھیلانے کی ترکیب ہے۔ یہی مشکل بنگال میں بھی آئی تھی لیکن وہاں یہ آندھی اٹھی تو سہی مگر چند ہی روز میں بیٹھ گئی۔ وہاں مخالفت برہمنوں سے شروع ہوئی تھی تو یہاں مسلمان پیش پیش تھے۔۔۔۔ مسلمان طلبا کی تعداد انگریزی شعبے میں اکثر کم رہی34۔ سچ ہے اجداد کے فکری جمود کی سزا اولاد کو کئی نسلوں تک ملتی رہتی ہے۔ مولوی عبدالحق مرحوم دہلی کالج کی روز افزوں مقبولیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ” اگرچہ ابتدا میں انگریزی پڑھنے والوں کی تعداد تین سو تک پہنچ گئی۔ یہ زمانے کی ہوا تھی۔ ” اسی اثنا میں دہلی میں کئی مشن اسکول اور آگرہ اور بریلی میں مشن کالج بھی قائم ہو گئے جن میں مغربی علوم انگریزی زبان میں پڑھائے جانے لگے۔
دہلی کالج خالص سیکولر درس گاہ تھی۔ وہاں ہندو، مسلمان، عیسائی سب کے لیے نصاب ایک ہی تھا۔ کالج کو معلّم متعلّم کسی کے دینی عقائد سے کوئی سروکار نہ تھا۔ نہ کسی مذہب کی طرف داری کی جاتی تھی اور نہ کسی کی دل آزاری۔ انگریزی شعبے میں تو ظاہر ہے کہ انگریزی زبان و ادب اور مغربی علوم ہی پڑھائے جاتے تھے مگر مشرقی شعبے میں بھی روایتی نصاب کے علاوہ اصولِ حکومت و وضعِ قوانین، ضابطہ دیوانی، الجبرا، ہیئت، ریاضیات، پیمائش، حرکیات، میلنکس، سکونیات، کیمسٹری، طبیعات، مساوات، اقلیدس، علم المناظر، اخلاقی سائنس، تاریخ، جغرافیہ اور نیچرل فلسفے کی تعلیم دی جاتی تھی۔
مشرقی شعبے میں یہ مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے لیکن ان موضوعات پر اردو میں کتابیں موجود نہ تھیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کی غرض سے کالج کے پرنسپل مسٹر تبروس کی تحریک پر (وہ اردو میں شعر بھی کہتے تھے) 1843ء میں وہلی میں “ا نجمن اشاعتِ علوم بذریعہ السنئہ ملکی” کا قیام عمل میں آیا۔ اس انجمن کا مقصد مغربی علوم کی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ یا خلاصہ تیار کرنا تھا۔ مولوی عبدالحق مرحوم نے انجمن کے شائع کردہ تراجم و تالیات کی جو فہرست دی ہے اس میں متذکرہ بالا تمام موضوعات پر کتابیں شامل ہیں۔ ان کتابوں سے یہ فائدہ ہوا کہ مشرقی شعبے کےطلبا کے علاوہ دوسروں کو بھی جو انگریزی نہیں جانتے تھے مغربی افکار سے واقفیت کا موقع ہاتھ آگیا۔
دہلی کالج کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ اسی درس گاہ کی بدولت شمالی ہند کے مسلمان پہلی بار جدید مغربی علوم سے باقاعدہ طور پر روشناس ہوئے اور کالج کے اساتذہ اور طلبا نے مغربی علوم کی کتابیں اردو میں ترجمہ کر کے ثابت کردیا کہ اردو میں اجنبی خیالات کے اظہار کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ کالج کی ان خدمات کو سراہتے ہوئے مولوی عبدالحق مرحوم لکھتے ہیں کہ ” یہی وہ پہلی درس گاہ تھی جہاں مغرب و مشرق کا سنگم قائم ہوا۔ اس ملاپ نے خیالات کے بدلنے، معلومات میں اضافہ کرنے اور ذوق کی اصلاح میں جادو کا کام کیا اور ایک نئی تہذیب اور نئے دور کی بنیاد رکھی اور ایک نئی جماعت ایسی پیدا کی جس میں ایسے پختہ، روشن خیال اور بالغ نظر انسان اور مصنف نکلے جن کا احسان ہماری زبان اور ہماری سوسائٹی پر ہمیشہ رہے گا۔” کالج کے اساتذہ میں مولوی امام بخش صہبائی، مولوی سبحان بخش، شمس العلما ڈاکٹر ضیاء الدین سائنس کی کتابوں کے مولف ماسٹر رام چندر ، ماسٹر پیارے لال (جو غالب کے دوست اور قصصِ ہند، تاریخِ انگلستان، دربارِ قیصری وغیرہ کے مصنف اور رسالہ اتالیفِ پنجاب لاہور کے ایڈیٹر تھے) اور شمس العلما مولوی ذکااللہ اور طلبا میں جنھوں نے اردو ادب میں شہرت پائی ڈپٹی نذیر احمد، مولوی محمد حسین آزاد، مولوی کریم الدین مصنف تعلیم النسا، گلستان ہند، تذکرہ شعرائے ہند، تذکرۃ النسا اور میرناصر علی ایڈیٹر صلائے عام قابلِ ذکر ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا تو قول تھا کہ
” معلومات کی وسعت، رائے کی آزادی، ٹالریشن (درگزر) گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی، اجتہاد، اعلیٰ بصیرۃ یہ چیزیں جو تعلیم کے عمدہ نتائج ہیں اور جو حقیقت میں شرطِ زندگی ہیں ان کو میں نے کالج ہی میں سیکھا اور حاصل کیا اور میں اگر کالج میں نہ پڑھتا تو بتاؤں کیا ہوتا؟ مولوی ہوتا، تنگ خیال، متعصب، اکھل کھرا، اپنے نفس کے احتساب سے فارغ، دوسروں کے عیوب کا متجسس، برخود غلط؎
ترکِ دنیا بہ مردُم آموزند
خویشتن سیم و غلہ اندوزند
(دوسروں کو ترکِ دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اور خود دولت اور غلہ جمع کرتے رہتے ہیں) مسلمانوں کا نادان دوست، تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا بہرا۔
صم بکم عمی فھم لا یرجعون، مااصابتی من حسنۃ فی الدنیا فمن الکالج (دین اور دنیا کی جو اچھائیاں میں نے حاصل کی ہیں وہ کالج ہی کا فیض ہیں)
یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ انگریزی زبان اور مغربی علوم کی تعلیم سے عام مسلمانوں کی ذہنیت بدل گئی یا وہ مغربی تہذیب و تمدن کے گرویدہ ہو گئے البتہ ایک حلقہ ضرور پیدا ہوا جو صدقِ دل سے محسوس کرتا تھا کہ اسلام کو مغرب کے سیکولر علوم اور سیکولر اداروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ کہ عزت و آبرو سے جینا ہے تو پرانی ڈگر کو ترک کر کے اپنی طرزِ زندگی اور طرزِ فکر میں اصلاح کرنی ہوگی۔
اسی دوران میں کمپنی کے کردار اور اس کی حکمتِ عملی میں بھی انقلاب انگیز تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اب وہ ایک سامراجی طاقت تھی جو دو تہائی ہندوستان پر قبضہ کر چکی تھی اور بقیہ علاقوں پر تسلط جمانے کی فکر میں تھی لہٰذا کمپنی کو اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کی خاطر یہ طے کرنا تھا کہ اس وسیع و عریض سلطنت کا نظم و نسق کن اصولوں پر استوار کیا جائے۔ قوانین کی نوعیت اور عدالتوں کا نظام کیا ہو، حکومت کی سرکاری زبان کون سی ہو، اسکولوں میں ذریعہ، تعلیم فارسی ہو انگریزی اور نصابِ تعلیم مشرقی ہو یا مغربی۔ کمپنی کے اعلیٰ حکام ان دنوں دو صفوں مین بٹ گئے تھے۔ بالآخر بڑی جرح و بحث کے بعد لارڈ میکالے کی تجویز منظور ہوئی جو کٹّر مغرب نواز تھا اور گورنر جنرل لارڈ ولیم بنٹنک نے 1835ء میں فیصلہ صادر کیا کہ حکومت کی سرکاری زبان آئندہ فارسی کے بجائے انگریزی ہو گی البتہ دفتروں اور عدالتوں میں دیسی زبانوں میں بھی لکھا پڑھی کی اجازت ہوگی۔ ملازمتوں پر ترجیح انگریزی دانوں کو دی جائے گی، اسکولوں اور کالجوں میں ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگی اور طلبا کو انگریزی ادب اور مغربی علوم پڑھائے جائیں گے۔ مغلیہ عہد کا قانونِ ضابطہ فوجداری تین سال قبل ہی منسوخ کردیا گیا تھا اور اس کی جگہ برطانوی قانون نافذ ہو گیا تھا۔ لارڈ میکالے پادریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کے بھی خلاف تھا۔ اس کی رائے تھی کہ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے حکومت کو کسی مذہب کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ بالکل غیر جانب دار رہنا چاہیے لہٰذا طے پایا کہ سرکاری اور امدادی درس گاہوں میں تعلیم سیکولر ہوگی۔
سرکاری درس گاہوں میں تعلیم کو سیکولر کردینے کی پالیسی کو ہندو مسلمان دونوں فرقوں کے روشن خیال حلقوں نے سراہا چنانچہ سر سید احمد خان نے ” مذہب اور عام تعلیم” کے عنوان سے جو مضمون 1871ء میں شائع کیا اس میں وہ حکومت کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ۔
” ہندوستان میں گورنمنٹ کی رعایا مختلف مذہب کی ہے اور وہ خود ان سے مختلف مذہب رکھتی ہے اور اس سبب سے وہ کسی قسم کی مذہبی تعلیم کو شامل نہیں کرسکتی تھی۔ ہم نہایت سچے دل سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جس قدر نا طرف دار طریقہ تعلیم کا اور مذہبی خیالات سے بچا ہوا اور اچھوتا اختیار کیا ہے اور جس قدر سعی اور کوشش ہندوستان کی تعلیم میں گورنمنٹ نے کی ہے وہ دونوں بے مثل اور بے نظیر ہیں اور غالباً اس وقت دنیا کے پردے پر اس کی نظیر موجود نہیں ہے مگر اس پر بھی جو امرا عام تعلیم کی ترقی کا مانع ہے اس کا رفع کرنا گورنمنٹ کی قدرت سے باہر ہے۔ وہ یہ کرسکتی تھی کہ اپنے تئیں مذہبی تعلیم سے بالکل علیحدہ رکھے مگر یہ نہیں کرسکتی تی کہ تمام مذاہبِ ہندوستان یا کسی خاص مذہب یا مذہبوں کی تعلیم اختیار کرے” ۔35
مگر کمپنی کی سیکولر پالیسی مخلصانہ نہ تھی بلکہ سیاسی مصلحتوں پر مبنی تھی۔ چنانچہ لارڈ میکالے کی تنبیہ کے باوجود کمپنی پادریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کی برابر حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ انگریز حکام مشن والوں کی مالی امداد کرتے، ان کو اپنی کوٹھیوں میں وعظ کے لیے بلاتے اور اپنے ملازموں کو پادریوں کی تقریریں سننے پر مجبور کرتے تھے۔ سرسید نے اپنی مشہور تصنیف “اسبابِ بغاوتِ ہند” (1859ء) میں کمپنی کے غیر سیکولر طرزِ عمل پر تفصیل سے لکھا ہے اور واقعات کےحوالے دے کر بتایا ہے کہ کس طرح قحط زدہ یتیم بچوں کو عیسائی بنایا جاتا تھا، کس طرح گورنمنٹ کے تنخواہ یافتہ پادری ہندوؤں اور مسلمانوں کی مقدس شخصیتوں کا ذکر اپنی تقریروں اور تحریروں میں نہایت ہتک اور نفرت سے کرتے تھے اور کس طرح مشن اسکولوں میں بچوں سے امتحان عیسائی مذہب کی کتابوں میں لیا جاتا تھا۔ سرسید نے کلکتہ کے لاٹ پادری ایڈمنڈ کی ایک گشتی چٹھی کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں سرکاری ملازمین کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ عیسائی مذہب اختیار کرلیں۔ ” میں سچ کہتا ہوں کہ ان چٹھیات کے آنے کے بعد خوف کے مارے سب کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ پاؤں تلے کی زمین نکل گئی، سب کو یقین ہو گیا کہ ہندوستانی جس وقت کے منتظر تھے وہ وقت اب آگیا۔ اب جتنے سرکاری نوکر ہیں اوّل ان کو کرسٹان ہونا پڑے گا اور پھر تمام رعیت کو۔”36
1857ء کے بعد ہندوستان اگر چہ براہِ راست تاجِ برطانیہ کے زیرِ نگیں ہو گیا مگر حکومتِ ہند کی مشن نواز پالیسیوں میں فرق نہ آیا البتہ ملک کے قوانین اور ضابطوں کو سیکولر بنانے پر زیادہ توجہ دی جانے لگی۔ 1859ء میں ضابطہ دیوانی وضع ہوا۔ دوسرے برس قانون تعزیراتِ ہند اور قانون ضابطہ فوجداری نافذ کیا گیا۔ 1864ء میں دیوانی عدالتوں سے مسلمان قاضی اور ہندو پنڈتوں کو چُھٹی مل گئی اور ہندو مسلم سِول قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کے فرائض سرکاری مجسٹریٹوں کے سپرد کردیے گئے۔ 1872ء میں قانونِ شہادت نافذ ہوگیا۔صوبوں میں ہائی کورٹ اس سے پہلے قائم ہو چکے تھے۔ یہ تمام قوانین مغرب میں رائج سیکولر اصولوں کی روشنی میں تیار کیے گئے تھے۔
مگر انگریزوں نے ہندوستانی سیاست کو سیکولر خطوط پر ترقی کرنے کا کبھی موقع نہ دیا بلکہ پہلے دن سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین نفاق اور بدگمانیوں کے بیج بونا شروع کردیے۔ ” پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو” ان کی پالیسی کا سنگِ بنیاد بن گیا۔ یہ نئی پالیسی مغلوں کی حکمتِ عملی کی عین ضد تھی۔ مغل حکمرانوں نے اپنی سیاست کی بنیاد ہندو مسلم اتحاد پر رکھی تھی۔ اُنھوں نے دونوں فرقوں کو آپس میں لڑانے کی کبھی کوشش نہیں کی بلکہ ایسے معروضی حالات پیدا کیے جن میں دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کے عقاید و جذبات کا احترام کریں، جو اقدارِ زیست مشترک ہوں ان کو فروغ دیں اور جن اقدار سے آپس میں عداوت یا دشمنی بڑھنے کا اندیشہ ہو ان سے حتی الوسع پرہیز کریں۔ مغلوں نے ان فسادی عناصر کو بھی سختی سے دبایا جو ہندو مسلمانوں کے درمیان ایک خلیج کو بڑھاتے تھے۔ اس کے برعکس انگریزوں نے ایسے معروضی حالات پیدا کیے جن میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلاف کی خلیج وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ برصغیر میں سیکولرازم کی نشوونما میں رکاوٹ ڈالنے والی دراصل خود حکومتِ برطانیہ کی سیکولر دشمن سیاسی پالیسی تھی۔
(5)
برصغیر میں سیکولر خیالات اپنی نئی شکل می ہرچند کہ جدید طرز کی صنعت و حرفت، مغربی انداز کے نظم و نسق اور مغربی علوم کی انگریزی زبان میں تعلیم کی وجہ سے پھیلے لیکن سیکولر خیالات یہاں پہلے بھی موجود تھے البتہ ان کی نوعیت مختلف تھی کیوں کہ معاشرتی حالات اور فکری تقاضے مختلف تھے۔ مثلاً اردو، فارسی کے کلاسیکی ادب میں بالخصوص شاعری میں جو ہمارے جذبات و احساسات کا آئینہ ہے سیکولر فکرکی روایت بہت پرانی ہے۔ اس طرزِ فکر کے ہدف معاشرے کے وہ عناصر تھے جو جبرو استبداد کی علامت بن گئے تھے اور انسان دشمنی، تعصب اور تنگ نظری کےاظہار میں وہی کردار ادا کرتے تھے جو قرونِ وسطیٰ میں مغربی کلیسا کا تھا۔ ہمارا شاید ہی کوئی شاعر ہو جس نے اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنے کے باوصف کو نہ آستین مُلاؤّں کی دراز دستیوں پر، زہادِ زشت خو کی ہوس ناکیوں پر، پیرانِ سالوس کی شعبدہ بازیوں پر، مفتیانِ شرع کی اقتدار پرستیوں پر، محتسبوں کی تردامیوں پر، واعظوں کی لن ترانیوں پر اور فقیہانِ شہر کی ریاکاریوں پر لعن طعن نہ کی ہو کیوں کہ اس دور میں سیکولر خیالات و جذبات کے ابلاغ کی یہی صورت ممکن تھی۔
مگر جس تہذیب و تمدن کا عمل دخل انیسویں صدی میں ہو رہا تھا اس کے مطالبے کچھ اور تھے۔ ان مطالبوں پر مرزا غالب نے دہلی کالج سے بھی پہلے لبیک کہی۔ مرزا غالب (1797ء۔ 1869ء) اُن بیدار مغز اور صاحبِ نظر ہستیوں میں تھے جن کی نگاہیں موت کے ملبوں میں زندگی کے ابھرتے ہوئے آثار دیکھ لیتی ہیں۔ وہ بقول خود اُن ” آزادوں ” میں تھے جن کو ماضی کے مٹنے کا غم ” بیش ازیک نفس” نہیں ہوتا کیوں کہ؎
برق سے کرتے ہیں روشن شمعِ ماتم خانہ ہم
عام خیال یہ ہے کہ غالب میں جدید سیکولر رحجانات کلکتہ کے قیام کے دوران ابھرے جہاں ان کو اپنی پنشن کے سلسلے میں تقریباً دو سال رہنا پڑا تھا (1827ء تا 1829ء) لیکن واقعہ یہ ہے کہ مغرب کا جادو اُن پر بنگال جانے سے پہلے اثر کر چکا تھا البتہ ان کے مغرب نواز طرزِ فکر و احساس میں پختگی کلکتے میں مغربی معاشرت کا مشاہدہ کرنے سے آئی۔ ان کو یقین ہو گیا کہ مشرق کا معاشرتی نظام دم توڑ چکا ہے اور انگریز جو نظام اپنے ساتھ لائے ہیں وہ بڑا توانا اور جان دار ہے۔
مرزا غالب کے گھرانے نے 1803ء ہی میں جب کہ غالب کی عمر فقط چھ سال تھی انگریزوں کی ماتحتی قبول کر لی تھی۔ لارڈ لیک نے آگرہ فتح کرنے کے بعد غالب کے چچا اور سرپرست مرزا نصراللہ بیگ خاں کو چار سَو سواروں کا بریگیڈیر مقرر کردیا تھا اور دوگنے بطور معاش دے دیے تھے۔ مرزا کے نانا بھی میرٹھ میں کمپنی کی فوج میں معزز عہدے پر مامور تھے اور آگرے کے عمائدین میں شمار ہوتے تھے اور مرزا کی شادی بھی لوہار خاندان میں ہوئی تھی جو انگریزوں کا بڑا خیر خواہ تھا۔ غالب نے 1811ء میں جب دہلی میں مستقل سکونت اختیار کرلی تو ان انگریزوں سے راہ و رسم بڑھانے کے زیادہ مواقعے ملے۔ اُنھوں نے مسٹر اینڈ منٹن، مسٹر فریزر اور دوسرے انگریزی حکام سے اگرچہ حصولِ منفعت کی خاطر دوستانہ تعلقات قائم کیے تھے لیکن اس میل جول نے بھی ان کے مزاج و مذاق کو ضرور متاثر کیا۔ اس کے علاوہ معمولی سُوجھ بُوجھ رکھنے والا شخص بھی مغلیہ تہذیب کی زبوں حالی کا موازنہ انگریز حاکموں کی شان و شوکت سے کر کے اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ شمعِ مشرق عنقریب بجھنے والی ہے اور ان تِلوں میں اب تیل نہیں رہا؎
کیا شمع کے نہیں ہیں ہوا خواہ اہلِ بزم
جب غم ہی جاں گُداز ہو، غم خوار کیا کریں
یہ جاں گُدازی ایک معاشرتی نظام کے عالمِ نزع کا المیہ تھی مگر غالب کو موت سے کبھی الفت نہیں ہوئی نہ اُنھوں نے مُردہ پرستی کو کبھی پسند کیا ( مُردہ پرور دن مبارک کارِ نیست)
جو میلانات دہلی میں ہنوز زیرِ تشکیل تھے وہ کلکتہ میں تکمیل پا گئے۔ غالب نے کلکتہ کی آب و ہوا کی جو تعریف کی ہے وہ تو خیر ان کی شاعرانہ ہٹ دھرمی ہے کیوں کہ آب و ہوا کے اعتبار سے کلکتہ ہندوستان کا شاید سب سے خراب شہر تھا اور اب بھی ہے۔ وہاں کی گرمی، حبس، اُمس اور غلاظت کے خیال ہی سے بدن کانپنے لگتا ہے البتہ جس چیز نے غالب کو چکا چوند کردیا ہوگا وہ کلکتہ کی مغربی طرزِ معاشرت تھی، انگریزوں کے ٹھاٹھ باٹھ تھے۔ شہر کی خوش حالی اور گہما گہمی تھی اور ہنستی شور مچاتی زندگی تھی جب کہ دہلی کے اجڑے دیار میں ہر طرف ویرانی اور مفلسی برستی تھی۔ نہ کوئی کاروبار تھا نہ روزگار، پیٹ خالی، جیب خالی اور چہروں پر ہوائی اُڑتی ہوئی۔ غالب جیسا حساس و ذی ہوش شخص زمین و آسمان کے اس فرق کو اگر نہ دیکھتا تو حیرت ہوتی۔ اپنے ایک عزیز علی بخش رنجور کو کلکتہ کی ثنا و صف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
” کلکتہ کیا شہر گُوناگوں و مالا مال ہے کہ چارہ مرگ کے سِوا ہر پیشے کا ہُنر مند وہاں موجود ہے اور تقدیر کے علاوہ جو چاہو بازار میں سستے داموں مل سکتا ہے۔” (فارسی)
اور دہلی واپس آکر کلکتہ کے ایک دوست کو لکھتے ہیں کہ
” کلکتے کی خاک نشینی دوسرے مقام کی تخت نشینی سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم۔ بال بچوں کا بکھیڑا نہ ہوتا تو میں کب کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہیں پہنچ جاتا۔” (فارسی)
فارسی کے ایک قطعے میں ” ساقی بزم آگہی” (ساقی بزمِ عشق نہیں) سے مختف مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ باتوں باتوں میں بنارس اور پٹنہ کا ذکر آتا ہے تو ساقی ان شہروں کی بڑی تعریف کرتا ہے۔”تب میں نے کلکتہ کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا کہ کلکتہ کو آٹھویں اقلیم کہنا مناسب ہوگا ۔ میں نے پوچھا اور وہاں کے آدمی۔ وہ بولا ہر ملک اور ہر فن۔”
حالِ کلکتہ باز جُستم گفت
باید اقلیمِ ہشتمیں گفتن
گفتم آدم بہم رسد دروی
گفت از ہر دیار، ازہرفن
غالب کو اخبار بینی کا شوق بھی کلکتہ کے قیام کے دوران پیدا ہوا۔ ان کے ادراک و آگہی میں اس سے بھی اضافہ ہوا ہو گا۔ کلکتہ سے اُن دِنوں فارسی کے دو ہفت روزہ اخبار نکلتے تھے۔ ایک منشی سدا سُکھ کا “جامِ جہاں نما” دوسرا راجہ موہن رائے کا ” مراۃ الاخبار”۔ جامِ جہاں نما میں تو قتیل کے شاگردوں سے مرزا کی ادبی بحثوں کی رُوداد بھی چھپتی تھی جو غالب کی نظر سے یقیناً گزری ہو گی۔ مراۃ الاخبار اس شخص کے خیالات کا نقیب تھا جو غالب ہی کی طرح موحد تھا اور جس کا کیش بھی ” ترکِ رسوم” تھا۔ کیا عجب کہ وحدت الوجود پر ان کا ایمان مراۃ الاخبار کے مطالعے سے اور مستحکم ہو ا ہوا۔
مرزا غالب نے نثر نویسی کا جو نیا اسلوب اختیار کیا وہ بھی خالص مغربی تھا۔ مقفّا مسجع پیرایہ بیان کے بجائے، جو اس وقت کا عام دستور تھا سہل اور رواں تحریر، مکتوب علیہ کو بے تکلفی سے مخاطب کرنا اور خطوں کا مکالمہ بنا دینا حتیٰ کہ لفافے پر پتہ بھی جدید طریقے پر لکھنا ان سب باتوں میں انگریزوں کے مذاق اور مشرب کا رنگ صاف نمایاں ہے۔ وہ صحیح معنی میں مرد آزاد تھے۔ مذہبی تعصبات سے مُبّرا، رسوم و قیود کی بندشوں سے گریزاں ، رنگ و نسل کی تفریق کے منکر، دینِ بزرگاں کی پیروی سے بے زار، خرد کے گرویدہ اور توہمات سے متنفر، ایسے فراخ دل اور روشن خیال شخص کو مغربی تمدن کی خوبیوں کی تہ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی ہوگی۔
اُنھوں نے سید احمد خان کی تصحیح کردہ ” آئینِ اکبری” پر جو منظوم تقریط لکھی اس کے مطالعے کے بعد تو غالب کی روشن خیالی کے بارے میں کسی شک و شبہے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ واقعہ 1855ء کا ہے۔ اس وقت تک سید احمد خان کو کمپنی کی ملازمت کرتے سولہ سترہ برس گزر چکے تھے مگر ان کی سوچ ہنوز روایتی تھی۔ تقریظ کی تمہید میں غالب سید احمد خان کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک “دیدہ بینا” نے ” کہنگی” کو نیا لباس پہنایا ہے لیکن ” آئینِِ اکبری” کی تصحیح ان کی ” ہمت والا” کے لیے باعث ” ننگ و عار ” ہے ۔ اُنھوں نے اس مشغلے سے اپنا دل بے شک خوش کیا مگر میں ” آئین ریا” کا دشمن ہوں لہٰذا ان کے کام پر آفریں نہیں کہہ سکتا کیوں کہ میں تو تخلیقِ نو کا جویا ہوں اور اب میں ” آئین” سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آنکھیں کھولو اور اس ” دیرِ کہن” میں
صاحبان انگلستان رانگر صاحبانِ انگلش کو اور
شیوہ و اندازِ انیاں رانگر ان کے شیوہ و انداز کو دیکھو
تاچہ آئین ہا پدید آور دہ اند اُنھوں نے کیسے کیسے آئین وضع کیے ہی اور ایسے آئین
آنچہ ہر گز کس نہ دید، آوردہ اند جن کو کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھا یہاں لائے ہیں
زیں ہنر منداں ہنر بیشی گرفت ان سے ہنر مندوں نے ہنر کے اصول سیکھے ہیں
سعی بر پیشیناں پیشی گرفت اور اپنے اجداد سے بھی آگے نکل گئے ہیں
حق ایں قوم است “آئیں” داشتن آئین پر عمل کرنا اس قوم کا حق ہے
کس نیارد ملک بہ زیں داشتن کسی اور کو ملک کو اس سے بہتر چلانا نہیں آتا
داد و دانش رابہم پیوستہ اند اُنھوں نے عدل اور دانائی کا مِلا دیا ہے
ہند را صد گو نہ آئین بستہ اند اور ہندوستان کو سَو گنا ملکِ آئین بنا دیا ہے
آتشے کز سنگ بیرون آورند لوگ پتھر سے چنگاری پیدا کرتے ہیں (چمقان کو رگڑکر)
ایں ہنر منداں زخس چو آورند مگر یہ ایسے ہنر مند ہیں کہ تنکے سے آگ نکالتے ہیں (دِیا سلائی)
تاچہ افسوں خواندہ اندانیاں برآب اُنھوں نے پانی پر نہ جانے کیا جادو کردیا ہے کہ
دُور کشتی راہمی راند در آب کہ دھواں کشتی کو پانی میں ہانکتا ہے
کہ دُخاں، کشتی بہ جیحوں می برد بھاپ کبھی جہاز کو سمندر میں لے جاتی ہے
کہ دُخاں، گردوں بہ ہاموں می برد اور کبھی چیزوں کو بلندی سے زمین پر لے آتی ہے
از دُخاں زورق بہ رفتار آمدہ بھاپ کی قوت سے کشتی رفتار پکڑتی ہے اور اس کے سامنے
باد و موج ایں ہر دوبے کار آمدہ ہوا اور پانی کی لہریں دونوں بے بس ہو جاتی ہیں
نغمہ بے زخمہ ازساز آورند یہ لوگ ساز سے بِلا دستانے کے دُھن نکال لیتے ہیں
حرف چوں طائر بہ پرواز آورند اور حروف کو پرندوں کی پرواز عطا کرتے ہیں
ہیں، نمی بینی کہ ایں دانا گروہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ دانا گروہ
در د دم آرند از صد کروہ لفظوں کا پیغام لمحوں میں سو کوس تک پہنچا دیتا ہے (تاربرقی)
می زنند آتش بہ باد اندر ہمی ہوا (گیس) کو ا س طرح آگ دکھاتے ہیں کہ ہوا، انگارے کی طرح دہکنے لگتی ہے(گیس کی روشنی)
روبہ لندن کا ندراں رخشندہ باغ لندن پر نظر ڈالو
شہر روشن گشتہ درشب بے چراغ جو رات کے وقت بِلا چراغ کے جگمگاتا رہتا ہے
کاروبارِ مردمِ ہشیار بیں ہوشیار انسانوں کے کاروبار کو دیکھو
در ہر آئیں صد نو آئیں کارِ بیں ایک آئین میں سینکڑوں نئے آئین کی کارفرمائی دیکھو
پیش ایں آئیں کہ دارد روزگار اس آئین کے آگے
گشتہ آئینِ دگر تقویم پار دوسرے آئین پرانی جنتری کی حیثیت رکھتے ہیں
ہست، اے فرزانہ بیدار مغز؟ اے میرے بیدار مغزعاقل
درکتاب ایں گونہ آئین ہائے نغر کیا تمھاری کتاب (آئینِ اکبری) میں ایسی دانائی کی باتیں ہیں؟
چوں چنین گنج گہر بیند کسے اگر کسی کو موتیوں کا خزانہ دکھائی دے تو
خوشہ زاں خرمن چرا چیند کسے وہ کھلیان میں سے ایک بالی کیوں چنے
مبداءِ فیاض را مشمر نجیل فیض کے سر چشمے کو کنجوس مت جانو
نورمی ریزدر طب ہازاں نخیل خرمے کے درخت سے سورج رسیلے پھل ٹپکاتا ہے
مُردہ پروردن مبارک کارِ نیست مُردہ پروری اچھا مشغلہ نہیں
خود بگو، کان نیز جز گفتار نیس تم خود ہی کہو کہ کیا یہ سب باتیں ہی باتیں نہیں ہیں
اس نظم میں مرزا غالب سید احمد خان کو اشارۃً کناتیہً بھی مغربی تہذیب کو اپنانے کا مشورہ نہیں دیتے۔ ان کو انگریزوں کی پوشاک،خوراک سے کوئی دل چسپی نہیں، نہ وہ صاحبانِ عالی شان کی طرزِ بُود و ماند سے مرعوب ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنی مادری زبان ترک کر کے انگریزی زبان اختیار کرلو اس لیے کہ غالب کو اپنی مشرقی تہذیب پر بڑا ناز تھا اور اُنھوں نے آخر وقت تک اپنی مشرقی قدروں کو بڑی آن بان سے نباہا۔ البتہ وہ ہماری سوچ کا انداز بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ ” کہنگی” اور مُردہ پرستی کے سخت دشمن ہیں۔ اپنی مشہور غزل میں جو کلکتہ سے واپسی پر1830ء میں کہی گئی تھی فرماتے ہیں کہ
رفتم، کہ کہنگی زتماشا بر افنگم میں گیا تاکہ زندگی سے کہنگی کو خارج کردوں
در بزمِ رنگ و بُو نمطی دیر افکنم اور اس دنیا میں ایک دوسرا طریقہ رائج کروں
دروّ جدِ اہلِ صومعہ ذوقِ نظارہ نیست زاہدوں کے وجد حقیقت شناسی کے ذوق سے خالی ہیں
ناہید رابہ زمزمہ از منظر افکنم لہٰذا میں اپنے زمزموں سے زہرہ فلک کے اقتدار کو ختم کرتا ہوں
دیر ِ کہن کیا، وہ تو ” قاعدہ آسماں” کو بھی بدل دینا چاہتے ہیں (بیاکہ قاعدہ آسماں بہ گردانیم) فیوڈلزم کی جدید اصطلاح سے ان کے کان اگرچہ آشنا نہیں لیکن کہنگی سے ان کی مرد یقیناً فیوڈلزم کا فرسودہ نظام تھا۔ البتہ وہ مغربی تمدن کے حامی ہیں اور مغرب میں جو نئی نئی صنعتی ایجادیں ہوئی تھیں سید احمد خان کو ان کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئلے اور بھاپ سے چلنے والی مشینیں، تار برقی، گیس، دِیا سلائی وغیرہ لیکن غالب کی نظرمیں ان چیزوں سے بھی زیادہ اہم مغرب کا آئینِ نو یعنی نظامِ مملکت ہے جو عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اٹھارویں صدی میں سلطنتِ مغلیہ کے زوال کے بعد ملک میں جو طوائف الملوکی، لا قانونیت اور افراتفری پھیلی اس کے پیشِ نظر مرزا غالب برطانیہ کے نافذ کردہ آئیںِ نو کی طرف داری کرنے میں یقیناً حق بہ جانب تھے۔ اس نئے آئین کے آگے آئینِ اکبری کی حیثیت واقعی پرانی جنتری سے زیادہ نہ تھی ۔
سید احمد خان کو غالب کے یہ بے لاگ تنقید پسند نہیں آئی لہٰذا اُنھوں نے تقریظ کو کتاب میں شامل نہیں کیا۔ وہ انگریزوں کے وفادار ضرور تھے مگر ان کے خیالات ابھی تک قدیم دائرے میں محدود تھے اور جو کتابیں اُنھوں نے اس دور میں لکھیں وہ یا تو روایتی انداز کی تھیں یا ایسے مذہبی موضوعات پر رسالے لکھے جو وہابی اندازِ فکر سے متاثر تھے نیز مناظرانہ انداز کے تھے 37۔ سید احمد خان کا یہ اندازِ فکر غدر کے بعد بھی 1862ء تک قائم رہا۔
سید احمد خان(1817ء۔1898ء) دہلی کے ایک ممتاز خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد سید متقَی (وفات 1838ء) بادشاہ کے مقربینِ خاص میں تھے۔ ان کے نانا خواجہ فریدالدین (وفات 1828ء) بڑے عالم فاضل بزرگ تھے۔ کمپنی نے ان کو سات سو روپے ماہانہ پر کلکتہ مدرسے کا ناظم مقرر کردیا تھا۔ انگریز ان کی فراست و ذکاوت سے اتنے متاثر تھے کہ اُنھوں نے خواجہ فریدالدین کو دوبار سفارت پر بھیجا، پہلے ایران پھر برما، 1815ء میں اکبر شاہ ثانی نے ان کو وزیرِ مال و خزانہ مقرر کیا مگر درباری سازشوں سے تنگ آکر اُنھوں نے بالآخر استعفیٰ دے دیا۔ سید احمد خان کا بچپن اسی لائق اور مُدبر نانا کے گھر میں گزرا۔ ان کے سوانح نگار کا کہنا ہے کہ سید احمد خان کا آنا جانا شاہی دربار میں بھی ہوتا تھا اور وہیں ” ان کو راجہ رام موہن رائے جیسے عظیم ہندوستانی رہنما کو دیکھنے کا موقع ملا”۔۔۔۔ سید احمد خان اپنے نانا کے تذکرے کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ” راجہ رام موہن رائے نہایت لائق اور ذی علم اور متین ، مہذب و با اخلاق شخص تھے۔ وہ دِلی میں آئے اور بادشاہ کی ملازمت کی اور ان کو راجہ کا خطاب بادشاہ کی طرف سے دیا گیا اور آخرکار وہ بادشاہ کے وکیل ہو کر لندن بھیجے گئے۔ راقم نے ان کو متعدد بار دربارِ شاہی میں دیکھا ہے (اس وقت سرسید کی عمر 12 ،13 برس سے زیادہ نہ تھی) اور دِلّی کے لوگ یقین کرتے تھے کہ ان کو مذہبِ اسلام کی نسبت زیادہ رحجانِ خاطر ہے۔” 38 راجہ رام موہن رائے کے اِنھیں اوصاف کی شہرت سن کر اکبر شاہ ثانی نے ان کو دہلی بلوایا تھا اور لندن اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ وہ بادشاہ کی پنشن میں اضافے کی کوشش کریں۔ راجہ رام موہن رائے پنشن میں تین لاکھ روپیہ سالانہ اضافہ کروانے میں کامیاب ہوگئے مگر واپسی سےپہلے برسٹل میں بیمار پڑے اور وفات پاگئے۔ ان کی لاش وہیں دریا کنارے نذرِ آتش کردی گئی۔ افسوس ہے کہ ہماری نئی نسل عربی فارسی کے اس عالم، بت پرستی کےے دشمن اور سلطنتِ مغلیہ کے وفادار خادم کے نام سے بھی واقف نہیں البتہ بچوں کی کتابوں میں ہمارے ہیرو کون ہیں؟ احمد شاہ ابدالی، جس ظالم نے سرحد، پنجاب اور سندھ کے مسلمانوں کو درجنوں بار حملہ کر کے لوٹا اور قتل کیا۔
سید احمد خان 1838ء دہلی کے صدر امین کے دفتر میں سر رشتہ دار ہوئے۔ چند ماہ بعد ان کو کمشنر آگرہ کے دفتر میں نائب منشی کا عہدہ مل گیا۔ تین سال بعد وہ مین پوری میں منصف مقرر ہوئے پھر فتح پور سیکری، دہلی، بجنور، مراد آباد، غازی پور، علی گڑھ اور بنارس میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر مامور رہے ۔ بجنور میں غدر کے زمانے میں اُنھوں نے انگریزوں کی جان بچانے کی کوشش میں کئی بار اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ مراد آباد میں اُنھوں نے قحط زدگان کی خدمت بڑے خلوص اور خوش اسلوبی سے کی۔ 1863ء میں اُنھوں نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تاکہ مغربی علوم کی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ غازی پور ہی میں اُنھوں نے ایک اسکول کھولا جس میں انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔1869ء میں وہ لندن گئے اور وہاں کے طرزِ تعلیم کا بالخصوص آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے طریقہ تعلیم کا بغور مطالعہ کیا۔ لندن ہی میں اُنھوں نے اپنے خیالات اور منصوبوں کی اشاعت کے لیے ایک رسالہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا اور 1870ء میں لندن سے واپس آتے ہی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ 1873ء میں اُنھوں نے مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کی خاطر ایک کالج قائم کرنے کی اسکیم شائع کی اور 1875ء میں ایم اے او کالج علی گڑھ میں قائم کردیا۔ دوسرے سال وہ پنشن لے کر علی گڑھ آگئے اور 1898ء وہیں وفات پائی۔
سرسید کو ” تقلیدِ مغربی” کے طعنے دینا ہمارے نام نہاد “جدیدی” ادیبوں کا شعار ہو گیا ہے۔ وہ سرسید کے طرزِ عمل کا ذکر اس حقارت سے کرتے ہیں گویا جدیدی حضرات کو اپنی زندگی مغربی تہذیب اور مغربی خیالات کے خلاف جدو جہد میں گزری ہے اور مغربی تہذیب نے ان کو چُھوا تک نہیں ہے حالانکہ مغربی تہذیب کے گندے انڈے ہی ان کے فکر کی خوراک ہیں۔ ہائی ڈیگر اور کیر کے گارد جیسے پرستار انِ مرگ اور حریفانِ عقل ان کے پیر ہیں اوران کے قلم ایذرا پاؤنڈ اور انزیو، ایلیٹ اور جارج آرویل ، کامیو اور کروچے کی مدح و ثنا کرتے نہیں تھکتے۔ سرسید نے مغرب کی روشن خیالیوں سے رشتہ جوڑا تھا مگر ہمارے یہ بزر جمہر مغرب کی ہر انسانیت دشمن تحریک کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہر ظلمت پرست کو بانس پر چڑھاتے ہیں ۔
سرسید نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا اس وقت بیڑا اٹھایا جب زمین مسلمانوں پر تنگ تھی اور انگریز ان کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ وہ توپوں سے اُڑائے جاتے تھے، سُولی پر لٹکائے جاتے تھے،کالے پانی بھیجے جاتے تھے، ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں، نوکریوں کے دروازے ان پر بند تھے اور معاش کی تمام راہیں مسدود تھیں۔
سرسید نے اپنا نصب العین کتابوں سے تیار نہیں کیا تھا بلکہ اس کے پیچھے ان کا تیس سال کا وسیع تجربہ اور ہندوستان کے معروضی حالات کا گہرا مطالعہ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اصلاحِ احوال کی اگر جلد کوشش نہیں کی گئی تو مسلمان ” سائیس، خانساماں، خدمت گار اور گھاس کھودنے والوں کے سوا کچھ اور نہ رہیں گے۔” سرسید نے محسوس کرلیا تھا کہ اونچے اور درمیانہ طبقوں کے تباہ حال مسلمان جب تک باپ دادا کے کارناموں پر شیخی بگھارتے رہیں گے، غیر اسلامی رسوم و رواج کو ترک نہیں کریں گے، توہم پرستیوں ہی کو اصل اسلام سمجھ کر مولویوں کے پیچھے بھاگیں گے اور انگریزی زبان اور مغربی علوم سے نفرت کرتے رہیں گے اس وقت تک بدستور ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ ان کو کامل یقین تھا کہ مسلمانوں کی ان ذہنی اور سماجی بیماریوں کا واحد علاج انگریزی زبان اور مغربی علوم کی تعلیم ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر وہ تمام عمر جدوجہد کرتے رہے۔
سرسید نے حصولِ مقصد کے لیے دو مورچے قائم کیے۔ ایک تنظیمی مورچہ، دوسرا تبلیغی مورچہ، ان کی تنظیمی کوششوں کا شاہکار ایم۔ اے کالج تھا جو ترقی کر کے مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا اور جس کے فیض سے ہزاروں لاکھوں مسلمان انگریزی زبان اور مغربی علوم سے بہرہ اندوز ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ اپنے خیالات کی نشر واشاعت اور مسلمانوں کی ذہنی تربیت کی خاطر اُنھوں نے ” تہذیب الاخلاق” جاری کیا جو اپنے وقت کا سب سے با اثر رسالہ تھا۔ اُنھوں نے اپنی پر خلوص سرگرمیوں سے نہ صرف بے شمار ہمدرد پیدا کیے بلکہ انیسویں صدی کے قریب قریب سب ہی ممتاز ادیبوں اور دانش وروں کا علمی تعاون بھی حاصل کر لیا۔ نواب محسن الملک، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا حالی جو اردو ادب کے ستون ہیں بزمِ سرسید ہی کے شب چراغ تھے۔
سرسید نے جس جوش اور ولولے سے انگریزی زبان اور مغربی علوم کی حمایت کی اُسی جوش اور ولولے سے عربی مدارس اور مروجہ مذہبی تعلیم کی مخالفت کی اور واضح کردیا کہ فی زمانہ یہ مذہبی تعلیم مسلمانوں کے لیے بے مصرف ہی نہیں مضرت رساں بھی ہے۔ مروجہ مذہبی تعلیم پر تنقید کرتے ہوئےوہ لکھتے ہیں کہ
” اب میں نہایت ادب سے پوچھتا ہوں کہ جو جو کتبِ مذہبی اب تک ہمارے ہاں موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں آتی ہیں ان میں سے کون سی کتاب ہے جس میں فلسفہ مغربیہ اور علومِ جدیدہ کے مسائل کی تردید یا تطبیق مسائلِ مذہبیہ سے کی ہو۔ وجودِ سماوات سبع کی ابطال پر جو دلیلیں ہیں ان کی تردید کس کتاب میں لکھی ہے۔ اثباتِ حرکتِ زمین اور ابطالِ حرکت و دَورئی آفتاب پر جو دلیلیں ہیں ان کی تردید کس سے جا کر پوچھیں۔ عناصر اربع کا غلط ہونا جواب ثابت ہوگیا ہے اس کا کیا علاج کریں۔۔۔۔ پس ایسی حالت میں ان (مذہبی) کتابوں کا نہ پڑھنا ان کے پڑھنے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ ہاں اگر مسلمان مردِ میدان ہیں اور اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں تو بے دھڑک میدان میں آویں اور جو کچھ ان کے بزرگوں نے فلسفہ یونانیہ کے ساتھ کیا تھا وہ فلسفہ مغربیہ اور علومِ محققہ جدیدہ کے ساتھ کریں۔ تب ان کا پڑھنا پڑھانا مفید ہوگا ورنہ اپنے مُنھ میاں مٹّھو کہہ لینے سے کوئی فائدہ نہیں”۔39
مگر علمائے دین میں اس چیلنچ کو قبول کرنے کی اہلیت ہی نہ تھی کیوں کہ ” کیا مقلد، کیا اہل حدیث سب تقلید کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان میں مادہ اجتہاد و تحقیق معدوم ہو گیا ہے۔ بس ہر ایک اپنی لکیر پر فقیر ہے اور کولھو کے بیل کی مانند اس حلقے میں چکر کھاتا جاتا ہے جس حلقے میں اس کو آنکھ بند کر کے ہانکا تھا”۔ 40
سرسید کا موقف یہ تھا کہ منقولات کی اندھی تقلید کرنے کے بجائے۔۔۔۔ جو مولویوں کا شیوہ ہے۔۔۔۔ ہم کو اپنے ہر عقیدے ، ہر فکر کو عقل و فہم کی کسوٹی پر کسنا چاہیے کیوں کہ “عقل ہی وہ آلہ ہے جس میں تمام باتوں کی اصلیت کا علم ہوتا ہے اور انسان سچائیوں کی تہ تک پہنچتا ہے۔”41 مگر عقل کو علم کہاں سے فراہم کیا جائے؟ سرسید جو اب دیتے ہیں کہ پرانی مذہبی کتابیں اور درس گاہیں تو اس قابل نہیں البتہ جدید سائنسی علوم سے ہماری عقل کو مناسب غذا مل سکتی ہے کیوں کہ سائنسی سوچ عقل کے مطابق ہے اور قوانینِ قدرت اور مظاہرِ قدرت کی سچی تشریح کرتی ہے۔ سائنس کے انکشافات اور نظریات نے، سائنس کی دریافتوں اور ایجادوں نے کائنات کی اصل حقیقت ہم پر روشن کردی ہے۔ پس ہم کو لازم ہے کہ اپنے عقاید و افکار کا محاسبہ مغربی علوم کی روشنی میں کریں۔ سائنسی علوم سے اُنھوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قوانینِ قدرت کو کوئی ماورائی طاقت نہیں بدلتی نہ ان میں مداخلت کرتی ہے بلکہ دنیا میں جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے خواہ اس کا تعلق مادی اشیا سے ہو یا انسانی معاشرے سے اس کے اسباب دنیاوی ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے دنیاوی مسائل دعا تعویذ، نذر نیاز، منتوں، چڑھاؤں سے یاد درگاہوں کی چوکھٹ چومنے، چلے کاٹنے اور زرپرست پیروں کی جھولیاں بھرنے سے حل نہیں ہوں گے بلکہ ان کی نجات توہمات کے اس طلسم کو توڑنے ہی میں ہے۔ ہم مغربی علوم و افکار اور مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا کر ہی دوسری قوموں کی طرح دنیا میں سر فراز و سُرخ رُو ہو سکتے ہیں۔
مسلمانوں کے روایتی عقاید کی اساس قرآن اور احادیث ہیں مگر سرسید کے علمِ کلام میں احادیث کی گنجائش بہت کم ہے۔ ان کے خیال میں احادیث کی نقل و روایت سے مسلمانوں میں تفرقے پیدا ہوئے اور گمراہیاں پھیلیں۔ وہ اپنی تائید میں حضرت ابوبکررضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
” حضرت ابو بکر رضی اللہ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم رسولِ خدا صلعم کی بہت حدیثیں بیان کرتے ہو اوران میں اختلاف کرتے ہو اور تمھارے بعد کے لوگ بہت زیادہ اختلاف کریں گے۔ پس تم رسولِؐ سے کوئی حدیث نہ بیان کیا کرو۔ جو کوئی تم سے کچھ پوچھے تو کہہ دو کہ ہم میں اور تمھارے میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے۔۔۔ کہا جاتا ہے خود حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جس قدر حدیثیں جمع کی تھیں وہ جلا دی تھیں۔”
” حضرت عمررضی اللہ نے بھی بہت دفعہ اور بہت لوگوں کو آنحضرتؐ سے حدیثوں کی روایت کرنے سے منع کیا اور کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہاں تک کہ ایک دفعہ اُنھوں نے بڑے عالم اور فقیہہ تین صحابیوں کو یعنی ابنِ مسعود، ابو درداء اور ابو مسعود انصاری کو اس لیے کہ وہ آنحضرتؐ سے بہت سی حدیثیں روایت کرتے تھے قید کردیا”۔ 42
اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے سرسید لکھتے ہیں کہ
” اس کے بعد زُہاد اور شائقین فی الخیرات پیدا ہوئے اور اوروں کو بھی زہد و ریاضت و عبادت پر ترغیب دلانے کو اور قیامت کے عذاب کا ڈر جتلانے کو روایاتِ ضعیف اور موضوع کے رواج پر مائل ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے جنت الفردوس کا مِلنا اور ادنیٰ ادنیٰ معصیت پر جہنم میں داخل ہونے کا وعظ کرنے لگے۔ یہ سب رطب ویا بس کتابوں میں جمع ہوگیا ہے۔”
سرسید نے قرآنی آیات کی تاویل عقلی اور سائنسی بنیادوں پر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ” خدا کی بات اور اس کا کام ایک ہونا چاہیے۔” 43 ان کے نزدیک ” خدا کا قول یعنی مذہب اور خدا کا فعل یعنی فطرت، موجودات دونوں ایک ہیں۔”44 دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ قدما نے بھی اسی اصول کی پابندی کی تھی اور موجوداتِ عالم کے جو تصورات ان کے زمانے میں حقائق ثابتہ کا درجہ رکھتے تھے اُنھیں کی روشنی میں قرآن کی تفسیریں لکھی تھیں۔ چوں کہ حقائق ہستی کی جو تفصیلات قرآن میں بیان ہوئیں قریب قریب وہی تورات و انجیل میں موجود تھیں اور عربوں کے عام عقاید بھی وہی تھے لہٰذا ان مفسرین نے آیات قرآنی کے باطنی معنی و مفہوم پر غور کرنے کے بجائے ان کے ظاہری معنی و مفہوم پر اکتفا کی۔ سرسید کا موقف یہ تھا کہ چوں کہ موجوداتِ عالم کے علم نے اب بہت ترقی کرلی ہے اور بیش تر پرانے مفروضات غلط ثابت ہو چکے ہیں لہٰذا ہم کو آیاتِ قرآنی کی تشریح ان نئی معلومات کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس علمائے دین فرماتے تھے کہ موجوداتِ عالم کی جو تشریح سائنس داں کرتے ہیں وہ قرآن سے ٹکراتی ہے۔ مگر کلام خدا چونکہ غلط نہیں ہو سکتا لہٰذا سائنس کی تشریحات لا محالہ غلط ہیں۔ سرسید نے اس منطق کو تسلیم نہیں کیا ۔ وہ کہتے تھے کہ
موجوداتِ عالم کی سائنسی نشریحیں سچی اور ثابت شدہ ہیں لہٰذا ہم کو کلام خدا کے معنی و مفہوم انھیں سچائیوں سے متعین کرنے ہوں گے۔ چنانچہ انھوں نے کائنات کی تخلیق، آدم و حوا کا، ہبوطِ آسمان، انبیا، وحی اور الہام کی اصل حقیقت، فرشتے، جن اور شیطان، لوح و قلم، نوشتہ تقدیر، میزان و معاد، حشر ونشر، جبرو اختیار، معراج معجزہ اور کرامات، نماز و دعا وغیرہ کی عقلی تشریحیں کیں۔ حضرت موسٰیؑ، حضرت نوحؑ اور دوسرے نبیوں کےقصوں میں جو واقعات قانونِ قدرت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں جیسے یدِبیضا، عصا کا اژدہا بن جانا، فرعون کے لشکر کا غرق ہونا، خدا کا موسیٰ سے کلام کرنا، پہاڑ پر تجلی ہونا، گئوسالہ سامری کا بولنا، من و سلویٰ کا اُترنا یا عیسیٰ کا گہوارے میں کلام کرنا، مُردوں کو زندہ کرنا اور اندھوں ، کوڑھیوں کو چنگا کرنا، ان باتوں کی تاویل بھی سرسید نے نئے انداز میں کی۔ قرآن میں چورکی سزا ہاتھ کاٹنا لکھا ہے مگرسرسید احمد خان کہتے تھے کہ یہ سزا لازمی نہیں ہے ” کیوں کہ لازمی ہوتی تو فقہا اس کو مالِ مسروقہ کی ایک خاص مقدار کے ساتھ مشروط نہ کرتے اور نیز صحابہ کے وقت میں متعدد موقعوں پر سارق کو صرف قید کی سزا نہ دی جاتی۔” مولانا حالی نے حیاتِ جاوید میں 51 اُن امور کی نشان دہی کی ہے جن کے بارے میں سرسید نے مروجہ اسلامی عقاید سے اختلاف کیا اور ان کی سائنسی اور عقلی تشریحیں پیش کیں۔
سرسید کی سوچ سیکولر تھی۔ وہ دینی امور کو دنیاوی امورسے الگ کر کے دیکھتے تھے۔ انھوں نے اس موضوع پر اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے ایک مضمون بھی لکھا تھا۔ بحث کی ابتدا وہ توریتِ موسوی سے کرتے ہیں جس میں دنیاوی احکام کثرت سے پائے جاتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ” حضرتِ موسیٰ کے تمام دنیوی احکام مثل ایک انسان کے احکام کے ہیں جو بہ صلاح بعض دانش مندوں کے اور بطور انتظام مناسب وقت و حالاتِ قوم کے دیے گئے ہوں” مگر ” بنی اسرائیل نے تمام دنیاوی احکام کو جو درحقیقت مذہب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے تھے مذہب میں شامل کرلیا اور پھر اس کے مقاصد کو چھوڑ کر صرف لفظی معنوں کی پیروی کرنا ٹھیٹ یہودی مذہب قرار پایا”۔ 45
فقہائے اسلام نے بھی دینی اور دنیاوی امور کو آپس میں گڈ مڈ کر کے جو غلطی کی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سرسید لکھتے ہیں کہ” عرب کی تمام قوموں کا یہ طریقہ تھا کہ جس کو شیخ یا سردارِ قوم قرار دیتے تھے، تمام دنیاوی امور میں بھی اس کی اطاعت کرتے تھے اوراسی کے حکم پر چلتے تھے۔ پس بطور قدرتی امر کے ضروری تھا کہ تمام قومِ عرب آنحضرتؐ کو اپنا دنیاوی سردار بھی قرار دیں اور آنحضرتؐ کو بھی مجبوراً دنیاوی سرداری اختیار کرنی لازم تھی مگر جس طرح کہ حضرتِ موسیٰؑ میں دو منصب جدا جدا جمع ہو گئے تھے اسی طرح آنحضرتؐ میں بھی دو جداگانہ منصب جمع تھے۔
” دنیاوی سرداری کے متعلق آنحضرتؐ بھی مثل حضرت موسیٰؑ کے اپنے صحابہ کےمشورے سے اور ضرورت و مصلحتِ وقت کے لحاظ سے احکام صادر فرماتے تھے اور یا تو یہودیوں کی پیروی سے یا اسی لازمی نتیجے سے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا آنحضرتؐ نے بھی دنیاوی امور کی نسبت جو کچھ کیا یا فرمایا بطور ربانی احکام کے سمجھا گیا اور لوگوں نے ” وانتم اعلم با مورو نیاکم” کو ایک لخت بھلا دیا۔
” مسلمان عالموں نے قدم بہ قدم یہودیوں کی پیروی کی اور تمام دنیاوی احکام کو جو در حقیقت مذہب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے تھے مذہب میں شامل کرلیا اور پھر یہودیوں کی تقلید سے اس کے مقاصد کو چھوڑ کر صرف لفظی معنوں کی پیروی کرنا ٹھیٹ مذہبِ اسلام قرار پایا”۔46
اس کے بعد سرسید ان علما پر گرجتے برستے ہیں جن کے مذہب میں دو انگل اونچی ازار پہننے سے بہشت ملتی ہے اور دو انگل نیچی پہننے سے دوزخ میں ڈالا جاتا ہے۔ ” غرضیکہ انسانوں کی بد بختی کی جڑ دنیاوی مسائل کو دینی مسائل میں جو ناقابلِ تغیر و تبدل ہیں شامل کرلینا ہے۔” وہ اپنی سیکولر سوچ پر اس سختی سے قائم ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ ” دنیاوی معاملات کو دینی معاملات میں ملا لینا جنون ہے۔” کیوں کہ ” دینی احکام کا نیچر دنیاوی احکامِ معاشرت سے بالکل مختلف ہے۔۔۔۔ امورِ معاشرت و تمدن جو روز بروز تبدیل ہوتے جاتے ہیں پس وہ داخلِ احکامِ مذہبی نہیں ہو سکتے”۔ 47
اور مضمون کا خاتمہ وہ ان فقروں پر کرتے ہیں کہ ” قرآن کا ہر ایک لفظ احکامِ مذہبی سے علاقہ نہیں رکھتا۔ اگر میں اپنے ہم نام مُلا احمد جونپوری کی تفسیرِ آیاتِ احکام ہی کو تسلیم کرلوں تو صرف پانسو آیاتِ احکام اس میں ہیں اور درحقیقت اتنی بھی نہیں۔ پس دنیاوی امور کا قرآن مجید میں ذکر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوسکتا کہ دنیاوی معاملات بھی مذہب میں داخل ہیں۔”
سرسید کے مضامین ” تہذیب الاخلاق” میں شائع ہونے لگے تو قدامت پرست حلقوں میں کہرام مچ گیا اور اسلام خطرے میں ہے کی دہائی دی جانے لگی۔ بس پھر کیا تھا سرسید پر ہر سمت سے تہمتوں اور دشنام طرازیوں کے تیر برسنے لگے۔ کسی نے کہا کہ سید احمد خان کرسٹان ہوگیا ہے، کسی نے کہا یہ ملحد، نیچری، کافر اور دجال لائقِ قتل ہے۔ اس کے کالج کے لیے چندہ دینا اور لڑکوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجنا ناجائز ہے۔ تہذیب الاخلاق کے جواب میں کئی اخبار نکالے گئے اور اشتہار جاری کیے گئے کہ سید احمد خان سے کوئی نہ ملے نہ ان کے ساتھ کھانا کھاوے اور جو ایسا کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مولویوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کی بلکہ مولوی امداد العلی نے ملک کے بڑے برے شہروں کے علمائے دین سے فتوے جمع کیے اور ایک رسالہ ” امداد الافاق برجم اہل النافق بہ جواب پرچہ تہذیب الاخلاق” چھاپ کر تمام ہندوستان میں مفت تقسیم کیا ۔ مولوی عبدالحئی فرنگی محل اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ
” وجودِ شیطان اور اجنّہ منصوص قطعی ہیں اور منکر اس کا شیطان ہے بلکہ اس سے بھی زائد۔۔۔۔ اور وجودِ آسمان منصوصِ قرآنی ہے، منکر اس کا مبتلائے و سواسِ شیطانی ہے۔ مذہب نیچر خدا جانے کیا بلا ہے۔ ہر متشرع اور متدین کو اس کے قبول سے اِبا ہے۔۔۔ ہر مسلمان کو حق جل شانہ ، اتباعِ شریعتِ محمدیہ پر قائم رکھے اور مذہب نیچر اور مشرب بدتر سے محفوظ رکھے۔ جو شخص محزبِ دین ، ابلیس لعین کے وسوسے سے صورتِ اسلام میں تخریبِ دینِ محمدی کی فکر میں ہے اور بنام تجدیدِ مدرسہ جدیدہ افسادِ شریعت اس کی منظورِ نظر ہے، جو چیزیں کہ اس کے نزدیک موجبِ تہذیب ہیں اہلِ سنت کے نزدیک باعثِ تخریب ہیں۔” 48
اگرچہ دِلّی، رام پور، امروہہ، مراد آباد، بریلی، لکھنو، بھوپال وغیرہ کے ساٹھ عالموں، مولویوں اور واعظوں نے کفر کے فتووں پر دستخط کیے تھے مگر صرف خدا کی طرف سے اس کی تصدیق اور تصویب باقی رہ گئی تھی سو مولوی علی بخش خان نے یہ کمی پوری کردی۔ انھوں نے حجاز جا کر مکّے کے چاروں فقہوں کے چاروں مفتیوں سے سر سید کے خلاف فتویٰ حاصل کیا جس میں ان مفتیوں نے سر سید کے لیے ” ضرب و حبس” کی سزا تجویز کی تھی۔ مدینہ منورہ کے مفتی احناف شیخ محمد امین بابی نے اپنے فتوے میں سر سید کی سزا اور بڑھا دی اور ان کو واجب القتل قرار دے دیا لیکن خیریت گزری کہ سید احمد خان ہندوستان میں تھے۔ اگر عثمانی سلطنت کی رعیت ہوتے تو شاید قتل کر دیے جاتے۔ مولانا حالی حیاتِ جاوید میں لکھتے ہیں کہ مولویوں کے اشتعال دلانے پر بعض سر پھروں نے سرسید کو قتل کرنے کی تیاری بھی کرلی تھی مگر ارادے کو عمل میں لانے کی نوبت نہیں آئی البتہ گالیوں اور دھمکیوں کے خطوط سرسید کے پاس آخر تک آتے رہے۔
سر سید کے سیکولر خیالات کو وہ مقبولیت نصیب نہیں ہوئی جس کی ان کو توقع تھی۔ اس کی بڑی وجہ حالات کی ناسازگاری تھی۔ سیکولر خیالات صنعتی نظام کے ماحول میں جڑ پکڑتے اور بار آور ہوتے ہیں کہ فیوڈل ماحول میں چنانچہ سیکولر خیالات اور اداروں نے کلکتہ، بمبئی اور مدارس میں جہاں صنعتی ماحول تھا نسبتاً زیادہ ترقی کی جب کہ سر سید اُس خطے میں سیکولرازم کی تبلیغ کررہے تھے جو خالصتاً فیوڈل تھا اور جہاں کے مسلمانوں کی فکری اور تہذیبی قدریں بھی فیوڈل تھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سیکولرازم کا نازک پودا اس سرزمین سے از خود نہیں اگا تھا بلکہ سات سمندر پار سے یہاں لایا گیا تھا اور لانے والے بھی غیر ملکی آقا تھے جن کی اچھی باتیں بھی لوگوں کو بری لگتی تھیں اور جن کی طرف سے ہر دم یہ خدشہ رہتا تھا کہ؎
ساقی نے کچھ مِلا نہ دیا ہو شراب میں
کالجوں اور اسکولوں میں انگریزی تو مجبوراً پڑھنا پڑتی تھی کہ اس کے بغیر سرکاری نوکری نہیں مل سکتی تھی نہ کارو بار چل سکتا تھا لیکن لوگ مغربی خیالات کو قبول کرنے پر مجبور نہ تھے
مزید برآں سرسید کی تعلیمی پالیسی بڑی ناقص تھی ان کی نظرمیں آکسفورڈ اور کیمبرج مثالی یونیورسٹیاں تھیں۔ جن میں اونچے طبقے کے نوجوان تعلیم پاتے تھے اور بعد میں پارلیمنٹ کے رکن، وزیر، سفیر یا سول سروس کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے تھے۔ سرسید بھی چاہتے تھے کہ ایم اے او کالج کی روش یہی ہو اور مسلمان طلبا وہاں سے نکل کر ڈپٹی کلکٹر، جج اور کپتان پولیس بنیں۔ کامرس، انجینئرنگ اور ڈاکٹر جیسے آزاد پیشوں کی طرف ان کا ذہن کبھی نہیں گیا حتیٰ کہ انھوں نے ٹیچرس ٹریننگ کالج بھی قائم نہ کیا۔ اس فروگزاشت کا سبب ممکن ہے کہ وسائل کی کمی ہو لیکن ہم کو ان کی تحریروں مین بھی صنعتی نظام کی اہمیت اور افادیت کا ذکر نہیں ملتا۔ نہ وہ لوگوں کو فیکٹریوں اور ملیں لگانے کی تلقین کرتے ہیں نہ ان کو تجارت یا ٹیکنیکل علوم و فنون کی ضرورت کا احساس ہے۔ ان باتوں کو اگر کہیں ذکر ہے تو برسبیلِ تذکرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ سرسید نے مغربی تہذیب ہی کو مغربی تمدن سمجھ لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں نے اگر انگریزی زبان سیکھ لی اور مغربی تہذیب اپنا لی تو ان کے اقتصادی اور سیاسی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے (مسلمانوں سے ان کی مراد اورنچے اور درمیانہ طبقے کے افراد تھے) اس لحاظ سے وہ مرزا غالب کی فکری سطح تک نہیں پہنچ سکے جنھوں نے سرسید کو مغربی تمدن کو قبول کرنے کا مشورہ دیا تھا اور صنعتی نظام کی خوبیاں بتائی تھیں، انگریزوں کے طرزِ طعام و لباس کی ثنا خوانی نہیں کی تھی۔
برطانوی حکومتِ ہند کی غیر مشروط اطاعت و فرماں برداری سرسید کا مسلک تھی۔ وہ برابر یہی کوشش کرتے رہے کہ مسلمان ملکی سیاست سے دُور رہیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو انگریزوں کی ناراضگی کا باعث ہو۔ وہ کالج کے لڑکوں کو بھی سیاسی مسائل میں دل چسپی لینے اور سیاسی بحثوں میں الجھنے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ احتیاط کی حد یہ تھی کہ تہذیب الاخلاق کا داخلہ بھی کالج میں بند تھا۔ طرفہ تماشایہ تھا کہ انھوں نے ایک انگریز مسٹربک کو کالج کا پرنسپل مقرر کررکھا تھا جو نہایت قدامت پرست شخص تھا۔ اس کو سرسید کے مزاج میں اوران کی سیاسی پالیسی وضع کرنے میں بڑا دخل تھا۔ غالباً اسی کے مشورے سے سرسید نے مسلمانوں کو ملکی سیاست اور نئے تمدنی دھارے سے الگ رہنے کا مشورہ دیا اور جو سیکولر ادارے نئے ماحول میں نشو ونما پارہے تھے ان میں شرکت سے باز رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علی گڑھ سے انگریزی داں تو کھیپ کے کھیپ نکلے مگر روشن خیال شاذو نادر۔ غالب اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کی ذہنیت غلامانہ تھی اور غلامانہ ذہنیت سے روایت پرستی کو تقویت ملتی ہے نہ کہ سیکولرازم کو۔
علی گڑھ تحریک کی ان خامیوں کے باوجود ہندوستان کے تعلیم یافتہ مسلمان سیکولر فکر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ علمِ سیاستِ مدن کے اصولوں سے پہلی بار واقف ہوئے۔ ری پبلک کیا ہے، جمہوریت کس کو کہتے ہیں، اقتدارِ اعلیٰ سے کیا مراد ہےے، تقسیمِ اختیار کے اعتبار سے ریاست کے عناصر ثلاثہ کون کون سے ہیں، مجلس قانون ساز کے حقوق و فرائض کیا ہیں اور اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، حق رائے دہی کیا شے ہے، نمائندہ حکومت کیسے بنتی ہے، قومی حق خودارادیت کے کیا معنی ہیں، وفاقی اور وحدانی ریاستوں میں کیا فرق ہے، صوبائی خود مختاری کی تعریف کیا ہے، بنیادی حقوق کیا ہیں اور کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، سیاسی پارٹیاں کیوں اور کیسے تشکیل پاتی ہیں یہ سوالات سیکولر علوم سے آگہی کی بدولت لوگوں کے ذہنوں میں ابھرے اور سیکولر علوم اور سیکولر اداروں کے تجربے ہی نے ان سوالوں کے جواب فراہم کیے۔ نہ وید اور پران نے رہبری کی، نہ توریت و انجیل نے اور نہ امام غزالی اور امام مخرالدین رازی نے۔ سیکولرازم کے نام چڑنے والے ہمارے سیاست داں حضرات یہ محسوس نہیں کرتے کہ ان کے نُطق و لب سے نکلا ہوا ہر سیاسی کلمہ سیکولر فکر ہی کی ترجمانی کرتا ہے ورنہ اہلِ مشرق کے فرشتوں کو بھی ان باتوں کی خبر نہ تھی۔
صورتِ احوال یہ ہے کہ وہی حلقے جو کل تک بڑے فخر سے دعویٰ کرتے تھے کہ ان تصورات کا مخرج و منبع اسلام ہے اور مسلمانوں ہی نے یہ باتیں یورپ والوں کو سکھائیں آج بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے اپنے ہی دعوؤں کی تردید کررہےے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں غیر اسلامی ہیں، اسلام کا اپنا مخصوص سیاسی نظام ہے جس کی اساس امیر کی اطاعت ہے خواہ امیر نے اقتدار بزورِ شمشیر کیوں نہ حاصل کیا ہو اور مجلس شوریٰ کو کسی فردِ واحد نے ہی کیوں نہ نامزد کیا ہو۔ ہم گھوم پھر کر ایک صدی پیچھے پہنچ گئے ہیں جب وائسرائے ہند اپنی کو نسل نامزد کیا کرتا تھا اور سر سید مسلمانوں کو حکومتِ ہند کی اطاعت کا سبق پڑھایا کرتے تھے۔
سیکولر فکر کی جمہوری قدروں کے بارے میں ہم نے ابھی ابھی جو دعوے کیے وہ تاریخی حقیقتوں پر مبنی ہیں چنانچہ مسٹر الطاف گوہر کو بھی ہر چند کہ وہ سیکولرازم کے سخت مخالف ہیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ
” سیکولر معاشرے کے ممتاز ادارے، 1۔ وہ مقنّہ ہے جو آزاد اور غیر جانب دار الیکشن کے عمل کے ذریعے وجود میں آئے۔ 2۔ وہ عدلیہ ہے جس کو مرکزی اور خود مختاری مرتبہ حاصل ہو۔3۔ وہ انتظامیہ ہے جو عدلیہ اور عدالتی حاکمیت کی اطاعت کرتی ہو۔ 4۔ وہ پریس ہے جو رائے عامہ کے اظہارو تشکیل کا مقبول حربہ ہے”۔49
موصوف کی رائے میں یہ ادارے سیکولرازم کا ” اعلیٰ نصب العین ہیں۔۔۔ جن کے لیے سیکولر سوسائٹی نے اپنے آپ کو وقف کردیا تھا”۔ مگران کو مغرب کی سیکولر سو سائٹیوں سے شکوہ ہے کہ انھوں نے اپنے نصب العین سے بے وفائی کی بالخصوص مشرق میں جہاں سامراجی طاقتوں نے سیکولر اصولوں پر عمل نہیں کیا۔ اغیار کا گِلہ شِکوہ بجا و درست لیکن آزادی کے بعد پاکستان میں ان اصولوں سے جو بے وفائیاں اپنوں نے کیں ان کا شکوہ ہم کس سے کریں؟ الطاف گوہر صاحب ایک زمانے میں پاکستان کے سیکریٹری اطلاعات اور فیلڈ مارشل ایوب خان کی ناک کے بال تھے۔ ان کے عشرہ ترقی” کے دوران “سیکولر سوسائٹی کے ممتاز اداروں” کو جس بے دردی سے نیست و نابود کیا گیا اس سے مسٹر الطاف گوہر سے زیادہ کون واقف ہوگا۔ ملکی آئین کی منسوخی، مارشل لاء کا نفاذ، اسمبلیوں اور وزارتوں کی برطرفی، شہری حقوق کی ضبطی، اخباروں پر کڑی سنسر شپ، ہزاروں بے قصور افراد کی گرفتاری اور ادیبوں ، دانش وروں اور صحافیوں کے ضمیر کی خریدوفروخت؎
مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا تمھیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو
مسٹر الطاف گوہر نے اپنے ایک مقالے میں مغرب کے اخلاقی اور روحانی انحطاط پر بڑی تفصیل سے تبصرہ کیا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ ” سیکولر سوسائٹی اور سیکولر ادارے شکست و ریخت کی حالت میں ہیں۔”50 سرمایہ داری نظام کے داخلی تضاد اور دیوالیے پن کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں الطاف گوہر صاحب نے ان کی ذمہ داری سیکولرازم کے سرتھوپ دی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ بندہ نواز سیکولرازم کے جن اصولوں کے آپ خود معترف ہیں سرمایہ دار طبقہ اگر ان سے ” غداری” کرتا ہے تو اس میں سیکولرازم کا کیا قصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب کے اخلاقی اور روحانی انحطاط کا بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ وہاں کا سرمایہ داری نظام سیکولرازم سے غداری کررہا ہے۔ اگر زوالِ مغرب کا باعث سیکولر خیالات ہوتے تو وہ اخلاقی یا روحانی خرابیاں جن میں مغرب مبتلا ہے سوشلسٹ ملکوں اور عوامی جمہوریتوں میں بھی عام ہوتیں کیونککہ یہ معاشرے تو زیادہ ہی سیکولر ہیں مگر کیا کسی نے سنا کہ سویت یونین یا چین یا ویت نام یا کیوبا یا ہنگری وغیرہ میں بھی مغرب کے سرمایہ دار ملکوں کی طرح نائٹ کلب جوئے خانے کھلے ہوئے ہیں یا عیاشی کے اڈے قائ ہیں یا عورتیں سڑکوں پر کھڑی اپنے جسم کا سودا کرتی رہتی ہیں یا بیسواؤں کے محلے آبا د ہیں یا غنڈے مدمعاش چرس پی کر راہ گیروں کو لوٹتے مارتے ہیں یا سر مُنڈے لونڈے کالے لوگوں کو چھرے چاقو سے حملے کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں اور ان کے گھروں، دکانوں کو آگ لگاتے ہیں ۔ کیا کبھی کسی نے سنا کہ وہاں بھی بینکوں پر دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں اور رات کے وقت سنسان سڑکوں پر چلنا خطرناک ہے، کیا کبھی کسی نے سنا کہ سوشلسٹ ملکوں میں بھی جرائم پیشہ گروہ پولیس سے مل کر اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ کیا سوشلسٹ ملکوں میں بھی لوگ ذریعہ معاش کی بے یقینی کے باعث ضبطِ تولید پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہاں بھی لاکھوں کروڑوں ہٹے کٹے لوگ ذہنی اور اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا نرخ بالا کرنے کی غرض سے گیہوں، آلو اور کافی کے ذخیرے ضائع کردیے جاتے ہیں۔ کیا وہاں بھی کروڑوں بے روزگاروں کی ” محفوظ فوج” جنگ کا ایندھن بننے کی خاطر موجود ہے۔ کیا ان ملکوں میں بھی ہر پانچویں ساتویں برس اقتصادی بحران آتا رہتا ہے اور مہنگائی اور افراطِ زر نے لوگوں کی زندگی اجیرن کردی ہے۔
اگران سوالوں کا جواب نفی میں ہے اور لازماً نفی میں ہوگا تو ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بہ جانب ہوں گے کہ الطاف گوہر صاحب نے مشرق و مغرب کے سرمایہ دار حلقوں سے اپنے گہرے ربط کی وجہ سے اصل مجرم یعنی سرمایہ داری نظام کی نشان دہی سے گریز کیا ہے اورسیکولرازم کو قصور ٹھہرایا ہے۔
مسٹرالطاف گوہر فرماتے ہیں کہ 1۔ سیکولرازم اور اسلام میں کوئی شے مشترک نہیں ہے۔2۔ سیکولرازم اسلام کی مکمل ضد ہے کیوں کہ سیکولرازم خدا، الہام اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتی۔3۔ سیکولرازم کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ دنیا میں مادی خوش حالی انسانی مسرت کا اہم ذریعہ ہے۔51
ہم فاضل مضمون نگار سے پوچھتے ہیں کہ جنابِ والا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اورسیکولرازم میں کوئی چیز مشترک نہیں تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام منتخب شدہ مقنّہ کے خلاف ہے یا اسلام آزاد عدلیہ کے خلاف ہے یا اسلام منتخب شدہ انتظامیہ کے خلاف ہے یا اسلام پریس کی آزادی کے خلاف ہے یا اسلام شہریوں کے بنیادی حقوق اور جمہوریت کے خلاف ہے۔ کیوں کہ سیکولرازم کے بنیادی اصول آپ کے بقول یہی ہیں۔اگرآپ کا جواب اثبات میں ہے تو آپ کے اسلام اور سیکولرازم میں واقعی کوئی چیز مشترک نہیں ہے مگر جس اسلام کی آپ وکالت کررہے ہیں وہ تیل کے مالکوں اور ان کے خیمہ برداروں کا اسلام ہو تو ہو عام مسلمانوں کا اسلام ہرگزنہیں ہے۔
جہاں تک خدا، الہام اور آخرت پر ایمان کا تعلق ہے تو عرض یہ ہے کہ سیکولرازم کا دائرہ فکر و عمل مذہبی عقاید سے متصادم نہیں بلکہ الگ ہے۔ سیکولرازم کو کسی فرد ، جماعت یا معاشرے کے مذہبی عقاید سے کوئی سروکار نہیں۔ سیکولرازم کا مسلک وہی ہے جو سر سید کا ہے یعنی دین امور اور دنیاوی امور کے تقاضے اور دائرہ کا ر جدا جدا ہیں لہٰذا نہ ریاست کو اپنے باشندوں کے مذہبی عقاید میں مداخلت کرنی چاہیے اور نہ مذہب کو ریاستی امور میں دخل دینا چاہیے۔
اس کلیے کی بنا پر سیکولر ریاست کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ فرد اور جمعیت کو مذہبی آزادی کی پوری پوری ضمانت دے اور اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی گروہ یا طبقہ کسی دوسرے کی مذہبی آزادی کو غصب نہ کرنے پائے۔ سیکولر ریاست میں ہر شخص بِلا لحاظِ مذہب مساوی درجے کا شہری ہوتا ہے۔ سیکولر ریاست کسی شہری کے مذہبی معاملات میں دخیل نہیں ہوتی نہ کسی کو مذہبی عقاید کی پابندی کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ سیکولر ریاست آئینی طورپر کسی مذہب سے وابستہ بھی نہیں ہوتی نہ کسی مخصوص فرقے کے عقاید کو فروغ دیتی ہے۔ اس تصور کے پیش نظر فرد، ریاست اور مذہب کے مابین رشتوں کی تین جوڑیاں بنتی ہیں۔52
1۔ فرد اور مذہب
2۔ فرد اور ریاست
3۔ مذہب اور ریاست
1۔ فرد اور مذہب پر غور کرتے وقت بقیہ دونوں رشتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ یہ رشتہ ریاست کے وجود میں آنے سے ہزاروں برس پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی دنیا کے بعض گمنام گوشوں میں ایسے قبیلے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مذہب ضرور ہے مگر ان کی زندگی میں ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان کو نہ ریاست کے وجود کی پروا ہے نہ وہ ریاستی قوانین کے تابع ہیں۔ یہودی مذہب ، دینِ مسیحی اوراسلام کی تاریخ بھی شاہد ہے کہ فرد اور مذہب کا رشتہ ریاست سے منسلک نہیں ہے۔ شریعتِ موسوی اس وقت نازل ہوئی ب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کررہے تھے اور اسرائیلی ریاستوں کا نام و نشان نہ تھا۔ گوتم بدھ نے چھٹی صدی قبلِ مسیح میں بدھ مت کا پرچار شروع کیا لیکن پہلی بُدھ ریاست تین سو سال بعد اشوکِ اعظم نے قائم کی۔ عیسائی مذہب کی تاریخ بھی یہی ہے۔ چنانچہ پہلی عیسائی ریاست حضرت مسیح کے تین سو سال بعد فلسطین سے سینکڑوں میل دور قسطنطنیہ میں قائم ہوئی۔ خود اسلام کا ظہور کسی ریاست کا مرہونِ منت نہیں بلکہ مکے میں تو جہاں آنحضرتؐ نے اسلام کا اعلان فرمایا اسلام کے دشمنوں کا غلبہ تھا۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر سات سو سال حکومت کی لیکن دہلی، یوپی اور بہار میں مسلمانوں کی آبادی 14 فیصد سے کبھی آگے نہ بڑھی۔ اگر اسلام کا دارومدار ریاست کی قوتِ قاہرہ پر ہوتا تو کم از کم شمالی ہند میں ہندو مذہب کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہتا۔ انڈونیشیا، ملایا، سری لنکا، برما، تھائی لینڈ اور فلپائن میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں مگر وہ ریاست کے دباؤ سے تو مسلمان نہیں ہوئے۔ انگریزوں نے یہاں ڈیرھ دو سو سال تک راج کیا لیکن وہ کے فیصد ہندوستانیوں کو عیسائی بنا پائے۔ پس معلوم ہوا کہ مذہب کا دارو مدار ریاست پر نہیں ہے۔ اگر مودودی صاحب اسلام کے لیے ریاست کی قوتِ قاہرہ کو ضروری سمجھتے ہیں تو وہ مذہب اور ریاست دونوں کی تاریخ سے نا واقفیت کا ثبوت دیتے ہیں۔
اگر ہم ریاست اور مذہب کے رشتے سے صرفِ نظرکرلیں تو فرد کی مذہبی آزادی کا تصور نمایاں ہو جاتا ہے۔ ریاست اس رشتے سے بے تعلق ہو جاتی ہے۔ ریاست کے ہر باشندے کو اختیار ہوتا ہے کہ جس مذہب کو چاہے قبول کرے اور جس کو چاہے رد کرے۔ اگر کوئی شخص خدا، الہام اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو شوق سے رکھے۔ ریاست کو اس سے باز پُرس کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ریاست کسی خاص مذہبی رسم یا مذہبی فریضے کی حمایت یا مخالفت میں قانون نافذ کرنے کی مجاز نہیں ہوتی البتہ اس کو یہ حق ضرور ہوتا ہے کہ امن عامہ کے تحفظ یا حفظانِ صحت کے اصولوں کے پیش نظر مذہبی رسوم کی ادائیگی کے ضابطے مقرر کردے مثلاً حج کے ضابطے، مذہبی جلسوں جلوسوں کی نگرانی یا دل آزار تقریروں، تحریروں کی ممانعت مگر ریاست کو مذہبی تنظیموں پر یا مذہبی عقاید کی تبلیغ و اشاعت پر پابندیاں عاید کرنے کا حق نہیں ہوتا۔
فرد اور ریاست کے رشتے پر غور کرتے وقت ہم کو تیسرے عنصر یعنی مذہب کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ ریاست میں فرد کی حیثیت شہری کی ہوتی ہے اوراس کے شہری حقوق مذہبی عقاید سے متعین نہیں ہوتے۔ ریاست کی نظر میں ہندو، مسلمان، عیسائی، پارسی، شہری ہونے کی حیثیت سے برابر ہوتے ہیں۔ ریاست کسی ایک مذہب کے شہری کو دوسرے مذہب کے شہری پر فقط مذہب کی بنا پر ترجیح نہیں دے سکتی نہ ایسے قانون وضع کر سکتی ہے جس سے ایک مذہب والوں کو فائدہ اور دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ریاست کسی مذہب سے امتیازی سلوک بھی نہیں کرسکتی نہ ایسا نصابِ تعلیم جاری کرسکتی ہے جس کسی مخصوص مذہب یا فرقے کی جانب داری یا مخالفت مقصود ہو اور نہ کسی فرقے پر کوئی مخصوص ٹیکس لگاسکتی ہے۔
فرد، ریاست اورمذہب کے رشتوں کی شکل ایک مثلث کی ہے جس کا بالائی سرِا افراد کی نمائندگی کرتا ہے اور زیریں گوشے ریاست اور مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں ۔
فرد
مذہب ریاست
مذہب کی آزادی کا تعلق فرد سے ہے لہٰذا ریاست کا پہلو اس سے خارج ہے۔ فرد کے شہری حقوق کا تعلق ریاست سے ہے لہٰذا مذہب کا پہلو اس سے خارج ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ریاست مذہب سے جدا ہو۔ ریاست اور مذہب میں جتنا قریبی تعلق ہوگا فرد کی مذہبی اور شہری آزادیاں اسی نسبت سے متاثر ہوں گی۔ اس کے برعکس مذہب ریاست سے جتنا دُور ہوگا مذہب اور ریاست دونوں کو آزادی سے ترقی کرنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع ملیں گے۔
مسٹر الطاف گوہر کے اس الزام کو کہ سیکولرازم کے نزدیک دنیاوی خوش حالی انسانی مسرت کا اہم ذریعہ ہے ہم اقراری مجرم بن کربہ خوشی تسلیم کرتے ہیں مگر مجرموں کے کٹہرے میں ہم اکیلے نہ ہوں گے بلکہ کروڑوں فاقہ کش مسلمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ سب لوگ جن کی دِلی آرزو ہے کہ دنیا میں آرام اور عزت و آبرو کی زندگی بسر کریں مگر جن کے شب و روز روٹی ، روزگار کی تلاش میں گزرتے ہیں، جن کے بچے تعلیم سے محروم ہیں اور جن کے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ ہے نہ دوا علاج کے لیے دام ہیں۔ ہماری صفوں میں وہ بزرگ ہستیاں بھی ہوں گی جنھوں نے اپنی زندگی مسلمانوں کی دنیاوی حالت درست کرنے کی کوششوں میں گزار دیں۔ ہمارے ساتھ سرسید بھی ہوں گے اور علامہ اقبال بھی اور مسٹر محمد علی جناح بھی۔
شکر ہے کہ محکوم ملکوں کے مسلمانوں کی سوچ مسٹر الطاف گوہر کی مابعد الطیعیاتی سوچ سے مختلف تھی ورنہ الجزائر اور لیبیا، شام و یمن ، ایران اور انڈونیشیا کبھی آزاد نہ ہوتے نہ پاکستان وجود میں آتاکیوں کہ ان ملکوں میں آزادی کی جنگ مسلمانوں کی دنیا سنوارنے اوران کو خوش حالی اور ترقی کے موقعے فراہم کرنے کے لیے لڑی گئی تھی نہ کہ عاقبت درست کرنے کی خاطر۔ اگردنیاوی زندگی کی مسرت و شادمانی مقصود نہ ہوتی تو آزادی کی کیا ضرورت تھی۔ ہم انگریزوں کے غلام تھے مگر انھوں نے ہم کو شرعی احکام پر عمل کرنے سے کبھی نہیں روکا نہ اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی۔ انھوں نے ہم کو خدا، الہام اور آخرت پر یقین رکھنے سے منع نہیں کیا نہ کبھی یہ کہا کہ تم نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور حج کرنا ترک کردو۔پھر مسلمانوں نے تحریکِ پاکستان میں کیوں حصہ لیا؟ پاکستان کیوں بنایا؟
کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ یہ شوشہ جماعتِ اسلامی نے چھوڑا ہے جو تحریکِ پاکستان کے سخت خلاف تھی اور پاکستان کو ” نا پاکستان” کہتی تھی۔ چنانچہ جسٹس محمد منیر مرحوم نے اپنی کتاب From Jinnah to Zia میں جماعتِ اسلامی نے اپنے ماضی کے داغ دھونے اور نئی نسل کو (جس تحریک پاکستان کا ذاتی تجربہ نہیں) گمراہ کرنے کی خاطر یہ نعرہ 1953ء میں وضع کیا تھا۔ ورنہ مسلم لیگ کی دستاویزیں اور قائدِاعظم اور تحریک پاکستا کے دوسرے ممتاز رہنماؤں کے بیانات گواہ ہیں کہ تحریکِ پاکستان ایک سیاسی تحریک تھی جو قومی حق خود ارادیت کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی اور جس کا مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو اپنی خود مختار ریاستیں بنانے کا حق دیا جائے مگر قومی حق خودارادیت مغرب کا خاصل سیکولر نظریہ ہے جو وہاں اٹھارویں صدی میں قومی ریاستوں کے وجود کے دوران وضع ہوا۔ اسی نظریے کے مطابق اٹلی، یونان، جرمنی، فرانس، ہالینڈ، بلجیم اور امریکا غرضیکہ بے شمار مغربی ریاستیں وجود میں آئیں۔ اسی نظریے کے مطابق پہلی جنگِ عظیم کے بع مجلس اقوام نے یورپ ہنگری ، چیکو سلوواکیہ، رومانیہ، بلغاریہ اور یوگو سلاویہ کی نئی ریاستیں قائم کیں اور دوسری جنگِ عظیم کے بعد ایشیا اور افریقہ میں درجنوں قومی ریاستیں بنیں۔ قوموں کے حقِ خود اختیاری کا تصور نہ عیسائی مذہب پیش کرتا ہے اور نہ اسلام۔ اسلام تو اُمت واحدہ کا قائل ہے جو قوم، نسل، رنگ، زبان اور جغرافیائی سرحدوں کی تفریق سے زیادہ وسیع وارفع تصور ہے۔
پاکستان کا تصور خواہ سرسید احمد خان کے ذہن کی تخلیق ہو یا علامہ اقبال اور مسٹر محمد علی جناح کی سوچ کا نتیجہ ، ان میں سے ہر ایک کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی اور ثقافتی خود مختاری تھی۔ انھوں نے مسلمانوں کی دنیاوی فلاح و بہبود کے پیشِ نظر آزاد پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ اسی بنا پر ہم تحریکِ پاکستان کو سیکولر تحریک کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا لقب ” مفکر پاکستان” ہے۔ وہ اپنے خطبہ صدارت میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 1930ء میں الہ آباد میں پڑھا گیا تھا فرماتے ہیں کہ:
” جہاں تک میں مسلم ذہن پڑھ سکا ہوں مجھ کو یہ اعلان کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ مستقل فرقہ وارانہ سمجھوتے کی خاطر ہندوستانی مسلمان کا اگریہ حق تسلیم کرلیا جائے کہ وہ اپنی تہذیب اور روایت کی روشنی میں آزاد اور مکمل ترقی کا مجاز ہے تو وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دے گا۔۔۔۔ میں چاہوں گا کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں ضم کردیے جائیں، خواہ سلطنت برطانیہ کے اندر خود مختاری، خواہ سلطنت سے باہر۔ میری نظر میں کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر یہی ہے۔ ہندوؤں کو یہ ڈر نہ ہونا چاہیے کہ ان خود مختار مسلم ریاستوں کے معنی ان میں کسی قسم کی مذہبی حکومت کے قیام کے ہوں گے۔”
اپنے اسی موقف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ” مفکر پاکستان 21 جون 1937ء کو مسٹر جناح کو لکھا تھا کہ ” شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو حق خود ارادیت کی مستحق قوم کیوں نہ سمجھا جائے کیوں کہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر دوسری قوموں کا بھی یہی حال ہے”۔ قراردادِ پاکستان اس طرزِ فکر کی آخری شکل تھی۔ چنانچہ مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں 23 مارچ 1940ء کو قوموں کے حقِ خود ارادیت ہی کی بنا پر یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ
” جغرافیائی اعتبار سے ملحق وحدتوں کی اس طرح حد بندی کی جائے کہ جن علاقوں میں، مسلمان اکثریت میں ہیں جیسے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی منطقوں میں ان کو ملا کر آزاد ریاستوں کی تشکیل کی جائے جن میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار اور اقتدارِ اعلیٰ کی مالک (ساورین) ہوں”۔
مسٹر جناح نے اپنی تقریروں اور اخباری بیانوں میں مسلمانوں کی قومی انفرادیت کی باربار تشریح کی ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ” ہم ایک قوم ہیں، ہماری مخصوص تہذیب ہے زبان، ادب، آرٹ اور فن ہیں، اسماء و اصطلاحات ہیں، قدریں اور پہچانیں ہیں، قانون و اخلاق کے ضابطے، رواج اور جنتری، تاریخ و روایات اور مذاق اور آرزؤئیں ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی کے بارے میں ہمارا مخصوص نقطہ نظر ہے۔ لہٰذا قانونِ قوم کے ہر قاعدے سے ہم ایک قوم ہیں۔” 53
پاکستان میں سیکولر نظام کے حق میں سب سے وزنی آواز قائدِاعظم کی وہ تقریر تھی جو انھوں نے 11، اگست 1947ء کو آئین ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں کی تھی۔ اس تقریر میں انھوں نے حاضرین سے اپیل ککی تھی کہ وہ اپنے پرانے اختلافات کو بھول جائیں اور ” رنگ ذات اور عقیدے” کے فرق کو نظر انداز کر کے ” اول و آخر پاکستان کے شہری” کی حیثیت سے مل کر کام کریں۔
” ہم کو اسی جذبے کے تحت مل کر کام کرنا چاہیے۔ امتدادِ زمانہ کے ساتھ اکثریتی فرقے اور اقلیتی فرقے کے زاویوں کا فرق مٹ جائے گا۔ کیوں کہ مسلمانوں میں پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں اور ہندوؤں میں برہمن، وشنو اور کھتری ہیں اورپھر بنگالی اور مدراسی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان کی حصولِ آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی فرق رہا ہے۔اگریہ نہ ہوتا تو ہم کب کے آزاد ہو چکے ہوتے لہٰذا ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اب آپ آزاد ہیں۔ آپ مندر میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ مسجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔۔۔۔ آپ کسی مذہب، کسی ذات، کسی عقیدے کے بھی ہوں امورریاست کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ آ پ جانتے ہیں کچھ مدت پہلے انگلستان کے حالات ہندوستان کے موجودہ حالات سے بھی کہیں بدتر تھے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے رہتے تھے۔ آج بھی بعض ملک ایسے ہیں جن میں بعض طبقوں کے ساتھ امتیازی برتاؤ ہوتا ہے اورپابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس عہد میں کام نہیں شروع کررہے ہیں۔ ہم ایسے عہد میں کام شروع کررہے ہیں جب ایک فرقے اوردوسرے فرقے کے درمیان کوئی فرق، کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے۔ہم اس بنیادی اصول کے تحت کام شروع کررہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اورایک واحد ریاست کے مساوی شہری ہیں۔ انگلستان کے لوگوں کو زندگی کی حقیقتوں سے سابقہ پڑا تھا اور حکومت نے ان پر جو ذمے داریاں عائد کی تھیں ان کو پورا کرنا تھا۔ اور وہ اس آگ میں قدم بہ قدم گزرے۔ آج آپ یہ کہنے حق بہ جانب ہوں گے کہ (وہاں) رومن کیتھولکوں اور پروٹسٹوں کا وجود نہیں ہے۔ جو موجود ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص ایک شہری ہے اور برطانیہ عظمیٰ کا مساوی شہری ہے اور وہ سب اپنی قوم کے رکن ہیں۔
” میرا خیال ہے کہ ہم سب کو یہی نصب العین اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا ہندو، ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے ۔ مذہبی مفہوم میں نہیں کیوں کہ وہ ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنی میں ، بہ حیثیت ریاست کے شہریوں کے”۔
قائدِ اعظم جب یہ کہتے ہیں کہ امورِ ریاست میں مذہبی عقیدوں کا دخل نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ وہ سیکولر ریاست ہی کا مفہوم پیش کررہے ہیں۔ انھوں نے بار بار انگلستان کا جو ذکر کیا ہے تو وہ پاکستانیوں کو یہ بات ذہن نشین کروانا چاہتے تھے کہ جس طرح انگلستان میں مختلف فرقوں کے لوگ آباد ہیں اور اپنے اپنے عقیدوں کی پیروی کرتے ہیں مگر مذہب ریاستی امو رمیں دخیل نہیں ہوتا اسی طرح یہاں بھی مذہب کو ریاستی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ریاستی امور کا تصفیہ مذہبی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔
قائدِاعظم کی سوچ کا انداز سیکولر تھا۔ ان کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ ان کی تعلیم کراچی ، بمبئی اور لندن کے تجارتی شہروں میں ہوئی تھی۔ ان کو جاگیریت اور ملائیت سے دور کا بھی تعلق نہ تھا اور نہ اس خرافات سے ان کا کوئی مفاد وابستہ تھا بلکہ برطانوی طرزِ فکرو سیاست کی لبرل روایتیں ان کا مزاج بن گئی تھیں۔ چنانچہ تحریکِ پاکستان کے دوران انھوں نے اس بات پر بار بار زور دیا تھا کہ پاکستان تھیو کریسی نہیں بلکہ ایک ماڈرن جمہوری ریاست ہوگا۔ اگروہ کچھ دنوں اور جیتے تو شاید سیکولر قدروں کو پامل کرنا آسان نہ ہوتا مگر موت نے ان کو مہلت نہ دی۔
قائدِاعظم کے بعد جو حضرات برسرِ اقتدار آئے جاگیری نظام اور اس کی قدروں سے ان کا بڑا گہرا رشتہ تھا بلکہ وہ خود نواب اور جاگیر دار تھے۔ انھوں نے جمہوریت کو فروغ کی اجازت ہی نہ دی اور نہ خردمندی کی حوصلہ افزائی کی بلکہ مذہب کی آر لے کر نہایت فرسودہ رسوم و توہمات اور رجعت پرست نظریات کی ترویج و اشاعت شروع کردی۔ وہ ملاؤں، پیروں اور سجادہ نشینوں سے ساز باز کرنے لگے۔ عرسوں، میلاد شریف کے جلسوں، عزاداری کی مجلسوں اور قوالی کی محفلوں میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہونے لگی۔ قبرپرستی عام ہوئی اور مزاروں کی آرائش و زیبائش پر لاکھوں روپے خرچ ہونے لگے۔ ملک میں مویشیوں کی شدید قلت تھی پھر بھی جانوروں کے بے دریغ قربانی پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ اخبار، ریڈیو، ٹی وی غرض کہ ابلاغ کے ذرائع اس مہم میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں مصروف ہوگئے ۔ زرعی پیداوار گھٹتی رہی مگر جاگیری نظام کو منسوخ کرکے زمین کاشت کاروں میں تقسیم کرنے کا کسی کو خیال نہ آیا۔ ابتدا میں تو جمہوری آئین اور بنیادی حقوق کا زبان سے اقرار ہوتا رہا لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ تکلف بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا اور ملک میں فوجی ڈکٹیٹر شپ قائم ہو گئی۔
بعض حلقوں کا خیال ہے کہ سیکولرازم سوشلزم ہی کا دوسرا نام ہے اور اشتراکی کوچہ گرد اپنے سوشلسٹ نظریوں کو سیکولرازم کے چور دروازے سے داخل کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ جدید سیکولرازم اور سائنسی سوشلزم دونوں صنعتی نظام کے بطن سے نکلے ہیں اور دونوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں مثلاً سائنسی اندازِ فکر اور سائنسی طرزِ تعلیم پر اصرار، جاگیری نظام کی مخالفت اور صنعتی نظام کی حمایت ، جمہوری حکومت اور اقتدارِ اعلیٰ کا غیر مابعد الطبیعاتی تصور، شہری حقوق کا احترام، آزادی فکر اور ریاست و مذہب کی خود مختاری وغیرہ۔ مگران مشترکہ اقدار کے باوجود دونوں کے اقتصادی نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر چند کہ کسی سیکولر ریاست کو سوشلزم کے اقتصادی اصولوں کے اختیار کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیکولرازم کا رحجان عموماً سرمایہ داری نظام کی جانب رہا ہے اس لیے کہا جاتا ہے سیکولرازم دراصل بور ژواجمہوریتوں کا سیاسی نظریہ ہے۔ اگر بینک ، فیکٹریاں، ملیں، کانیں، زمینیں اور صنعتی اور تجارتی کارپوریشن چند افراد کی ذاتی ملکیت ہوں اور سرمایہ دار طبقہ محنت کشوں کی قوت و محنت کا آزادانہ استحصال کرتا رہے تو بھی سیکولرازم کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ سیکولرازم کو نہ محنت کشوں کی طبقاتی جدو جہد سے کوئی دل چسپی ہے نہ ان کو برسرِ اقتدار لانا اس کے لائحہ عمل میں شامل ہے۔ اس کے برعکس سوشلزم دولت آفرینی کے ذرائع کو جن پر استحصالی طبقوں کا قبضہ ہے قومی ملکیت میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ ان کا انتظام محنت کشوں کی چنی ہوئی حکومت اور چنے ہوئے نمائندوں کے سپرد ہو اور معاشرے کی تنظیم اس اصول پر ہو کہ ” جو محنت کرے گا وہ کھائے گا ” یعنی سوشلسٹ معاشرے میں بچوں، بوڑھوں اور بیماروں سے قطع نظر کسی مفت خورے گروہ کی گنجائش نہ ہوگی۔ یہی بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے بیش تر سیکولر ریاستوں کا اقتصادی نظام سرمایہ دارانہ ہے بلکہ بعض ریاستوں کا حاکم طبقہ تو سوشلزم کا شدت سے مخالف ہے۔ مثلاً امریکا، برطانیہ، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا اور ترکی وغیرہ۔
سوشلزم کو سیکولرازم کی سپر بھی درکار نہیں ہے۔ سوشلزم کے بازو اتنے قوی ہیں کہ اس کو اپنی ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں سیکولرازم کی بیساکھی لگانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی۔ آج آدھی دنیا میں معاشرے اور ریاست کی تعمیر نواگرسوشلسٹ نظریات کے مطابق ہو رہی ہے تو یہ سیکولر ازم کا فیض نہیں بلکہ محنت کشوں کی جدو جہد کا ثمر ہے۔ سوشلزم کے بڑھتے ہوے اخلاقی وقار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے ملک جو دراصل سوشلسٹ نہیں ہیں وہ بھی خود کو سوشلسٹ کہتے ہیں مثلاً یونان، فرانس، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، شام و عراق، چین اور ہندوستان، برما اور سری لنکا حتیٰ کہ مصربھی۔ آخر ہٹلر کی فاشسٹ پارٹی کا نام بھی تو نیشنل ” سوشلسٹ” پارٹی تھا۔
پاکستان گزشتہ 30،32 برس سے سیاسی اور اقتصادی بحرانوں کا شکارہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہاں زندگی کے ہر شعبے میں فیوڈل عناصر اور فیوڈل اقدار کا غلبہ ہے۔ حالانکہ فیوڈلزم مدت ہوئی اپنی افادیت کھو چکا ہے اوراب اس میں دورِ حاضر کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت باقی نہیں۔ وہ ایک پیرِ تسمہ پا ہے جس کو گردن پر سے اتارے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب جمہوری اصولوں کو فروغ کا موقع ملے اور معاشرے کی ازسرِ نو تنظیم سیکولر خطوط پر کی جائے۔ اس تاریخی منصب کو ملک کے روشن خیال عناصر عامتہ الناس کے عملی تعاون ہی سے پورا کرسکتے ہیں۔
حوالہ جات و حواشی
1۔ مولانا در خواستی زندگی میں ایک آدھ بار ضرور بیمار پڑے ہوں گے اور کسی ڈاکٹر یا حکیم نے ان کا علاج بھی کیا ہوگا لیکن ان سے اگر عرض کیا جائے کہ حضورِ والا آپ کی شفا یابی کے ذرائع سیکولر تھے تو وہ ہرگز نہ مانیں گے۔
2۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا، جلد 20، ص 264
3۔ ایضاً جلد، 24،ص 521
4۔ایضاً۔ ص 1091
5۔H.A.L. Fisher. History of Europe vol. I London. 1972. P. 186
6۔ ایضاً۔ ص 260
7۔ ایضاً
8۔ Phillip Hitti, History of the Arabs. P. 582.587
9۔ Cambridge History of Islam, vol.11. Cambridge. P 801
10۔ Will Durant. The Age of Faith. P 956
11۔ Amold Toynbee. A Histotian’s Approach to Religion, New York. 1956 p. 184
12۔ خالدہ ادیب خانم، Conflict of East and West in Turkey, Delhi, 1935, pp. 40.42
13۔ Niazi Berkes, Development of Secularism in turkey, Montreal, 1964, p. 33
14۔ خالدہ ادیب ، ص 51
15۔ Cambridge History of Islam, vol1.p. 368
16۔ خالدہ ادیب، ص 154
17۔ نیازی برکس، ص 259
18۔ خالدہ ادیب خانم، ص 163
19۔ خالدہ ادیب خانم، ص 160۔162
20۔ Cambridge History of Islam, Opcit, p.555
21۔ نیازی برکس، ص 262
22۔ نپولین نے 1798ء میں اسکندریہ پر قبضہ کرنے کے بعد جو پہلا اعلان جاری کیا اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور سورہ اخلاص سے ہوئی۔ پھر مصریوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ” ہم پر یہ تہمت لگائی جا ریہ ہے کہ ہم آپ کا مذہب برباد کرنے آئے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم آپ کو ظالموں کے پنجے سے آزاد کروانے آئے ہیں۔ میں خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں اور پیغمبر خدا اور قرآن مجید کا احترام کرتا ہوں۔ لوگوں سے کہہ دو کہ فرانسیسی بھی سچے مسلمان ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ انھوں نے روم پر قبضہ کر کے پاپائے روم کی قوت کو خاک میں ملا دیا ہے جو ہمیشہ عیسائیوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دیتا تھا اور ہم نے مالٹا کے عیسائی مہم پسندوں کو جو (صلیبی جنگوں کے وقت سے ) مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو خدا کا حکم سمجھتے تھے زیر کرلیا ہے۔ فرانسیسی ہمیشہ سلاطینِ عثمانی کے مخلص دوست اور ان کے دشمن کے دشمن رہے ہیں۔”
23۔انقلاب اور قدامت پرستی، 1923، ضیاء گو کلپ کے خیالات ان کے مضامین کے مجموعے کے انگریزی ترجمے کے ماخوذ ہیں:
Zia Gokalp: Trukish Nationalism and Western Civilization, Londo, 1959.
24۔ Mohammad Iqbal: Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 162
25۔ Dr Ziaul Haq. “ Muslim Religious Education in Indo-Pakistan”. Islamic studies. Islamabad, 1975
26۔ History of Freedom Movemet, vol.11, Karachi, 1960, p. 172
27۔ Dr. Abid Husain: The National Culture of India, Bombay, 1951, p. 71
28۔ برنیٹر، عہد اورنگزیب، ترجمہ محمد حسین، کراچی، 1960ء، ص 231۔232
29۔ منقول ازڈاکٹر ضیاءالحق، ص 279
30۔ S.N. Mukherji, Sir William Joes, Cambridge, 1968, p. 82
31۔ خلیق احمد نظامی، سید احمد خان، نئی دہلی، 1971، ص 12
32۔ W.H. Cary, The Good old Days of Hon’ble John Company, vol,1, simla. 1882 p. 234
33۔ محمد عقیق صدیقی ، ہندوستانی اخبار نویسی ، علی گڑھ، انجمن ترقی اردو، 1957، ص 150
34۔ مولوی عبدالحق ، مرحوم دہلی کالج، کراچی، 1962ء ص 15۔16
35۔ سر سید احمد خان ، مقالاتِ سرسید، لاہور، 1962ء، ص 105
36۔ الطاف حسین حالی، حیات جاوید، ضمیمہ، اسباب بغاوت ہند، لاہور، سن ندارد، ص 902
37۔ خلیق احمد نظامی ، سید احمد خان، ص 25
38۔ مقالاتِ سرسید، جلد 16، لاہور، 1965ء ص 663،6
39۔ ایضاً۔ جلد اول ، لاہور، 1962ء، ص 97۔98
40۔ ایضا۔ ص 273
41۔ایضاً۔ جلد 5، لاہور، 19622ء ص 251
42۔ ایضاً جلد اول، ص 191، بحوالہ تذکرہ الحافظ، جلد اول، ص 3 ، ص 266
43۔ ایضاً۔ جلد اول، ص 98
44۔ ایضا۔ ص 288
45۔ مقالاتِ سرسید، جلد 5، ص 1، 3
46۔ ایضا۔ 3، 4
47۔ ص 2
48۔ منقول ازالطاف حسین حالی، جاوید، ص 269
49۔ Translation From Quran, Lahor, 1975, p. 21
50۔ Altaf Gauhar (ed), The Challenge of Islam, London, 1978, p. 299
51۔ ایضاً۔ ص 299۔ 300
52۔Donald E. Smith , India as a Secular State, Princeton, 1963. P. 5
فرد ، ریاست اور مذہب کے رشتوں کی اس بحث کے لیے راقم مسٹر ڈونلڈ اسمتھ کا ممنون ہے۔
53۔ Gunar Myrdal Asian Drame, vol, 1, London, 1968. P. 233
باب چہارم: وادی سندھ کا سوشلسٹ صوفی
منصور ہویا سرمد ہو صنم ، یا شمس الحق تبریزی ہو
اس تیری گلی میں اے دلبر ہر ایک کا سرقربان ہوا
سچل سرمست
وادیِ سندھ ہمارے ماضی کی امین اور مستقبل کی نوید ہے۔ برصغیر کی سب سے قدیم تہذیب کا مولدو مرقد یہی علاقہ ہے جس نے گزشتہ تین چار ہزار سال کی تاریخ میں بڑے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں اور ان گنت قوموں اور مذہبوں کی جولاں گاہ رہا ہے۔ شکتی وادی مسلک کے پابند دراوڑ، ویدک دھرم پر چلنے والے آریا، حکیم زرتشت کے ماننے والے ایرانی، زیوس اور اپالو کے پرستار یونانی، بدھ مت کے پیرو ہن اور کشن اور اسلام کے معتقد عرب، ایرانی، ترک اور افغان سب نے یکے بعد دیگرے اپنی اپنی تہذیبوں کے حسین امتزاج سے۔
مگرایک وقت وہ بھی آیا جب معاشرہ ماضی کی دلدل میں پھنس کر آگے بڑھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھا اور تب ڈھائی پونے تین سو برس گزرے ایک مردِ مجاہد نے اجتماعی طرزِ معیشت کی طرح ڈال کر ہم کو آگے بڑھنے کی راہ دکھائی۔ اُس نے اِس خزاں گزیدہ دیار میں “گلشنِ نا آفریدہ” کا خواب دیکھا اوراپنے قبل از وقت سنہرے خواب کی تعبیر کے صلے میں شہادت پائی۔ اس نیک نیت بزرگ کا نام شاہ عنایت اللہ تھا۔ جھوک کی بستی میں جو شہر ٹھٹھہ سے 35 میل کے فاصلے پر واقع ہے ان کا مزار آج بھی زیارت گاہِ خاص و عام ہے اور لوگ دُور دُور سے آکر ان کی قبرپر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں لیکن شاہ عنایت کی شہادت کے اسباب و محرکات کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔
شاہ عنایت کا سنِ ولادت معلوم نہیں لیکن یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ سترھویں صدی عیسوی میں شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں ٹھٹھہ کے ایک خدار سیدہ خاندان میں پیدا ہوے۔ ان کے جدِ علیٰ مخدوم صدھولا نگاہ موضع نصریہ پرگنہ بٹھورہ ضلع ٹھٹھہ کے رہنے والے تھے1۔ وہ ایران توران سے نہیں آئے تھے بلکہ یہیں کی خاک سے اٹھے تھے لنگاہ قو م سے تعلق رکھتے تھے۔
شاہ عنایت کے والد مخدوم فضل اللہ ” بے رِیا درویش ” تھے۔ میر علی شیر قانع شاہ عنایت کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں خاموش ہیں لیکن لکھتے ہیں کہ ” پیرِ حق شناس، بنیاد شریعت، مرشدوں کے مرشد، ولی زمانہ، مقبولِ بارگاہِ الہیٰ شاہ عنایت اللہ صوفی نے ابتدا میں جستجوئے حق کے لیے بڑی سیرو سیاحت کی اور کافی مدت کے بعد دکن میں جا کر شاہ عبدالملک سے ملاقات کی”۔ ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے بعد شاہ عنایت نے دہلی کا رخ کیا اور وہاں ایک بزرگ شاہ غلام محمد سے علومِ ظاہری حاصل کیے۔ مگر استاد پر شاگرد کی شخصیت کا اتنا اثر ہوا کہ وہ شاہ عنایت کے ہمراہ ٹھٹھہ چلے آئے۔ شاہ غلام محمد کو شریعت سے طریقت کی راہ زیادہ عزیز تھی لہٰذا ” ٹھٹھے کے علما نے انھیں تعزیر کے لیے شرعی عدالت میں پیش کردیا” کیوں کہ اہل اللہ کو علما سے ہمیشہ اذیتیں پہنچتی ہیں۔” 2 شاہ عنایت نے شاہ غلام محمد کو دہلی لوٹ جانے کا مشورہ دیا چنانچہ وہ دہلی واپس چلے گئے اور شاہ عنایت نے جھوک میں سکونت اختیار کرلی۔
شاہ عنایت نے جب ہوش سنبھالا تو سلطنت ِ مغلیہ کا آفتاب بڑی تیزی سے مائل بہ زوال تھا۔ اورنگ زیب نے اگرچہ اکبر اعظم کی مانند پچاس برس حکومت کی لیکن اس کی سلطنت کو عہدِ اکبری کا سا امن و استحکام کبھی نصیب نہ ہوا۔ شہنشاہ کا ابتدائی زمانہ باپ اور بھائیوں کو راہ ہٹانے میں گزرا۔ پھر دکن کی مہمیں شروع ہو گئیں۔ اُدھر مرہٹوں، راجپوتوں اور سکھوں نے شورش برپا کی اور جا بجا بغاوتیں ہونے لگیں۔ مرکز کی گرفت کمزور ہوئی تو جاگیری نظام کی تباہ کاریوں نے اپنا رنگ دکھایا۔ ایسی حالت میں سندھ جیسے دُور افتادہ علاقے کا کون پر سانِ حال ہوتا۔ صوبے کا نظم و نسق درہم برہم ہوگیا۔ جاگیرداروں کی بن آئی اور ہر طرف لوٹ مارکا بازار گرم ہوگیا۔
سندھ اُن دنوں دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔
بالائی سندھ جس کا صدر مقام بھکر (سکھر) تھا اور زیریں سندھ جس کا صدر مقام ٹھٹھہ تھا۔ بالائی سندھ کی حیثیت صوبہ ملتان کی چوتھی سرکار کی تھی اور وہاں کا حاکم ملتان کے صوبے دار کے تابع ہوتا تھا۔ وہاں 1574ء اور 1679ء یعنی 105 برس میں پچاس حاکم مقرر ہوئے۔ ان کی مدت ملازمت کا اوسط فی کس دو سال ہوتا ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں سلطنت کے ضعف اور سیاسی ابتری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1679ء میں فوجی مہموں کی ناکامی کے بعد بالائی سندھ کا علاقہ کلہوڑا سردار میاں یار محمد کے حوالے کردیا گیا اور پھر وہاں کوئی مغل حاکم نہیں آیا۔ زیریں سندھ جہاں مرزا جانی بیگ ترخان کی خود مختار حکومت تھی 1599ء میں اکبر کے حکم سے فتح ہوا تھا مگر دُور اندیش شہنشاہ نے مرزا جانی بیگ سے عہدِ وفاداری لے کر ریاست اس کو واپس کردی تھی۔ مرزا جانی بیگ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مرزا عیسٰی خان ترخان سندھ کی باج گذار ریاست کا مالک تسلیم کرلیا گیا لیکن اس کی وفات کے بعد جہانگیر نے سندھ کو 1614ء میں الگ صوبہ بنا دیا۔ ٹھٹھہ میں 1614ء اور 1732ء (118سال) کے درمیان 67 صوبے دار آئے اور گئے۔ ان کی مدتِ ملازمت کا اوسط ڈیڑھ سال ہوتا ہے۔ بعضوں نے تو دہلی سے ٹھٹھہ آنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کی بلکہ اپنے نائب بھیج دیے۔ لاہری بندر کو جو وادیِ سندھ کی واحد بڑی بندرگاہ تھی خالصہ کی ملکیت قرار دے دیا گیا لہٰذا صوبے کی آمدنی گھٹ گئی اور سیاسی اہمیت بھی کم ہو گئی۔ چنانچہ عموماً کم رتبے کے منصب داروں کو ٹھٹھہ کا صوبے دار مقرر کیا جاتھا بلکہ بعض اوقات سیوستان یا بھکر کے کسی فوجدار کو صوبے دار بنا کر ٹھٹھہ بھیج دیا جاتا تھا۔ آخرش صوبہ ٹھٹھہ کا بھی وہی حشر ہوا جو بھکر کا ہوا تھا۔ 1732ء میں نواب امیر خان کو پوا صوبہ بطورجاگیر عطا ہوا۔ انھوں نے اس دولت خدادا کو ایک شخص دلیر خان ولد دلیر دلبر خان کو اجارے (ٹھیکے) پر دے دیا اور جب دلیر خان مرگیا تو صادق علی خان کو مستاجر بنا دیا۔ ان موصوف کو اجارے میں ” گھاٹا” ہوا لہٰذا انھوں نے زیریں سندھ کو 1738ء میں خدا یار خان کلہوڑا (نور محمد خان) کے سپرد کردیا۔
ٹھٹھے کا صوبہ چار سرکاروں پر مشتمل تھا۔ ٹھٹھہ ، نصرپور، چاچکاں اور چاکر ہالا۔ صوبے کے حاکم اعلیٰ کو ناظم کہتے تھے۔ سرکار کا حاکم فوجدار اور پرگنے کا حاکم شقہ دار کہلاتا تھا۔ ان کے علاوہ نظم ونسق کے فرائض کی ادائیگی کے لیے دیوان، بخشی، عامل، وقائع نویس، قاضی، محتسب، صدر، مقدم، قانون گو، پٹواری، متصدی، کارکن، سجاول اور ارباب متعین تھے۔ وقائع نویس مرکزی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا۔ اس کا کام مرکز کو علاقے کے نظم و نسق کی خفیہ رپورٹیں بھیجنا ہوتا تھا البتہ یہ پتہ نہیں چلتا بقیہ عہدے داروں کا تقرر بھی مرکز کرتا تھا یا وہ صوبیدار کے نامزد کردہ ہوتے تھے۔ بہرحال قریب قریب سبھی عہدے ترکوں اور ایرانیوں کے لیے مخصوص تھے خواہ وہ براہِ راست دہلی سےآتے یا سندھ میں بسے ہوئے پرانے ترک، ایرانی یا عرب خاندانوں کے افراد ہوتے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مقامی باشندے فارسی زبان سے جو سلطنت کی سرکاری زبان تھی شاذو نادر ہی واقف ہوتے تھے۔
زرعی نظام کا ارتقا
یہاں کے قدیم سیاسی نظریوں کے مطابق زمین کاشت کاروں کی مشترکہ یا ذاتی ملکیت تسلیم کی جاتی تھی، ریاست کی ملکیت نہیں ہوتی تھی۔ البتہ کاشت کاروں کو پیداوار کا ایک مقررہ حصہ ریاست کے حوالے کرنا پڑتا تھا۔ پیداواری عمل میں گاؤں والے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ واجبات کی وصولی اور ادائیگی گاؤں کے مکھیا کی ذمے داری ہوتی تھی۔3
مسلمانوں کے عہد میں (712۔1843ء) سندھ میں یکے بعد دیگرے گیارہ مختلف خاندان برسر اقتدار آئے۔ ان میں سومرا، کلہوڑا اور تالپور خاص مقامی لوگ تھے لیکن نسلی تفاخر کا رحجان ہمارے پڑھے لکھے طبقوں میں چھوت کی بیماری کی طرح پھیلا ہوا ہے ہم کو اس سرزمین سے رشتہ جوڑتے بری شرم محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر شخص یہی کوشش کرتا ہے کہ اپنا نسلی رشتہ عرب، عراق، ایران، ترکستان سے جوڑے اور یہ ثابت کرے کہ ہمارے اجداد باہر سے آئے تھے۔ کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے پرکھے یہیں کے رہنے والے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ افسوس ہے کہ ہمارے مورخین بھی اس مرض سے محفوظ نہ رہ سکے۔ مثلاً مولانا غلام رسول مہر نے ” تاریخِ سندھ عہدِ کلہوڑا” میں 35 صفحے یہ ثابت کرنے میں صرف کیے ہیں کہ کلہوڑا عباسی ہیں4؎ اسی طرح مولانا اعجاز الحق قدوسی نے تاریخ معصومی ، تاریخ طاہری، مولانا سید سلیمان ندوی، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ اور انگریز مورخین کی تمام دلیلوں کو رد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ” سومرا عرب تھے جو ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے” 5؎ حالاں کہ سومرا، سمہ اور کلہوڑا خاندان کے بانیوں کے نام اوران کے قبیلہ داری رسم و رواج ہی ان کے سندھی الاصل ہونے کی ناقابلِ تردید شہادت پیش کرتے ہیں۔ مثلاً بھونگر، دودا، سانگھڑ، پاتھو، گھنرا، چنیسر، گھچن، بہیل وغیرہ۔
مقامی خاندانوں کے دور میں حاکم اور محکوم کا فرق اگرچہ موجود تھا مگر خلیج اتنی وسیع نہیں تھی جتنی غیر ملکی حکمرانوں کے عہد میں ہوئی۔ سومرا ہوں یا سمہ، کلہوڑا اور تالپور ان کا رہن سہن، ان کے رسم و رواج ، ان کی زبان اور تہذیبی قدریں عام باشندوں سے مختلف نہ تھیں لہٰذا رعایا کو بے گانگی کا چنداں احساس نہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے عہد میں سندھ کی دولت سندھ ہی میں رہتی تھی اور عام لوگوں کو بھی اس سے براہِ راست یا بالواسطہ طور پر مستفید ہونے کا موقع مل جاتا تھ۔ خراج کی شکل میں دمشق، بغداد، غزنی یا دہلی نہیں منتقل ہوتی تھی۔ مثلاً ہیر وڈوٹس لکھتا ہے کہ داریوش اعظم کے دور میں سندھ کا صوبہ ایران کو سونے کے 231 من ذرات بطور خراج بھیجتا تھا6؎ اسی طرح خلافتِ بنی امیہ اور بنی عباس کی محکومی میں سندھ کو ہر سال 15 لاکھ درہم خراج ادا کرنے ہوتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ملکی حکومتوں کے زمانے مین سرکاری ملازمتیں مقامی لوگوں کو ملتی تھیں۔ صوبے دار اور شقہ دار باہر سے آکر ان پر مسلط نہیں ہوتے تھے اور نہ فوج کے سالار اور سپاہی غیر سندھی ہوتے تھے۔
ہباری قریش، ارغون اور ترخان ہر چند کے باہر سے آئے تھے لیکن انھوں نے سندھ میں مستقل بودوباش اختیار کرلی تھی۔ شادی بیاہ بھی مقامی خاندانوں میں کرنے لگے تھے اور انھیں میں گھل مل گئے تھے۔ اس کے برعکس سلاطینِ مغلیہ کے عہد میں سندھ کی حیثیت بالکل مفتوحہ علاقے کی تھی۔ تمام ذمہ دار عہدے ترکوں اور ایرانیوں کو سونپے جاتے تھے اور ان کو ہر طرح کی مراعات حاصل تھیں جب کہ سندھ کے حقیقی باشندوں کو صوبے کے نظم و نسق پر کوئی اختیار نہ تھا۔
سندھی اور غیر سندھی خاندانوں کے دورِ حکومت کے اس فرق کے باوجود انگریزوں کی آمد (1843ء) سے پیش تر یہاں کے معاشرے میں ہزار برس کی طویل مدت کے دوران کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی۔ حکومتیں بدلتی رہیں لیکن طرزِ حکومت قریب قریب یکساں رہا۔ نہ قبیلہ داری نظام بدلا اور نہ ذرائع پیداوار اور پیداواری رشتوں میں کوئی فرق آیا۔ جو آلات و اوزار گوتم بدھ کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے وہی مغلوں کے زمانے میں بھی بدستور استعمال ہوتے رہے۔ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں مگر دیہات کی زندگی پرانی ڈگر پر چلتی رہی۔ غور سے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ خالص سندھی حکومتوں کے عہد میں بھی سرکار دربار کی ساری فضا ایرانی تھی۔ دربار میں فارسی بولی جاتی تھی، سرکاری دفتروں کی زبان فارسی تھی، خط و کتابت فارسی مین ہوتی تھی، شعر فارسی میں کہے جاتے تھے، کتابیں فارسی میں لکھی جاتی تھیں، مکتبوں اور مدرسوں میں ذریعہ تعلیم فارسی تھا اور جو خاندان ایران، عراق، ترکستان اور افغانستان سے بھاگ کر یہاں آتے تھے ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا تھا۔ ان کو ملازمتیں اور زمینیں آسانی سے مل جاتی تھیں۔ سندھ میں پیروں اور سیدوں کی فراوانی اہلِ سندھ کی اسی فراخ دلی اور مہمان نوازی کی مرہونِ منت ہے۔
اسلام کی رُو سے زمین کا مالک اللہ ہے لیکن سلف میں زمین اسی شخص کی ملکیت سمجھی جاتی تھی جو اس کو جوتتا تھا۔ مزارعوں یا ہاریوں کے ذریعے کھیتی باڑی کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر ضیا الحق نے اپنی محققانہ تصنیف Landlord and Peasant in EarlyIslam میں اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور احادیث کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے مزارعت یعنی زمین کو بٹائی پر دینے کی ممانعت فرما دی تھی۔ (ڈاکٹر صاحب کی رائے میں فقط وہ حدیثیں معتبر ہیں جن میں مزارعت کی ممانعت کی گئی ہے اور جن حدیثوں میں مزارعت کی اجازت کا ذکر ہے وہ عباسی دور کی الحاقی اور وضعی حدیثیں ہیں) امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں کاشت کاروں کے حقِ ملکیت کو تسلیم کیا ہے۔ 7؎
اسلامی مملکتوں میں جاگیری نظام کو سب سے پہلے خلفائے بنی امیہ نے رواج پایا۔ انھوں نے ساسانی اور بازنطینی شہنشاہوں کی مانند زمین کے بڑے بڑے قطعات اپنے خاندان کے افراد اور دوسرے متوسلین کو انعام یا وظیفے کے طورپر سونپ دیے۔8؎ اس طرزِ انتقال کو ” اقطاع” کہتے ہیں۔ “اقطاع” نے سندھ میں بھی بنی امیہ ہی کے زمانے میں اس وقت رواج پایا جب عرب خاندان یہاں آآکر آباد ہونے لگے۔ عباسی خلیفہ المتوکل کے عہد میں (847ء۔861ء) جب فو ج کی ازسرِ نو تنظیم ہوئی تو فوجی کمانداروں کو اقطاع کی زمینیں ان علاقوں میں عطا کی گئیں جہاں وہ نظم و نسق کے سلسلے میں متعین ہوتے تھے۔ 9؎ اقطاع کی یہ نئی شکل تھی کیوں کہ اب تک زمینیں سرکاری عہدیداروں کو فوجی یا انتظامی اخراجات کی کفالت کے لیے یا نقدی مشاہرے کے عوض بھی ملنے لگیں۔
سلاطینِ دہلی کے عہد میں اقطاع کی ابتدا سلطان التمش ( 1210ء۔ 1236ء) نے کی۔10؎ اس کے جانشینوں نے بھی اس کی تقلید کی چنانچہ بلبن نے دہلی کو سرکش میواتیوں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے دارالسلطنت کے نواح اور دوآبے میں اقطاع کی آراضیاں دو ہزار پٹھان لشکریوں میں تقسیم کردیں11؎ مگر سلطان علاؤالدین خلجی نے جو تخت نشینی سے پہلے کڑا الہٰ آباد کا مقطیع رہ چکا تھا ، لشکریوں کو زمینیں دینے کا طریقہ بند کردیا اور تنخواہیں نقد ادا کرنے کا سلسلہ شروع کیا لیکن فیروز تغلق نے پرانی روایت پھر تازہ کردی۔ اس نے عین الملک کو ملتان کا صوبہ، ملک بیر خان افغان کو بہار کا صوبہ اور ملک افغان خان کو روہیلکھنڈ بطور اقطاع دے دیا۔ لودھیوں کے عہد میں اقطاع میں مزید اضافہ ہوا۔ اقطاع کے عوض مقطیعوں کا فرض تھا کہ وہ اپنے علاقوں میں امن و امان کے تحفظ کے لیے فوج رکھیں اور سلطان کی طلبی پر لشکر سمیت حاضر ہوں، چنانچہ جمال خان لودھی جاگیردار جونپور کے پاس 20 ہزار لشکری تھے۔ تاتار خان جاگیردار پنجاب کے پاس پندرہ ہزار اور اعظم ہمایونی سرونی جاگیردار الہ آباد کے پاس 45 ہزار سوار اور سات سو ہاتھی تھے۔12؎
اقطاع کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ برے جاگیر دار اپنی جاگیروں میں چھوٹے چھوٹے جاگیردار مقرر کرنے لگے۔ مثلاً اعظم ہمایوں سروانی نے سیف خان کو چھ ہزاری، دولت خان کو چار ہزاری اور فیروز خان کو چھ ہزاری جاگیردار بنا دیالیکن اسلام شاہ سوری (1545ء۔1553ء) نے بڑے جاگیر داروں کا زور توڑنے کی غرض سے ” جمع ولایت راخالصہ ساختہ” (بدایونی) یعنی پوری مملکت کو شاہی ملکیت قرار دے دیا اور نقدی ادائیگی کو دوبارہ رائج کرنے کی کوشش کی مگرناکام رہا۔ اس کے عہد میں ” منصب داری ” کی ابتدا ہوئی۔ یہ خالص فوجی عہدہ تھا اور پچاس تا 20 ہزار سپاہیوں کے سردار کو خزانے سے نقد ادائیگی ہوتی تھی جاگیر نہیں دی جاتی تھی۔ (یہی وہ افغان جاگیردار منصب دار تھے جو پہلے بابر اور ہمایوں کے خلاف اور پھر اکبر کے خلاف صف آرا ہوئے تھے اور جن کو کچل کر اکبر نے افغان امرا کا اثرو نفوذ ختم کیا تھا ان کی جگہ ترک، مغل اور ایرانی منصب دار مقرر کیے تھے) مغلوں کے دور میں اقطاع کی اصطلاح رفتہ رفتہ متروک ہو گئی اور جاگیر اور منصب کی اصطلاحوں نے رواج پایا۔ 13؎
منصب داری نظام کی خرابیوں پر ہم اپنی کتاب ” پاکستان میں تہذیب کا ارتقا” میں مفصل تبصرہ کرچکے ہیں۔ ہم نے لکھا تھا کہ برصغیر کے معاشی اور سیاسی انحطاط کی بڑی ذمہ داری اسی فیوڈل نظام پر عائد ہوتی ہے۔ اسی نظام اقتدار کی ہمہ گیری کے باعث ملک میں وہ سماجی حالات پیدا نہ ہو سکے جن میں سرمایہ داری نظام کو فروغ ہوتا۔ نہ صنعت کاروں، مہاجروں اور بیوپاریوں کا طبقہ اتنا مضبوط ہوا کہ وہ سیاسی اقتدار میں شرکت کا مطالبہ کرتا یا طاقت آزمائی کرکے اقتدار پر قابض ہوجاتا اور نہ دست کاری کی صنعتیں خود کار صنعتوں میں تبدیل ہو سکیں جیسا کہ یورپ میں ہوا۔ یہ محاکمہ اپنی جگہ درست سہی لیکن قرونِ وسطیٰ کے تاریخی حالات میں نظم و نسق کا کیا کوئی دوسرا طریقہ ممکن تھا۔ کیا سلاطینِ دہلی خواہ وہ پٹھان تھے یا مغل تاریخ کے جبر سے آزاد ہو سکتے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ بات یہ ہے کہ شخصی حکومتوں کے دور میں کہ نمائندے ادارے سرے سے مفقود ہوتے ہیں۔ تخت و تاج کی سلامتی ہر فرماں روا اپنا بنیادی فریضہ سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ طاقت ور سے طاقت ور بادشاہ بھی خود تنہا اپنا بچاؤ نہیں کرسکتا بلکہ اس کو کسی نہ کسی طبقے یا گروہ کا تعاو ن حاصل کرنا پڑتا ہے البتہ اس تعاون کی قیمت اختیارات میں شرکت کی شکل میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ سلاطینِ دہلی نے یہ تعاون ، یہ وفاداری جاگیر اور منصب عطا کرکے حاصل کی۔
مثال کے طورپر صوبوں کے نظم و نسق پر ہی غورکریں لیکن یہ حقیقت ذہن میں رکھیں کہ سترھویں اٹھارویں صدی میں مرکز اور صوبوں کے درمیان رابطے کی وہ سہولتیں موجود نہ تھیں جو اب ہیں۔ اس وقت نہ موٹریں اور ریل گاڑیاں تھی نہ ہوائی جہاز۔ نہ تار نہ ٹیلی فون نہ وائر لیس، ایسی صورت میں بس یہی ممکن تھا کہ معتبر اور وفادار امرائے دربار کو صوبوں کا نگراں بنایا جائے۔ نقدی ادائیگی ممکن نہ تھی۔ سکوں کا رواج بہت کم تھا۔ کیوں کہ جاگیری نظام میں چیزیں بازار میں فروخت ہونے کے لیے بہت کم بنتی تھیں لہٰذا سکوں کی ضرورت نہ تھی۔ سرکاری عہدیداروں کو تنخواہیں لا محالہ زمین یا جنس کی شکل میں ادا کی جاتی تھیں۔ کوئی بادشاہ فیوڈل ازم کے دائرے میں رہ کر بدی کے اس چکر سے نکل ہی نہیں سکتا تھا اور اگر کسی نے کوشش کی بھی تو وہ ناکام ہوا۔ علاؤالدین خلجی، محمد بن تغلق اور اسلام شاہ سوری کے تجربے اسی وجہ سے کامیاب نہ ہوسکے۔
اختیارات میں شرکت کی دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ صوبائی وحدتوں کے حق ِ خود اختیاری کو تسلیم کرلیا جاتا اور ان کا نظم و نسق منتخب شدہ نمائندوں کے سپرد کردیا جاتا جیسے امریکا میں ہوتا ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن تھا جب خود مرکز میں کوئی منتخب شدہ نمائندہ حکومت موجود ہوتی ۔ مگرقرونِ وسطیٰ میں جہاں اقتدارِ اعلیٰ کا سرچشمہ ریاست کے باشندے نہیں بلکہ ایک فردِ واحد کی ذات ہوتی تھی اور باشندوں کی حیثیت شہریوں کی نہیں بلکہ رعایا کی ہوتی تھی اس قسم کی طرزِ حکومت کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ قرونِ وسطیٰ کا ہندو ستان پانچویں صدی قبل مسیح کے یونان سے دو ہزار برس پیچھے تھا۔
سلطنتِ مغلیہ کی عمارت بھی جاگیری نظام پر قائم تھی ۔ ہرچند کہ زمین اصولاً ریاست کی ملکیت تھی اور ریاست کے سربراہ کو اس پرپورا اختیار حاصل تھا لیکن قبضے کے اعتبار سے زمین کی چار قسمیں تھیں۔ 1۔ خالصہ، 2۔ جاگیر، 3۔ سیورغال /مددمعاش/انعام 4۔ زمینداری۔ خالصہ کی زمینیں بادشاہ کی ذاتی ملکیت ہوتی تھیں۔ سندھ میں مغلوں کے عہد میں خالصہ کی زمینیں بہت کم تھیں14؎ اور دو حصوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ اول خالصہ سلطانی جس کی آمدنی خزانہ عامرہ میں جمع ہوتی تھی۔ دوئم صوبہ داروں ، فوجداروں اور حاکموں کی کفالت کرنے والی زمینیں لیکن یہ عہدہ دار خود کاشت کرنے کے بجائے زمینوں کو ٹھیکے پر دے دیتے تھے۔ اور ” اس طرح پوری معیشت کی بربادی کا باعث ہوتے تھے”15؎ شکایت جائز لیکن سرکاری عہدہ دار نظم و نسق کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کیسے کرتے۔ وہ زمینیں اجارے پر دینے پر مجبور تھے۔ خالصہ کی زمینیں عموماً بہت زرخیز ہوتی تھیں۔ ان کا مجموعی رقبہ 4/1 اور 11/1 کے درمیان گھٹتا بڑھتا رہتا تھا۔ شاہ جہاں کے عہد میں خالصہ مواضات کی تعداد 75 ہزار اوران کی آمدنی تین کروڑ 15 لاکھ روپیہ تھی16؎ شاہ جہاں کے بعد خالصہ کی آراضیاں بھی اجارے (ٹھیکے) پر دی جانے لگیں۔ نظام الملک آصف جاہ نے محمد شاہ (1719ء۔ 1747ء) کو مشورہ دیا تھا کہ ” چوں کہ خالصہ محال کی اجارہ داری نے ملک کو تباہ کردیا ہے لہٰذا اس طریقے کو منسوخ کردیا جائے” 17؎ مگر اس کی شنوائی نہ ہوئی۔
2۔ جاگیر دار طبقہ حکومت کا دستِ راست تھا اور تقریباً تین چوتھائی زمینیں اس کے تصرف میں تھیں۔ مغلوں نے جاگیرداری اور منصب داری کو یک جا کر کے فوجی ریاست کا جو نظام رائج کیا اس کی وجہ سے جاگیردار طبقہ بادشاہ کے لطف و کرم کا محتاج ہوگیا۔ شاہی خاندان کے افراد اور وزرا سے لے کر صوبوں کے ناظم اور ان کے ماتحت عملہ سب کے سب فوجی عہدے دار ہوتے تھے اور منصب دار کہلاتے تھے 18؎ یہ منصب داریاں دس ہزاری سے شروع ہو کر دس سواروں پر ختم ہوتی تھیں۔ منصب داروں کے مرتبے کا تعین اسی مناسبت سے ہوتا تھا اور اسی حساب ان کو سرکاری خدمات کی بجا آوری کے لیے نقدی تنخواہ کے عوض جاگیریں دی جاتی تھیں۔ گویا ” وہ فوجی بھی ہوتے تھے، نواب بھی اور سول انتظامیہ کے رکن بھی” 19؎ منصب داروں کے تبادلے، برطرفی یا موت کی صورت میں ان کی جاگیر ریاست کو منتقل ہو جاتی تھی۔ سرکاری عہدے چوں کہ موروثی نہیں ہوتے تھے لہٰذا جاگیریں بھی موروثی نہیں ہوتی تھیں۔بڑے منصب داروں (مثلاً صوبہ دار) کی تقرری اور تبدیلی بھی کسی قاعدے سے ضابطے کے مطابق نہیں ہوتی تھی بلکہ بادشاہ کی مرضی پر منحصر تھی لہٰذا ان عہدے داروں کو کچھ خبر نہ ہوتی کہ وہ کب تبدیل یا برطرف کردیے جائیں۔ وہ اپنے فرائض بڑی بے یقینی کے عالم میں ادا کرتے تھے۔
بڑے بڑے جاگیر دار شاذو نادر ہی اپنی جاگیروں پر جاتے تھے۔ وہ خود شاہی دربار سے منسلک رہ کر آگرہ، دہلی اور لاہور میں عیش کی زندگی گزارتے اور جاگیر کی دیکھ بھال عاملوں کے سپرد کردیتے۔ ان کو اپنی جاگیر کو ترقی دینے ، پیداوار کو بڑھانے، افتادہ زمینوں کو زیر کاشت لانے یا آب پاشی کے نظام کو بہتر بنانے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ سوچتے ہمارا یہ منصب چند روزہ ہے ۔ تبادلے کا حکم نہ جانے کب آجائے پھر ہم کیوں فکر کریں لہٰذا جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانو اور جتنا مال و متاع سمیٹ سکو جلد از جلد سمیٹ لو۔ وہ اپنی جاگیریں اجارے پر دے دیتے تھے بلکہ حفظِ ماتقدم کے طورپر مستاجروں سے پیشگی رقم وصول کرلیتے تھے۔ یہ رقم ” قبض” کہلاتی تھی۔ شاہ جہاں کے عہدمیں تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ زمین کا سودا ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص قبض کی زیادہ رقم پیش کرتا تو مقرر شدہ مستاجر کو بے دخل کرکے زمین اس کے حوالے کردی جاتی تھی۔ اس بد عہدی اور لاقانونیت کی نہ کوئی داد تھی نہ فریاد۔ پروفیسر عرفان حبیب کی تحقیق کے مطابق سندھ میں جاگیروں کے انتظام میں مقامی لوگوں کو شریک نہیں کیا جاتا تھا حتیٰ کہ خالصہ میں بھی یہی دستور تھا۔ فقط پرگنے کا قانون گو مقامی آدمی ہوتا تھا۔
یہ اجارہ داری سب سے بڑی لعنت تھی جس سے سندھ کا کاشت کار سندھی فرماں رواؤں کے عہد میں بچا ہوا تھا۔ چنانچہ عہدِ شاہ جہانی کا سب سے مستند مورخ یوسف میرک جو خود جاگیر دار طبقے سے تھا (اس کے والد میرابوالقاسم نمکین بھکری اور بڑے بھائی میرابو البقاد دونوں صوبہ دار رہ چکے تھے) مرزا عیسیٰ خان ترخان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے کہتا کہ فلاں پرگنے کو جس کی مال گذاری بیس ہزار روپیہ ہے ایک لاکھ کے عوض اجارے پر دے دو تو وہ قبول نہ کرتا کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ
درعمل اجارہ ویرانیِ ملک است، چراکہ اجارہ داری میں ملک کی ویرانی ہے کیوں کہ
درعملِ اجارہ دست خاکم ازرعیت برآیدو اجارے میں حاکم رعیت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے
دستِ مستاجر بر آنہا قائم شودو مردم اور مستاجر رعیت پر حاوی ہو جاتا ہے اور
مستاجر حسبِ خواہش خود آنچہ می دانند مستاجر کے آدمی رعیت غریب کے ساتھ جو
بررعیت غریب فی کنند عملِ اجارہ اگرچہ چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اجارہ داری ابتدا
اول مرتبہ مانند آتش کر درکاہ خشک می گیرد میں سوکھی گھاس میں آگ کی طرح اچھی لگتی
خوشترو روشن می نماید، اماآخرش نتیجہ ہے اور روشنی دیتی ہے مگر آخرکار اس کا
سیاسی و خاکستری مطلق می دہد20؎ نتیجہ مکمل سیاہی اور خاکستری ہوتا ہے۔
3۔۔۔۔۔ ” سیور غال” یا مدد معاش وہ زمینیں تھیں جو مکتبوں اور مدرسوں کے خرچ کے لیے یا علما، فضلا اور خاندانِ سادات کے گزارے کے لیے بطور معافی دی جاتی تھیں۔ علم و دانش کو فروغ دینے کا یہ طریقہ ارغونوں نے شروع کیا تھا۔ ترخانوں نے بھی اس روایت کو قائم رکھا البتہ ” مدد معاش کی ایک شرط تھی کہ وظیفہ خوار حاکمِ وقت کے وفادار رہیں” 21؎ اس طرح ارغونوں اور ترخانوں نے سندھ میں پڑھے لکھے افراد اور بااثر خاندانوں کا ایک اہم طبقہ پیدا کرلیا تھا جس کا مفاد حکومت سے وابستہ ہوتا تھا۔ مغلوں کے عہد میں ” مدد معاش” کی زمینوں میں اور اضافہ ہوا مثلاً بھکر میں میر عدل کو پچاس ہزار بیگھہ زمین بطور سیورغال عطا ہوئی لیکن اورنگ زیب سے پہلے یہ معافیاں موروثی نہیں ہوتی تھیں اورنگ زیب نے ان کو موروثی کردیا۔ ڈاکٹر انصار زاہد کے اندازے کے مطابق سندھ میں سیورغال زمینوں کا مجموعی رقبہ 25،30 فی صد سے کم نہ تھا۔ سیورغال کو موروثی کردینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ” سندھ میں سابق علما و مشائخ کے خاندانوں کے اثر و نفوذ میں تدریجاً اضافہ ہوتا گیا اور وہ نہایت طاقت ور فیوڈل گروہ بن گئے” 22؎ ان خاندانوں سے علم و فضل تو ایک دو پشتوں میں رخصت ہوگیا البتہ جاگیریں باقی رہیں اورپیری مریدی کا کاروبار خوب چمکا۔
4۔ چوتھا طبقہ جس کو زمین پر کسی حد تک مالکانہ حقوق حاصل تھے زمینداروں کا تھا۔ یہ اصطلاح بڑی مبہم ہے۔ محمد شاہ کے عہد کا مشہور لغت نویس آنند رام مخلص” مراۃ الاصطلاح” میں لکھتا ہے کہ زمیندار لغوی اعتبار سے” صاحبِ زمیں” کو کہتے ہیں لیکن اب وہ ہر شخص زمیندار کہلاتا ہے جو کسی گاؤں یا قصبے میں زمین کا ” مالک” ہو اور کاشت کرتا ہو23؎۔ زمیندار کی اصطلاح مغلوں کے دور میں بھی استعمال ہوتی تھی چنانچہ ” آئینِ اکبری” اور ” رقعات عالم گیری” دونوں میں زمینداروں کاذکر موجود ہے اور عبدالقادر بد ایوانی بھی منتخب التواریخ میں مالوہ کے کے مشہور ہیرو باز بہادر خان کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ” باز بہادر خان نے جس نے اپنے چند امرا کے ہمراہ راہِ فرار اختیار کرلی تھی دوسرے زمینداروں سے مل کر پیر محمد خان پر حملہ کردیا” 24؎ ایک اور واقعے کے ضمن میں وہ ” غریب زمینداروں ” کا بھی ذکر کرتا ہے۔ 25؎
تاریخ مظہر شاہ جہانی کی شہادت اس سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ وہ سندھ کے دیہات کے بارے میں لکھتا ہے کہ ” ائمہ ایں دیار چار قسم اند” ان میں زمینداروں کو وہ چوتھی قسم قرار دیتا ہے۔
مردم زمینداراں اند کہ تعلق بہ چوتھی قسم زمینداروں کی ہے جن کا تعلق
ربابی و مقدمی نیزدارند، وچوں زمیندار ارباب اور مقدموں سے بھی ہے۔ زمیندار
انند زمین ہا خوب پر حاصل از جاہائے ہونے کے باعث وہ اپنے ماتحت چکوں
نیک درتحت چکہائے خود گرفتہ اندومردم قابض ہیں اور رعیت جو ان کی محتاج ہے
و کندن جوئی آب، زمینہائے آنہارا بلاکسی مدد اور آب پاشی کی سہولتوں کے
مزروع نمایند چاں چہ اکثر زمینہائے آں ان زمینداروں کی بیشتر زمینوں
چکہائے خود نمی برند۔۔۔۔26؎ میں زراعت ہوتی ہے مگروہ اپنے چکوں کو آباد کرنے کی خود کوئی کوشش نہیں کرتے
تاریخِ مظہر شاہ جہانی کے اس اقتباس سے ظاہر ہوتاہے کہ سندھ کے زمیندار گاؤں میں رہتے تھے اور کاشت کاروں سے ان کا تعلق براہِ راست تھا۔ وہ اپنی زمینوں کے خود مالک تھے مگر خود کاشت کرنے کے بجائے مزارعوں سے کام لیتے تھے۔ بسا اوقات جاگیر دار وں کے ارباب اورمقدم یہی مقامی زمیندار ہوتے تھے لہٰذا قدرتی طورپر ان کا مفاد بھی جاگیر دار طبقے سے وابستہ تھا لیکن وہ جاگیرداروں کے تابع نہیں تھے ۔ مثلاً یوسف میرک لکھتا ہے کہ ” ایک بار میں نے سہوان کے حاکم کو مشورہ دیا کہ سمیجہ اُونر قوم کے فلاں سرکش گروہ کا قلع قمع فریب اور دھوکے سے حملہ کر کے کیا جائے تو ” بعض زمیندارانِ سہواں ایں حرف را خوش نہ کردند” (میری بات سہوان کے بعض زمینداروں کو پسند نہیں آئی) اور حملے کا مشورہ مسترد ہو گیا 27؎ پروفیسر عرفان حبیب کا کہنا ہے کہ زمیندار عام کسانوں سے اونچے ہوتے تھے۔ وہ اپنے مزارعوں کو بے د خل کرسکتے تھے۔ ان کی زمینیں موروثی ہوتی تھیں اور وہ ان کو فروخت بھی کرسکتے تھے۔
جس دیار” بیداد گراں ، ناپرساں اور بیکساں” میں یوسف میرک کے بقول بے شمار ” بھیڑیے” اور ” راکشش” موجود ہوں وہاں غریب کسانوں کی زبوں حالی کا پوچھنا ہی کیا۔ وہ زمین جوتتے بوتے اور فصلیں اُگاتے مگر زمین پر ان کو کسی قسم کا اختیار نہ تھا نہ عارضی نہ مستقل اور جو غلہ وہ اپنے خون پسینے سے پیدا کرتے اس کا بیش تر حصہ جاگیر دار، مستاجر، معافی دار ملا، مشائخ، سادات اور زمیندار لے جاتے۔ جو باقی بچتا اس میں سے متعدد ” رسوم” ادا کرنے پڑتے۔ نتیجہ یہ کہ پیداوار بڑھانا تو درکنار وہ سرکاری کارندوں اور اجارہ داروں کی لوٹ مارسے تنگ آکر جنگلوں کی راہ لیتے اور ڈاکو، راہ زن بن کر دوسروں کو لوٹنا شروع کردیتے تھے۔
سندھ میں عموماً ” غلہ بخشی” یعنی بٹائی کا رواج تھا چنانچہ ترخانوں کے عہد میں کسانوں سے زمین کی زرخیزی اور آب پاشی کی سہولتوں کی مناسبت سے فصل 2/1 ،3/1 اور 4/1 وصول کیا جاتا تھا لہٰذا بقول یوسف میرک ” ملک آباد تھا اور رعیت پر قوت تھی لیکن جاگیر داروں کے دور میں کسانوں کو ” خراجِ مقاسمہ” (2/1) کے علاوہ ان گنت ” رسوم” ادا کرنے پڑتے تھے جن کو ” ستم شریکی” یا ” فروعی واجبات” یا ” سائرجہات” کہتے تھے۔ قانوناً یہ واجبات سراسر ناجائز تھے لیکن قانون کے محافظ جب خود یہ ناجائز رقمیں وصول کرتے تو کسانوں کی کون سنتا چنانچہ۔
” بہ تہمت ہائے باطلہ سکان ایں دیار را از آزاد ہائے گونا گوں دادہ ، زیادہ از جریم آنہا جرمانہ کہ از طاقتِ بشر دُور است مقررمی سازند چنا ں چہ مردم ہلاک می گردند”۔
” انھوں نے ناجائز واجبات وصول کرکے اس ملک کے باشندوں کو طرح طرح کی تکلیفوں میں پھنسا رکھا ہے۔ وہ اتنا جرمانہ لگاتے ہیں جس کی ادائیگی بشر کی طاقت سے دور ہوتی ہے لہٰذا لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔28؎
سکونت کے اعتبار سے سندھ کی دیہی آبادی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ حضری اور بدوی۔ وہ گاؤں جو دریائے سندھ کے آس پاس مستقل طورپر بسے ہوئے تھے لاندھی یا گوٹھ کہلاتے تھے۔ زیادہ آبادی انھیں علاقوں میں تھی اور آب باشی کی سہولتوں کی وجہ سے یہاں پیداوار بھی اچھی ہوتی تھی۔ اس کے برعکس کوہستانی اور ریگستانی علاقے جہاں گلہ بان قومیں رہتی تھیں بہت پس ماندہ تھے۔ ان صحرا نورد قوموں کا کوئی مستقبل ٹھکانہ نہ تھا بلکہ وہ اپنے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو ساتھ لیے چارہ گھاس کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مارے پھرتے رہتے تھے۔ ان کی عارضی بستیوں کو تھانہ یا گدھان کہتے تھے۔ یہ گھاس پھوس کی جھونپڑیاں یا اون کی چھول داریاں ہوتی تھیں جن کو بری آسانی سے جانوروں پر لادا جا سکتا تھا۔ جھونپڑیوں اور خیموں کے جھنڈ کو تومان کہتے تھے جو یک جدی خاندانوں (خیل) کا مسکن ہوتا تھا۔ تومان کا بزرگ تومان دار کہلاتا تھا۔ یہ خانہ بدوش قبیلے زیادہ تر بلوچ تھے جن کی مہمان نوازی، جفاکشی اور دلیری ضرب لمثل تھی۔ ہر تومان میں ایک مہمان خانہ ضرور ہوتا تھا اور تو مان کے ہر فرد کو مہمان داری کے مصارف کے لیے تومان دار کو شیشک (6/1) ادا کرنی پڑتی تھی۔ (شیشک کا رواج بلوچستان میں چند سال پیش تر تک تھا) یہ بلوچ قبیلے بھکر اور ٹھٹھہ کے مغرب میں کوہستانی علاقوں میں رہتے تھے۔ کلہوڑا سردار انھیں کی مدد سے برسرِ اقتدار آئے۔
شاہ جہان کے آخری ایام میں حاکموں کے ظلم و جور اور جاگیرداروں کے بے دریغ استحصال کی وجہ سے سندھ کی اقتصادی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی اور رعایا میں بے چینی بڑھتی گئی۔ کئی قومیں مثلاً سمیچہ، بلوچ اور نہمردی ایسی تھیں جنہوں نے مغلوں کی اطاعت کبھی قبول نہیں کی تھی۔ ان کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے صوبہ داروں کو مسلسل فوجی طاقت استعمال کرنی پڑتی تھی چنانچہ یوسف میرک کی کتاب اِن ” سرکش” قوموں کی سرکوبی کی خونیں داستان سے پُر ہے۔ بد امنی کا یہ حال تھا کہ شہر سہوان کا حاکم قلعے سے باہر نکلنے کی جرات نہیں کرسکتا تھا اور قلعے کی دیوار کے نیچے دن دہاڑے قتل اور لوٹ مار کی وارداتیں ہوتی رہتی تھی۔ لاہری بندر اورٹھٹھے کے درمیان تجارتی قافلے تیس میل کا سفر فوج کی نگرانی میں طے کرتے تھے۔
سندھ میں بارش برائے نام ہوتی ہے لہٰذا زراعت کا انحصار پانی کی فراہمی پر ہے۔ جس حکمران نے نہریں نکا کر اس مسئلے کو حل کرلیا وہ کامیاب رہا اور جس نے نہروں کی طرف سے غفلت برتی وہ ناکام ہوگیا۔ مغلوں نے یہ اہم فریضہ جاگیر داروں کے سپرد کردیا تھا حالاں کہ اتنا بڑا کام ان کی استطاعت سے باہر تھا۔ اگر نہریں نکال کر اُفتادہ زمینوں کو قابلِ کاشت بنایا جاتا تو ملک قحط کی بار بار آفتوں سے بچ جاتا اور خانہ بدوش قبیلے بھی آباد ہو کر پر امن زندگی بسر کرنے لگتے۔ حیرت ہے کہ اورنگ زیب کا سا عاقل شخص بھی سندھیوں کی بے چینی اور سرکشی کے اصل سبب کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ اس نے بھی یہ نہ دیکھا کہ سمیچہ یا نہمروی جن کو اس نے بزورِ شمشیر مطیع و فرماں بردار بنانے کا عزم کررکھا تھا تلاشِ معاش کے سلسلے میں مجبور ہو کر مزروعہ علاقوں کا رخ کرتے تھے اور یوسف میرک کا سا صاحبِ فہم مورخ بھی شاہ جہاں کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ ” مردُمِ مفسدو متمر دغیر از ضربت شمیشر بہ طریقِ نیک رام نمی شوند” (مفسد اور سرکش عناصر کو نیک طریقوں کے بجائے تلوار ہی کے زور سے رام کیا جا سکتا ہے) حالاں کہ وہ خود معترف ہے کہ اگرکسی دُور اندیش جاگیردار یا حاکم نے غیر آباد علاقوں میں آب پاشی کا بندوبست کردیا یا سرکش قبیلوں کو زمین دے کر بسا دیا تو حالات سدھر گئے۔ مثلاً پرگنہ چندوکہ (لاڑکانہ) میں میرابرہ نے ایک بڑی نہر نکالی (جو اب بھی موجود ہے) تو ویران اور غیر آباد علاقہ سرسبز و شاداب ہوگیا اور وہاں کئی شہر بس گئے۔ اسی طرح سمیجہ ، ابرہ اور سانگی قوموں نے خود نہریں کھودیں تو نئے دیہات وجود میں آگئے اور کسان جوق درجوق آکر وہاں آباد ہوگئے اور مزروعہ زمین ایک لاکھ جریب سے زیادہ ہوگئی اور سرکاری لگان بھی 30،40 فیصد بڑھ گئی۔29؎
اورنگزیب نے 1707ء میں اورنگ آباد دکن میں بڑی مایوسی کے عالم میں انتقال کیا۔ اس کے بعد تختِ شاہی کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی اور ملک میں طوائف الملوکی پھیلی اس سے تاریخ کا ہر طالبِ علم واقف ہے۔ اورنگ زیب نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ تینوں بیٹے سلطنت کو آپس میں تقسیم کرلیں لیکن خود اس نے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کے پیشِ نظر بیٹوں سے توقع رکھنا کہ وہ باپ کی وصیت پر عمل کریں تے عبث فعل تھا۔ شہزادہ اعظم شہزادہ معظم کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ پھر کام بخش کا کام تمام ہوا اور شہزادہ معظم شاہ عالم اول کے لقب سے تخت پر بیٹھا لیکن چار سال بعد وفات پاگیا اور اس کے چاروں بیٹے جہاں دار شاہ، عظیم الشان، جہاں شاہ اور رفیع الشان آپس میں آمادہ پیکار ہوئے۔ جہاں دار شاہ تینوں بھائیوں کو قتل کر کے بادشاہ بنا مگر ایک سال بعد عظیم الشان کے بیٹے فرخ سیر نے لال قلعہ دلی میں چچا کا گلا گھونٹ کر ہلاک کردیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا (1713ء) چھ سال کی مختصر مدت میں تخت کے چھ دعوے دار مارے گئے اور فقط ایک قدرتی موت مرا۔
یہی پُرآشوب زمانہ صوفی شاہ عنایت کا بھی ہے۔
زوالِ سلطنت کے اسباب
سلطنتِ مغلیہ کا عروج جتنا پر شکوہ تھا زوال اتنا ہی المناک ثابت ہوا۔ یوں لگا گویا یہ عظیم عمارت ریت کا گھروندہ تھی جو ہوا کے تیز جھونکے کی بھی تاب نہ لا سکی۔ مگر زوال کے آثار اورنگ زیب کے آخری ایام ہی میں ظاہر ہونے لگے تھے۔ اُدھر بوڑھا شہنشاہ اپنی ساری قوت دکن مہموں میں صرف کررہا تھا اِدھر سلطنت کے پرانے رفقا یکے بعد دیگرے اس سے کنارہ کش ہوتے جارہے تھے۔ بیٹے، امرائے دربار، ایرانی، جاٹ بندیلے، راٹھور، سی سوڈیا غرضیکہ کوئی بھی بادشاہ کی سیاسی حکمتِ عملی سے خوش نہ تھا۔ اس قحط الرجال کی وجہ سے کی وجہ سے سلطنت کے نظم و نسق میں جو خلل پڑ رہا تھا سلطان اس سے بخوبی آگاہ تھا چنانچہ شکایت کرتا ہے کہ “ازنایابیِ آدم کار آہ، آہ ” تس پروزیر سعد اللہ خان عرض کرتا ہے کہ ” جہاں پناہ، لائق آدمیوں سےس کوئی زمانہ خالی نہیں ہوتا البتہ خود غرضوں کی تہمتوں اور الزام تراشیوں پر کان دھرے بغیر، ان کا دل جیتنا اور ان کے ذریعے امورِ سلطنت سرانجام دینا، عقل مند آقاؤں کا شیوہ ہے”۔ اورنگ زیب کو اپنی اس مردم ناشناسی کا احساس ہے اور وہ سعد اللہ خان کی عرضداشت کی صداقت کو تسلیم کرتا ہے مگر پانی سے اونچا ہو چکا تھا۔ مسلک میں تبدیلی اب اس کے اختیار میں نہ تھی۔30؎
اورنگ زیب کے مشہور مورخ سر جادو ناتھ سرکار نے زوالِ سلطنت کے متعدد اسباب بیان کیے ہیں۔ مثلاً اورنگ زیب کی غلط حکمتِ عملی، اس کے جانشینوں کا پست کردار اور امرائے دربار کی نااہلی اور خود غرضی لیکن جاگیری نظام کی فرسودگی پر حیرت ہے کہ اس کی نظر نہیں پڑی حالاں کہ تمام خرابیوں کی جڑ یہی نظام تھا جو اپنا تاریخی کردار ادا کرچکا تھا اوراب اس میں مزید ترقی کی گنجائش نہ تھی۔
لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سلطنت کے زوال میں اورنگ زیب کے جانشینوں کے پست کردار کو بھی بڑا دخل ہے۔ نازو نعم کی گود میں پلے ہوئے یہ عیش پسند شہزادے جن کو نہ امورِ سلطنت کی تعلیم دی گئی تھی اور نہ نظم و نسق کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں، مسخروں، بھانڈوں ، اور خوشامدی مصاحبوں میں گھرے رنگ رلیوں میں مصروف رہتے تھے اور برسراقتدار آنے پر بھی ان مشغلوں کو ترک نہ کرتے تھے۔ چنانچہ مورخ لکھتا ہے کہ اٹھارویں صدی میں تخت دہلی کے ورثا کی تربیت اس ڈھنگ سے ہوئی کہ بڑے ہو کر وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں دوسروں پر تکیہ کرنے کے عادی ہو گئے۔ وہ آزادی سے نہ خود فیصلہ کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت رہ گئی تھی۔ اُن کے ذہن کند ہو چکے تھے اور ان کی روحیں مردہ لہٰذا وقت گزاری کے لیے وہ حرم سرا کی عورتوں ، مسخروں اور خوشامدیوں کی صحبت میں پناہ لیتے اور تخت نشین ہو کر حکومت کی باگ وزیروں کے سپرد کردیتے تھے جس کی وجہ سے امرا میں باہمی رقابتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور جب وہ کسی طاقت ور وزیر کے اثرو اقتدار سے خوف زدہ ہو کر اس کو گرانے کی غرض سے کسی دوسرے وزیر کی حوصلہ افزائی کرتے تو آخر کار اس کے دامِ اختیار میں پھنس جاتے”۔ 31؎
شخصی حکومت کا سب سے بڑا نقص ہی یہ تھا (اور ہے) کہ ریاست کی بقا و ترقی کا دارو مدار سر براہ کی شخصیت، اہلیت اور مردم شناسی پر ہوتا تھا۔ بادشاہ میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہوتی تو نظم و نسق درست رہتا،ریاست کو لائق وزرا اور حکام میسر آتے اور رعایا بھی ظالموں کی دست برد سے کسی حد تک محفوظ رہتی لیکن بادشاہ نا اہل ہوتا تو سلطنت کا وہی حشر ہوتا جو سلطنتِ مغلیہ یا اس سے پیش تر کی سلطنتوں کا ہوا۔ شخصی اور مطلق العنان بادشاہتوں کی تاریخ اسی نشیب و فراز کا آئینہ ہے۔ خواہ وہ رومتہ الکبریٰ ہو یا بنی عباس یا خاندانِ مغلیہ کی سلطنتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اورنگ زیب کے کسی جانشین میں معمولی ضلع کے نظم و نسق کی صلاحیت نہ تھی چہ جائیکہ اتنی وسیع و عریض سلطنت کا لنگر سنبھالنا جو کابل سے چاٹگام اور کشمیر سے راس کمار تک پھیلی ہوئی تھی اور آبادی و رقبہ میں پورے یورپ کے برابر تھی۔
طبقہ امرا میں بھی، جن سے نظم و نسق چلتا تھا اب پرانا سا دم دم خم باقی نہ تھا۔ اورنگ زیب سے پہلے اعلیٰ سرکاری عہدوں کے لیے بھرتی تین حلقوں سے ہوتی تھی۔ اول ترکستان اور ایران سے آنے والے قسمت آزما خاندان جن کا پیشہ سپہ گری تھا یا جو اپنی ذہانت اورلیاقت سے سرکار دربار میں رسائی حاصل کرلیتے تھے ۔ دوئم مقامی نو مسلم خاندان کے امرا و شرفا اور سوئم راجپوت اور کایتھ۔ اورنگ زیب کے طرزِ عمل سے بیرونِ ملک سے آمد کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ راجپوت امرا بھی ایک ایک کر کے علیحدہ ہوتے گئے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی مسلمانوں کے طبقہ امرا اور تورانی نژاد امرا میں اقتدار کی خاطر رسہ کشی ہونے لگی۔ اونگ زیب کے بعد تو اِن رقابتوں نے باقاعدہ کشت و خون کی صورت اختیار کرلی۔ مثلاً نظام الملک آصف جاہ دکن کی صوبہ داری پر اپنے تین حریفوں کو شکست دے کر قابض ہوا۔ اسی طرح گجرات کی صوبے داری کی خاطر شجاعت خان اور سر بلند خان اور ستم خان کے مابین جنگ چھڑ ی۔ شجاعت خان اور سربلند خان مارے گئے اور رستم علی خان نے شکست کھائی۔ سندھ میں نواب عطر خان، فرخ سیر کے عہد میں ٹھٹھہ کا صوبے دار مقرر ہو کر آیا مگر اس کو میر لطف علی خان سے مقابلہ کرنا پڑا۔ دونوں ایک سال تک لڑتے رہے یہاں تک کہ عطر خان قتل ہوا اور میر لطف علی خان نے سندھ کی صوبے داری پر قبضہ کرلیا۔ لطف یہ ہے کہ شاہی احکام کی اس باغیانہ خلاف ورزی کے با وصف فرخ سیر نے میر لطف علی خان کو شجاعت خان کے خطاب سے نوازا32؎ غرضیکہ دہلی دربار مختلف گروہوں کی سازشوں کا اڈا بن گیا تھا۔ تورانی، ایرانی اور ہندوستانی امرا دن رات اپنے ذاتی مفاد کی خاطر سیاسی داؤں پیچ میں مصروف رہتے تھے۔ کسی کو سلطنت کے مستقبل کی فکر نہ تھی۔ اس کے علاوہ عالیم گیری عہد کے بہت سے امرا شہزادوں کی معرکہ آرائیوں میں پہلے ہی جان نذر کرچکے تھے۔ جو بچ رہے تھے انھوں نے دربار کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر گوشہ نشینی اختیار کرلی تھی۔
فرخ سیر(1713۔1719ء) نہایت ظالم، ناکارہ اور عیش پرست ثابت ہوا۔ اس نے چچا کے قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ جس شخص کی طرف سے بھی خطرہ محسوس ہوا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ امیرالامرا ذوالفقار خان اور اجہ سبھ چند دیوان کی زبانیں کٹوا دیں۔ جہاں دار شاہ کے عہد کے بہت سے امرا کو تہ تیغ کیا۔ جہاں دار شاہ کے بیٹے اعزالدین اور اعظم شاہ کے بیٹے اوراپنے چھوٹے بھائی ہمایوں بخت کو اندھا کرکے قیدخانے میں ڈلوا دیا۔ شہر کیا میدان حشر تھا جس میں کوئی کسی کا پرسانِ حال نہ تھا اور نہ کسی کی جان و مال، عزت، آبرو سلامت تھی۔ انھیں حالات سے غم زدہ ہو کر شاہ حاتم دہلوی نے جو شہر آشوب لکھا وہ نظم و نسق کی ابتری، طبقہ امرا کے انحطاط اور شہریوں کی مالی پریشانیوں کی بڑی سچی تصویر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:
شہوں کے بیچ عدالت کی کچھ نشانی نہیں
امیروں بیچ سپاہی کی قدر دانی نہیں
بزرگوں بیچ کہیں بوئے مہربانی نہیں
تواضع کھانے کی چاہو کہیں تو پانی نہیں
گویا جہان سے جارہا سخاوت و پیار
امیرزادے ہیں حیران اپنے حال کے بیچ
تھے آفتاب پر اب آگئے زوال کے بیچ
پھرے ہیں چرغے سے ہر دن تلاشِ مال کے بیچ
وہی گھمنڈ امارت ہے پر خیال کے بیچ
خدا جو چاہے تو پھر ہو، پر اب تو ہے دشوار
میر جعفر زٹلّی(پیدائش1657ء) اس دور کے ایک ہزل گو شاعر تھے جو ہنس ہنسا کر لوگوں کو خوش کرتے اور اپنا پیٹ پالتے تھے لیکن حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ وہ بھی ضبط نہ کرسکے۔ وہ اپنی ہزلوں میں کبھی شہزادوں کی نا اہلیوں اور آپس کی رقابتوں پر فقرے چست کرتے ہیں اور کبھی معاشرتی افراتفری کا ماتم کرتے ہیں۔ شہزادہ معظم شاہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ:
نخستیں کلاں، ترکہ برکھنڈ کرو اول بڑے بیٹے نے سب کھنڈت کردی
ہمہ کاروبارِ پدر بھنڈ کرو باپ کا سارا کاروبار بھنڈ کردیا
چناں لوٹ شد بستیِ بھگ نگر حیدرآباد میں وہ لوٹ مچی
نہ خذ ما صفا ماند نہ ماکدر کہ اچھا برا کچھ نہ بچا
جہاں ہووے ایسے کلچھن سپوت لگے خلق کے منھ کو کالک بھبوت
محمد اعظم شاہ کا ذکر یوں کرتے ہیں،
دگرشاہ واعظم ہمہ کندور بہ رسوائی انداخت کارپدر
بہ خوش دامن و حسپورہ ساختہ بہ للو پتو کارِ درباختہ
ساس اور سالے کے ساتھ مل کر اور ایروں غیروں میں وقت صرف کرنے لگا
فرسذایں ناں بہ شب پان پھول ملا کر کیا کام سب خاک دُھول
عوام کی پریشان حالی کا حال یوں بیان کرتے ہیں۔
زلت کے آنسوؤں جگ روتا ہے نہ میٹھی نیند کوئی سوتا ہے
صدائے توپ و بندوق است ہرسو بسر اسباب و بندوق است ہرسو
دو ادوہر طرف بھاگڑ پڑی ہے بچہ در گود، سر کھٹیا پڑی ہے
کٹاکٹ و لٹالٹ ہست ہرسو جھٹا جھٹ و پھٹا پھٹ ہست ہرسو
برہر سو مار مار دھاڑ دھاڑاست اُچل چال و تبر خنجر کٹاراست
فرخ سیر تخت نشین ہوا تو اس کے سکے پر یہ شعر کندہ کیا گیا؎
میر جعفر زٹلّی نے سکے کو ہجو میں بدل کر کہا
سکہ زدبرگندم و موٹھ و مٹر مچھر ماربادشاہ فرخ سیر نے گندم
بادشاہ پستہ کش فرخ سیر موٹھ اور مٹر پر مہر لگا دی ہے
بد نصیب شاعر کو کیا خبر تھی کہ کم ظرف بادشاہ ایک بے ضرر شعر کی پاداش میں اس کو قتل کروادے گا۔ جعفرزٹلّی اردو کا واحد شاعر ہے جس کو ایک شعر کے عوض جان دینی پڑی۔ صوفی شاہ عنایت بھی فرخ سیر ہی کے عہد میں شہید ہوئے۔
صوفی عنایت شاہ کی تحریک
صوفی شاہ عنایت نے جس وقت جھوک میں تعلیم و تبلیغ شروع کی تو سندھ کے بیش تر مشائخ، صوفیا اور سادات اپنے فرائض منصبی کو فراموش کر کے خالص دنیا دار زمیندار بن گئے تھے۔ اس اندھیرے میں صوفی شاہ عنایت کے علم و فضل کی، اُن کی خدا ترسی ، درد مندی اور بے لوث خدمتِ خلق کی روشنی پھیلی تو ان کے گرد ارادت مندوں کا ہجوم ہونے لگا۔ مگر صوفی شاہ عنایت ان روایتی صوفیوں میں نہ تھے جو حالات کو بدلنے کے بجائے صبرو قناعت کی تلقین کرتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ دنیاوی زندگی چندہ روزہ ہے لوگوں کو توشہ آخرت جمع کرنے کا درس دیتے ہیں۔ وہ ان علمائے دین میں بھی نہ تھے جن کے نزدیک دولت کی مساوی تقسیم ہی مساوات محمدی کی اساس ہے۔ حالاں کہ دولت پیدا کرنے کے ذرائع مثلاً زمین، فیکٹریاں، کارخانے اور بینک وغیرہ اگر چند افرادکی ذاتی ملکیت ہوں تو دولت کی مساوی تقسیم کیوں کر ممکن ہوگی۔ صوفی شاہ عنایت نے قانونِ معیشت کا یہ راز پالیا تھا کہ اصل چیز پیداواری عمل ہے اور اصل مساوات وہ ہے جو پیداواری عمل کے دوران قائم ہو نہ کہ تقسیم کے دوران ورنہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹولا بھی مال کو آپس میں بانٹ کر کھاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم پیداواری عمل میں مساوی شرکت کے بغیر ممکن ہی نہیں لہٰذا صوفی شاہ عنایت نے پیداواری عمل میں مساوی شرکت پر زور دیا۔ ان کا راسخ عقیدہ تھا کہ مساواتِ محمدی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ کھیتی باڑی اجتماعی اصولوں پر کی جائے، پیداواری عمل میں سب لوگ برابر کے شریک ہوں اور پیداوار کو حسبِ ضرورت آپس میں تقسیم کرلیں۔ صوفی شاہ عنایت کے مرید فقیروں نے یہ تجویز بہ خوشی منظور کرلی اور اجتماعی کھیتی باڑی میں مصروف ہوگئے۔
اجتماعی زراعت صوفی شاہ عنایت کی ایجاد بندہ نہ تھی بلکہ ان سے بہت پہلے قبیلہ داری نظام کے دور میں بھی اجتماعی زراعت کا رواج عام تھا۔ عین ممکن ہے کہ صوفی صاحب کے زمانے میں بھی بعض کوہستانی قوموں بالخصوص بلوچوں میں یہ طریقہ رائج ہو اور صوفی صاحب نے اس کی افادیت کو محسوس کرلیا ہو۔ ان کا سید محمد جونپوری (1443۔1505ء) کی مہدوی تحریک سے متاثر ہونا بھی بعیدازقیاس نہیں ہے کیوں کہ سید محمد جونپوری سمہ حکمران جام نندا کے عہد میں ڈیڑھ دو سال تک ٹھٹھے میں مقیم رہے تھے اور بہت سے لوگ جن میں میاں آدم شاہ کلہوڑا بھی تھے ان کے مرید بن گئے تھے۔ سید محمد جنھوں نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا بڑے عالم فاضل بزرگ تھے۔ انھوں نے اپنی مہدوی برادری کو “دائرے” کا نام دیا تھا جو مکمل مساوات اور ابدیت کی علامت ہے۔ اُن کے دائرے میں چھوٹے برے امیر غریب کا امتیاز نہ تھا۔ مرید دائرے میں اجتماعی زندگی بسر کرتے تھے اور ضروریاتِ زندگی آپس میں برابر تقسیم کرلیتے تھے۔33؎
صوفی شاہ عنایت کا تجربہ بہت کامیاب ہوا۔ جھوک میں آباد فقیروں کو نہ بٹائی دینی پڑتی نہ بے گار کرنی پڑتی اور نہ پٹواری قانون گو کو ” ستم شریکی” رسوم ادا کرنے پڑتے تھے لہٰذا صوفی شاہ عنایت کی شہرت جلد ہی دور دور پھیل گئی اور ہر جگہ ان کے نئے تجربے کا چرچا ہونے لگا۔ اُس پر مستزاد یہ کہ سادات ہلڑی کے فقیر جو اب تک اپنے زمینداروں کے مرید تھے شاہ عنایت کے حلقہ ارادت میں چنانچہ تحفہ الکرام میں رقم ہے کہ
” فقرائے بلری خاندان شان بہ معائنہ فروغ و مجد ایں سلسلہ از آنہا بریدہ بایں ہامی پیوستند” 34؎
” جو درویش پہلے خاندانِ ہلری سے وابستہ تھے وہ صوفی شاہ عنایت کے سلسلے کا فروغ دیکھ کر سادات کو ترک کرکے اس نئے سلسلے مین شامل ہوگئے”
لہٰذا ” فقیروں کی جاعت سندھ کے خاندانی پیروں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی۔” 35؎
اس تحریک کی مقبولیت سے خاندانِ سادات کے مریدوں ہی کی تعداد میں کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ بابو پلیجہ اور آس پاس کے دوسرے علاقوں کے مزارع بھی متاثر ہوئے۔ ” در زمینِ ایشاں فقرارگ و ریشہ دو اندہ بودند” (صوفی شاہ عنایت کے فقیر اُن کی زمینوں میں بھی ریشہ دوانیاں کررہے تھے۔ یعنی اجتماعی زراعت کی تبلیغ کررہے تھے)۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمینداروں کے مزارعے مطالبہ کرنے لگے کہ ہماری زمینوں میں بھی صوفی شاہ عنایت کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ مگر پیداوار میں مساوی شرکت کے اصول کو تسلیم کرنے کے لیے زمیندار ہر گز تیار نہ تھے۔ انھوں نے محسوس کرلیا کہ اس انقلابی فتنے کا اگر فوراً تدارک نہ کیا گیا تو سندھ میں جاگیر داری اور زمینداری نظام خطرے میں پڑجائے گا۔ لہٰذا خطرے کا سدِ باب کرنے کی غرض سے زمینداروں نے جن میں ہلڑی کے شاہ عبدالکریم کے جانشین سید عبدالواسع اور شیخ ذکریا بہاؤلدین کے جانشین شیخ سراج الدین اور پلیجانی کے زمیندار نور محمد بن منبہ پلیجو اور حمل بن لاکھا جاٹ پیش پیش تھے، میر لطف علی خان صوبے دار ٹھٹھہ سے فریاد کی کہ صوفی شاہ عنایت کو اجتماعی کھیتی سےمنع کیا جائے لیکن صوفی کی زمین مدد معاش کی معافی زمین تھی۔ صوبے دار کا اس پر کوئی اختیار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے حکومت کی جانب سے مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا البتہ زمینداروں کو اجازت دے دی کہ وہ صوفی اور ان کے فقیروں سے جس طرح چاہیں نپٹ لیں۔ صوبے دار کا اشارہ پا کر زمینداروں نے جھوک کی بستی پر اچانک دھاوا کردیا مگر منھ کی کھائی البتہ کئی فقیر مارے گئے اور لوگوں کا مالی نقصان بھی ہوا۔ شہدا کے وارثوں نے زمینداروں کی اس لا قانونیت کے خلاف شاہی دربار میں استغاثہ دائر کیا تو وہاں سے حکم صادر ہوا کہ ” مرتکبین بادشاہ کے حضور آکر بے گناہوں کے خون کا حساب دیں ۔ چوں کہ انھوں نے شاہی حکم کی تعمیل سے انحراف کیا لہٰذا خوں بہا کے عوض سلطانی دستورالعمل کے مطابق ان کی زمینیں مقتولین کے ورثا کے حوالے کر دی گئیں۔”36؎
فقیروں کی اس قانونی جیت سے گرد پیش کے مزارعین کے حوصلے بڑھ گئے اور سرکاری حکام اور زمینداروں کی بھی وہ پہلی سی ہیبت نہ رہی بلکہ
کثر غربا و سائر مردم اضلاع در مہدِ امان ان اضلاع کے اکثر غربا اور سائر
آن اہل اللہ از جنگِ تظلم زمینداران زمینداروں کے ظلم سے نجات پاکراس
رہائی یا فتہا مامون نشتند اہل اللہ (صوفی شاہ عنایت) کے دامینِ پناہ میں امن سیرہنے لگے
اس سے پتہ چلتا ہے کہ صوفی شاہ عنایت کی کسان تحریک زیریں سندھ میں کئی ضلعوں میں پھیل گئی تھی اور صوفی صاحب کی پشت پناہی کی وجہ سے لوگوں میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ زمیندار اب ان پر ہاتھ اٹھانے کی جرات نہ کرسکتے تھے۔ اسی اثنا میں ” جور زمانہ سے تنگ آکر فقیروں کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہونے لگا اور ہر درو دیورا و گنبد و خانقاہ سے ہمہ اوست کی صدائیں بلند ہونے لگیں”۔ 37؎
فرخ سیر نے غالباً یہ سمجھ کر کہ میر لطف علی خان فقیروں کے ساتھ نرمی برت رہا ہے اس کو بر طرف کر کے نواب اعظم خان کو 1716ء میں ٹھٹھہ کا صوبے دار مقرر کردیا۔ زمینداروں نے اس تبدیلی سے فائدہ اٹھایا اور اعظم خان کے کان بھرنے شروع کردے۔ شاید نواب کو صوفی شاہ عنایت سے ذاتی پرخاش بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ اعظم خان ایک بار صوفی شاہ عنایت سے ملاقات کے لیے گیا تو فقیروں نے اس کو یہ کہہ کر روک دیا کہ حضرت اور ادو وظائف میں مشغول ہیں۔ جب صوفی صاحب سے ملاقات ہوئی تو اعظم خان نے کہا کہ ” درِ درویش را درباں نہ شاید( درویش کے دروازے پر دربان اچھے نہیں لگتے) صوفی صاحب نے بے تامل جواب دیا کہ ” بہ یک شاید تاسگِ دنیا نہ آید” (ٹھیک ہے تاکہ دنیا کا کتا اندر نہ آنے پائے) ۔ یہ امر اعظم خان کی ذاتی رنجش کا باعث بن گیا۔38؎
یہ روایت صحیح ہو یا غلط، نواب اعظم نے بہر حال اجتماعی زراعت کی تحریک کو کچلنے کا فیصلہ کرلیا اور چھیڑ چھاڑ شروع کردی۔ اس نے صوفی شاہ عنایت سے وہ واجبات طلب کیے جو ” ممنوعہ سلطانی” تھے۔ صوفی نے جواب دیا کہ جب یہ واجبات کی بادشاہ کی طرف سے معاف ہو چکے ہیں تو آپ کو ان کی وصولی کا کیا حق ہے۔ اس جواب سے نواب تلملا اٹھا۔ اس نے پیش کاروں اور متصدیوں سے مشورہ کرکے بادشاہ کے پاس شکایت لکھ بھیجی کہ صوفی شاہ عنایت اور ان کے فقیر دعوئے سلطنت کررہے ہیں اور خلیفتہ اللہ کا حکم ماننے سے انکاری ہیں 39؎ فرخ سیر نے امرِ واقعی کی تحقیقات کیے بغیر حکم صادر کردیا کہ باغیوں کو بزورِ شمشیر اطاعت پر مجبورکیا جائے۔
مرکز سے اجازت ملتے ہی نواب اعظم خان جھوک پر حملے کی تیاریوں میں مصروف ہوگیا۔ اس نے سندھ کے سب ہی رئیسوں کے نام پروانے جاری کیے کہ اپنے اپنے سپاہی لے کر مدد کو آؤ۔
میاں یار محمد کلورہ و سائرزمینداران و جملگی (اعظم خان نے) میاں یار محمد کلہوڑہ ، تمام
اہل و احشام ایں الکہ، کہ با فقرا کینہ کہنہ می زمینداروں اوراس خطے کے ان تمام لوگوں
داشتند، احکامِ اعانت حاصل کردہ با افواج کے نام معاونت کے احکام حاصل کرلیے
برون ازا حاطہ شمار واز مور ملخ بسیار ، کہ از تھے جو فقیروں سے پرانی دشمنی رکھتے تھے
جد سیوی داور تاکنارہ دریائے شور جمع آمدہ یوں ایک ایسی فوج تیارکرکے فقیروں پر حملہ کیا جو شمار نہیں کی جا سکتی تھی اور چیونٹیوں اور ٹڈیوں سے بھی زیادہ تھی اور سبی و ڈھاڈر سے سمندر تک کے علاقے سے جمع کی گئی تھی۔
صوفی شاہ عنایت صلح پسند بزرگ تھے۔ ان کو جب زمینداروں کی مخالفت اور اعظم خان کی فوجی تیاریوں کی خبر ملی تو وہ افسوس کرنے لگے کہ ” میں بازار عشق میں یہ سودا اس لیے تو نہیں لایا تھا اورنہ میں چاہتا تھا کہ اس طرح کا شورو غل بپا ہو کہ داروگیر کا میدان آراستہ ہو جائے”۔ جب دشمن کی فوجوں نے جھوک کا رُخ کیا تو فقیروں نے تجویز پیش کی کہ کیوں ہ ہم ان پر راستے میں حملہ کردیں تاکہ شاہی لشکر کو اپنی صفیں آراستہ کرنے کا موقع نہ ملے اور جھوک محاصرے سے بچ جائے مگر ” شاہِ خدا آگاہ نے پیش دستی کی اجازت نہیں دی”۔
جھوک فقیروں کی پرامن بستی تھی فوجی چھاؤنی نہ تھی۔ فقیروں کے پاس ان کی ” کاغذی” تلواروں کے سوا جن کے دستے لکڑی کے تھے اگر کوئی اسلحہ تھا تو وہ کاٹھ کا ایک زنبورچہ تھا جب کہ دشمن ” تو پہائے پیل کش روئیں” (ہاتھیوں کو ہلاک کرنے والی لوہے کی توپیں) سے مسلح تھے۔ مگر میاں یار محمد (خدایار خان کلہوڑا والی بھکر) اور میراں سنگھ کھتری ملتانی کے خطوط سے جو میدانِ کارزار سے لکھے گئے تھے اندازہ ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کے دستور کے مطابق جھوک کے گرد کچی مٹی کی مضبوط دیواری موجود تھی اور گہری خندق بھی کھدی ہوئی تھی جو پانی سے بھری تھی۔41؎
میاں یار محمد نے جھوک کے محاصرے کے دوران جو خط اپنے بیٹے میاں نور محمد کو فارسی میں لکھا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاہی لشکر 12 اکتو بر 1717ء کو یا اس سے دو چار دن پیش تر دریائے اوتھل سے کوچ کرکے پہنچا اور بستی سے ایک میل کے فاصلے پر مقیم ہوا البتہ یہ معلوم نہ ہوسکا کہ حملہ آوروں اور فقیروں کی تعداد کیا تھا۔ میران سنگھ کھتری ملتانی کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ ” نواب اعظم خان کی جمعیت قلیل تھی” اور مقابلہ دراصل خدایار خان کی کثیر فوج اور فقیروں ہی میں ہوا۔ وہ لکھتا ہے کہ ” قلعہ مفسد” کو ایک جانب خدا یار خان نے محاصرہ کیا اور ” بہ آوازِ بندو قہائے برق شرائر و جزائر عد نوائر ہوش ربائے مقہور شدند” (برق گرانے والی بندوقوں اور رعد کی سی ہوش ربا آواز پیدا کرنے والے جزیروں (؟) سے دشمن پر قہر برسانے لگے) اور دوسری طرف نواب اعظم خان نے مورچہ لگایا اور “بہ تیرو خدنگ ہنگامہ آرائی معرکہ جنگ گردیدند (تیروں سے جنگ کا ہنگامہ برپا کیا) میران سنگھ نے اپنے محسن میاں خدا یار خان کی فوجی برتری اور شاہی لشکر کی کمتری کو بڑی ہوشیاری سے واضح کیا ہے۔ فقیروں کی جمعیت کو وہ دس ہزار سوار بتاتا ہے جو سراسر غلط ہے۔ ان کے پاس گھوڑوں کجا اتنے تو آدمی بھی نہ تھے۔ میاں یار محمد نے اپنے خط میں فقیروں کے شب خون مارنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی تعداد سترہ سو پیادہ تھی” کہ در حقیقت روحِ تمام مفسدان بو”۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ فقیروں کی کل تعداد دو ڈھائی ہزار سے زیادہ نہ تھی اور ان کے پاس آتشیں اسلحہ بالکل نہ تھا۔
شب خون کا واقعہ 12 اکتوبر 1717ء کو اسی رات پیش آیا جس دن شاہی لشکر نے جھوک کا محاصرہ کیا۔ میاں یار محمد لکھتے ہیں کہ:
“اتوار کی رات تھی۔ ہمارا لشکر گھراؤ ڈالے پڑا تھا۔ ابھی ایک پہر رات باقی تھی کہ مفسدوں کے ایک ہزار سات سو پیادے شب خون کے ارادے سے کسی نہ کسی طرح لشکر تک پہنچ گئے اور جوق در جوق کئی جگہوں پر لشکر میں گھس آئے اور بلا خوف و تردد حملے کرنے لگے چنانچہ لشکر کے بہت سے آدمی کام آئے البتہ ہمارے دلیروں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور گنتی کے چند مفسد ہی اپنی جان جان سلامت لے جا سکے” 42
” اس شب خون میں ‘اکثرپھوار من جملہ قاسم پسر گہرام اور سید بولہ وکیل ٹھٹھہ و احمد بوبکانی و اودھیجہ قوم کے ہمارے بھائی اور دوسرے زمیندار بھی مارے گئے”۔
جس وقت یہ حملہ ہوا تو وہ سپاہی جو میاں یار محمد کے خیمے کے گرد پہرے پر مامور تھے ” ادھر اُدھر ہوگئے” (شاید جان بوجھ کر) مگر خیریت گزری کہ میاں یار محمد کے دو بیٹے میاں داؤد میاں غلام حسین اور بھائی میر محمد بن میاں نصیر محمد موقعہ واردات پر موجود تھے۔ چنانچہ انھوں نے ” غبارِ فتنہ رابآبِ شمشیر فرو نشاند ند” ۔ اس چپقلش میں میاں غلام حسین زخمی ہوئے۔
محاصرے کو دو مہینے گزرگئے مگرشاہی لشکر توپ و تفنگ سے لیس ہونے کے با وصف جھوک پر قبضہ کرنے کی جرات نہ کرسکا۔ اسی اثنا میں صاحبزادہ سید حسین خان اور کئی زمیندار نواب اعظم کے حسبِ پروانہ کمک لے کر جھوک پہنچ گئے لیکن شاید ان ہی دنوں سیلاب آگیا اور”گردِ قلعہ مفسد طغیانی آب بمرتبہ بود کہ از چہار طرف تازہ کردہ نشانِ خشکی نمایاں نمی شد” (صوفی عنایت کے ” قلعے” کے گرد پانی اس کثرت سے تھا کہ چاروں طرف چار پانچ میل تک خشکی کا نشان نظر نہیں آتا تھا) بہرحال صاحبزاد صاحب کی فوج نے کسی نہ کسی طرح پانی عبور کیا اور جھوک کی چہاردیواری کے قریب مورچہ لگایا۔ میاں یار محمد فرزندِ ارجمند کے اس کمالِ بے مثال کی قصیدہ خوانی فرماتے ہوئے یوں گہرافشاں ہیں گویا موصوف نے ہفت خواں فتح کرلیا ہو۔ لکھتے ہیں کہ
سپاہ پادشاہی ، فتح یا باں بادشا کی فوج فتح یاب ہے اور
عدواز سوزغم، بس دل کباباں دشمن کا دل شوزِ غم سے کباب ہے
سپاہِ پادشاہی درشکر خند بادشاہ کی فوج مسکرا رہی ہے اور
عدوں چوں غنچہ، دستارازسر افگند دشمن نے کلی کی مانند اپنی پگڑی سر سے اتارپھینکی ہے
سپاہ پادشاہی درشکر خند بادشاہ کی فوج کا دل باغ باغ ہے اور
عدو چوں بوم، درویراں فتادہ دشمن اُلوؤں کی مانند ویرانے میں پڑا ہے
سپاہِ پادشاہی، شادو فیروز بادشاہ کی فوج شاد اور کامیاب ہے
عدو و لشکر ش، ناشاد ودل سوز بادشاہ کی فوج خوش خرم ہے اور
عدو ہر دم بہ غم ہم ارتباط است دشمن ہر لحظہ غم سے دوچار ہے
سپاہ پادشاہی رُوبہ شادی بادشاہ کی فوج کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے
عدو عاجز، بدستِ نامرادی دشمن عاجز و نامراد ہے
سپاہ پادشاہی پرشکوہ است بادشاہ کی فوج پر شکوہ ہے اور
عدواز جانِ خود ہر جاستوہ است دشمن اپنی جان سے تنگ ہے
سپاہِ پادشاہی، دل خروشاں بادشاہ کی فوج دل دہلانے والی ہے اور
عدو چوں مردگاں ، ازلب خموشاں دشمن کے ہونٹ مردوں کی طرح خاموش ہیں
سپاہ پادشاہی، نصرت اندوز بادشاہ کی فوج کا اثاثہ جیت ہے
نشستہ برعدو پیکاں جگردوز وہ دشمن پر سینے میں پیوست ہونے والے تیر کی مانند چڑھی ہوئی ہے۔
آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ صاحب زادہ بلندا قبال عنقریب “آن بدسگالِ لعین” (صوفی شاہ عنایت ) کو قتل کردیں گے یا گرفتار۔43؎
اس بات کو دو مہینے گزر گئے لیکن فقیروں کی قوتِ مقاسمت میں کمی آئی اورنہ شاہی فوج ان کو زیر کرسکی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک صبح” خان والا شان اور نواب عالی مکان” ہاتھیوں پر سوار ہو کر” شیرانہ و دلیرانہ” جھوک کی چہاردیواری کے قریب آئے اور ” دلیران نبردکیش و دلاورانہ شہامت اندیش” سے کہا کہ ” پہلے تم اس چہارد یواری کو توپ اور بندوق سے دھنیے کی رُوئی کی طرح ہوا میں اُڑا دو پھر ہم فقیروں کے خرمنِ حیات کو تلواروں کی آگ سے جلا کر خاک کردیں گے”۔ مگر اتفاق سے وہاں پر صوفی کا کوئی جاسوس موجود تھا۔ اس نے فقیروں کو دشمن کے اس منصوبے سے آگاہ کردیا لہٰذا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔
محاصرہ چار مہینے تک جاری رہا۔ فقیروں کے پاس توپیں بندوقیں نہ تھیں لہٰذا اُن کو شب خون مارنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ طریقہ اتنا کار آمد ثابت ہوا کہ میر علی شیر قانع کے بقول ” حملہ آور تباہی کے قریب جا پہنچے تھے”44؎ صوفی عنایت نے فقیروں کو ہدایت کردی تھی کہ شب خون نہایت خاموشی سے مارو لیکن ایک رات کسی فقیر نے غلطی سے اسمِ ذات (اللہ) کا نعرہ لگادیا اور دوسرے بھی اس کے شریک ہو گئے جس کی وجہ سے لشکر میں اپنے اور پرائے ظاہر ہو گے اور بیش تر فقرا تلوار کا لقمہ بن گئے” 45؎
شاہی لشکر میں جاسوسوں کی موجودگی سے اور اس بیان سے کہ نعرہ لگانے کی وجہ سے لشکر میں ” اپنے اور پرائے ظاہر ہو گئے” ۔ یہ گمان ہوتا ہے کہ کچھ فقیر خفیہ طورپر دشمن کی فوج میں شامل ہو گئے تھے اور عام لشکریوں کو اپنا ہمدرد بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ شاہی لشکر چوں کے بھاڑے کے سپاہی تھے اور جھوک سے ان کو نہ کوئی ذاتی عناد تھا اور نہ ذاتی مفاد وابستہ تھا لہٰذا ان کو نواب اور زمینداروں سے منحرف کرنا چنداں دشوار نہ تھا ۔ ہمارے اس قیاس کو محاصرے کی طوالت اور ناکامی سے مزید تقویت ملتی ہے۔
شب خون میں فقیروں کو شکست سے نقصان ضرور پہنچا مگر ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور وہ دشمن سے بدستور مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار جب فقیروں پر فتح پانے کا کوئی امکان نہ رہا تو دشمن نے دغا و فریب سے کام لیا اور 1 جنوری 1718ء کو صوفی شاہ عنایت کے سامنے صلح کی تجویز پیش کی گئی۔ ” میاں خدا یار کلہوڑا کا بیٹا محمد خان اور شہداد بلوچ وغیرہ سالارانِ فوج نے قرآن کو درمیان میں رکھ کر عہد کیا کہ فقیروں کی جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا” 46؎ صوفی شاہ عنایت کے بعض رفقا نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ قسمیں اور عہدو پیمان دشمن کی چالیں ہیں۔ ان کے دھوکے میں نہ آئیے اور مقابلہ جاری رکھیے مگر خدا پرست صوفی قرآن کی قسم پر کیسے شک کرسکتا تھا چنانچہ انھوں نے صلح کی تجویز منظورکرلی۔ جھوک کا پھاٹک کھول دیا گیا اور شاہی فوج نے بستی پر بلا کسی مزاحمت یا خوں ریزی کے قبضہ کرلیا۔ بعد ازاں صوفی شاہ عنایت کو بڑے احترام کے ساتھ نواب اعظم خان کے خیمے میں صلح نامے پر دستخط کرنے کے بہانے لایا گیا لیکن وہاں پہنچتے ہیں گرفتار کرکے ہتھکڑیاں، بیڑیاں پہنا دی گئیں۔
تب شاہی انتقام کی آگ نے جھوک کا رُخ کیا اور فقیروں کا قتلِ عام شروع ہوا۔ ان کے گھر جلا دیے گئے ۔ ان کا اثاثہ لوٹ لیا گیا اور بستی کی چہار دیواری مسمار کردی گئی۔ جھوک کی اجتماعی کھیتی سیلابِ خون میں ڈوب گئی۔ نہ بیج بونے والے بچے نہ فصل کاٹنے والے۔
جھوک کو نیست و نابود کرنے کے بعد نواب اعظم خان ٹھٹھہ واپس آیا اور صوفی شاہ عنایت دربارمیں طلب کیے گئے۔ میرعلی شیرقانع راوی ہیں کہ صوبے داری اور صوفی کے مابین دربار میں جو سوال و جواب ہوا وہ ” طوفانی داستان” ہے۔ مختصر یہ کہ نواب نے جتنے سوال کیے صوفی شاہ عنایت نے ان کے جواب خواجہ حافظ شیرازی کی زبان میں دیے۔47؎
نواب اعظم خان: بتاؤ تم نے یہ شورش کیوں برپا کی؟
صوفی شاہ عنایت :
آں روز کہ تو سنِ فلک ذیں کردند آرائش مشتری زپردیں کردند
ایں بود نصیب ماز دیوانِ قضا ماراچہ گنہ، قسمت ماایں گردند
جس دن خدا نے آسمان کو گردش کا حکم دیا اور مشتری ستارے کو سات چھوٹے ستاروں کی جھرمٹ سے آراستہ کیا خدا کی عدالت سے میرا یہی نصیب مقرر ہوا تھا اس میں میرا کیا قصور، میری قسمت ہی میں یہ لکھا تھا۔
شیخ محمد رضا شاعر نے جو اعظم خان کے پاس بیٹھا تھا کہ کہ ؎
دوست بیدار، بشو، عالم خواب است اینجا دوست عالمِ خواب سے جاگ جاؤ
حرفِ بیہودہ مگوپاء حساب است اینجا بیہودہ باتیں مت کرو کہ یہ تمھارا وقتِ حساب ہے
صوفی شاہ عنایت:
درکوئے نیک نامی مارا گذرنہ دادند مجھ کو نیک نامی کے کوچے میں گھسنے نہیں دیا گیا
گر تو نمی پسندی، تغیر کن قضارا تجھ کو اگرپسند نہیں تو حکمِ خداوندی کو بدل دے
اعظم خان: پھر تو مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔
شاہ عنایت: البلاء للولاء کا للہب للذہب
اعظم خان: تم نے اپنے آپ کو کیوں بدنام کیا اور مصیبت کا شکار ہوئے۔
شاہ عنایت:
ہرگز نہ میرد آنکہ دلش زندہ شدزِ عشق وہ شخص جس کا دل عشق سے زندہ ہے کبھی نہیں مرتا
ثبت است بر جریدہ عالم دوامِ ما ہماری ابدیت کی مہر دفترِ کائنات پر لگی ہوئی ہے
اعظم خان : حاکم وقت کی اطاعت کیوں ترک کی؟
شاہ عنایت
مامریداں رُوبہ سوئے کعبہ چوں آریم چوں ہم مرید اپنا منہ کعبے کی طرف کیسے کریں
روبہ سوئے خانہ خمار دارد پیرما جب کہ ہمارے پیر کا منھ مے خانے کی طرف ہے
اعظم خان: اب اپنی خواہشوں کا ناکام ہونے کا غم کیوں کرتے ہو۔
شاہ عنایت:
من ازاں دم کہ وضو سا ختم از چشمہ عشق میں نے جس وقت عشق کے چشمے پر وضو کیا
چار تکبیر زدم یکسرہ برہرچہ کہ ہست اسی وقت ہستی کی ہرشے کو سات سلام کرلیا
اعظم خان نے جب دیکھا کہ یہ شخص مجھ سے نہ ڈرتا ہے نہ اپنے کیے پہ نادم ہوتا ہے اورنہ جان بخشی کی التجا کرتا ہے تو اس نے حکم دیا کہ گستاخ صوفی کو قید میں ڈال دو۔ شاہ عنایت نے چلتے چلتے یہ شعرپڑھا کہ؎
ساقیا برخیزدر د ہ جام را
خاک برسرکن عمِ ایاّم را
7 جنوری 1718ء مطابق 15صفر 1130ھ کو صوبے دار اعظم خان کے حکم سے صوفی شاہ عنایت کا سرقلم کردیا گیا۔ وہ آخری وقت میں یہ شعر پڑھ رہے تھے۔
رہا یندی مرا از قید ہستی
جز ایک اللہ فی الدارین خیرا
صوفی شاہ عنایت شہید ہو گئے۔ بے شمار فقیر تہ تیغ کردیے گئے اورجھوک کی بستی بربا دہوگئی پھر بھی اربابِ اقتدار کے خوف وہراس کا یہ عالم تھا کہ وہ فقیروں کے نام سے لرزتے تھے چنانچہ اعظم خان نے منادی کروا دی تھی کہ اگرکسی کی زبان سے لفظ “اللہ (جو فقیروں کا اسمِ تکبیر تھا) بلند آواز سے نکلے تو اس کا سر تلوار سے قلم کردیا جائے۔48؎ اس حکم پر تبصرہ کرتے ہوئے میر علی شیر قانع لکھتے ہیں کہ ” سبحان اللہ! خدائی است کہ بہ عوض نام گرفتن خود سرمی کرد بلے عشق بازاں را ہمیں سر راہ است (سبحان اللہ کیا خدائی ہے کہ خود اس کا نام لینے پر سر قلم ہوتے تھے لیکن عاشقوں کا یہی راستہ ہے)۔
ہم نہیں کہہ سکتے کہ اعظم خان اور صوفی شاہ عنایت کے درمیان مکالمے کی داستان کسی معتبر شہادت پر مبنی ہے یا صوفی شہید کے کسی خوش مذاق مداح کی پروازِ تخیل کی تخلیق ہے مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صوفی شاہ عنایت آخر وقت تک اپنے اصولِ زیست پر قائم رہے۔ ان کے پانے استقلال میں ایک لمحے کے لیے بھی لغزش نہیں ہوئی۔
تحفتہ الکریم کے بیان کے مطابق میاں یار محمد کلہوڑا کو ” اعلیٰ خدمات کے عوض شماداتی اور چاچکاں کے علاقے سے لکری، دندا، حجام، دورنک، رجب، پسر، پاچاتہ، ٹھور اور دیہ سائیں ڈنہ کے موضعے بطور انعام عطا ہوئے۔ اس طرح وادی سندھ میں اجتماعی زراعت اور منصفانہ تقسیم دولت کا پہلا تجربہ انجام کو پہنچا۔
صوفی شاہ عنایت نے فیوڈلزم کے دور میں اجتماعی زراعت یعنی سوشلسٹ طریقہ پیداوار اور طریقہ تقسیم کو رواج دینے کی کوشش کی تھی۔ ان کا یہ اقدام لاکھ لائق تحسین و تعریف سہی اوران کی اوران کے رفقا کی قربانیاں لاکھ لائقِ احترام مگر معاشرتی ارتقا کے قانون پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ی بڑا انقلابی کیوں نہ ہو اور خدمتِ خلق کے جذبے سے کتنا ہی سرشار کیوں نہ ہو اس قانون پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ صوفی شاہ عنایت کی خواہش بڑی نیک تھی لیکن تقدیریں فقط خواہشوں سے نہیں بدلتیں۔ان کا خواب بہت خوش آئیند تھا لیکن وہ یہ خواب کم از کم دو صدی پہلے دیکھ رہے تھے جب کہ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے نہ معروضاتی خیالات موجود تھے نہ موضوعی حالات موزوں تھے۔ نہ پیداواری قوتوں نے اتنی ترقی کی تھی کہ فیوڈل ازم کا خاتمہ ناگزیر ہو جاتا اور نہ محنت کشوں میں جن کا منصب سوشلسٹ انقلاب برپا کرنا ہے اپنے تاریخی کردار کا شعور پیدا ہوا تھا ( یہ شعور آج بھی نہیں ہے) اٹھارویں صدی کا محنت کش طبقہ سندھ میں یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ نوابوں جاگیرداروں کے ہاتھوں سے سیاسی طاقت چھین کر خود برسرِ اقتدار آجانا چاہیے۔ (اہلِ جھوک نے تو کبھی ٹھٹھہ پر قبضہ کرنے کے بارے میں بھی غور نہ کیا چہ جائیکہ سندھ پر) ایسی صورت میں صوفی شاہ عنایت کے تجربے کو لازماً ناکام ہونا تھا سو ہوا البتہ بیرونی قوتوں کی چال بازیوں سے نہ کہ اندرونی خرابیوں کی وجہ سے۔
صوفی شاہ عنایت کو اپنے تجربے کی تاریخی اہمیت احساس نہ تھا اورنہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اجتماعی کھیتی کی تحریک زمینداروں کے حق یں کتنی مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ بہ ظاہر یہ تحریک کسی چھوٹے سے تالاب کے بند پانی میں ایک کنکری کی موجوں سے زیادہ نہ تھی مگر صوفی اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان لہروں میں طوفانی موجوں کی توانائی پوشیدہ ہے جو ابھر کر پوری جاگیر نظام کو خس و خشاک کی طرح بہا لے جانے کی قدرت رکھتی ہے۔ اُن میں عوام کی مسلح جدو جہد کی قیادت صلاحیت بھی نہ تھی۔ مثلاً فقیروں نے جب مشورہ دیا کہ نواب کی فوج پر راستے ہی میں بڑھ کر حملہ کردیا جائے تاکہ دشمن کو صف بندی کرنے اور جھوک کو گھیر لینے کا موقع نہ ملے تو صوفی شاہ عنایت نے پیش دستی سے انکار کردیا اور دفاعی مقابلے ہی پر اکتفا کیا۔ اس طرح لڑائی چھڑنے سے پہلے ہی لڑائی کا فیصلہ ہوگیا کیوں کہ دفاعی جنگ عموماً شکست کی تمہید ہوتی ہے۔ (یہی غلطی 1857ء) دہلی کے قلعہ بند لشکر نے بھی کی اور انگریزوں کو موقع دے دیا کہ وہ پنجاب اور دوسرے مقامات سے فوجیں اور سامانِ رسد لے جا کر دہلی پر حملہ کرسکیں۔) انھوں نے حصار بند ہو کر دشمن کو کھلی چھٹی دے دی اور اپنا ناتہ سندھ کے عوام سے توڑلیا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے کسان فقیروں کی سرفروشانہ جدو جہد کو اپنی جدو جہد نہ سمجھ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جھوک کے ففیروں کو یہ جنگ تنہا لڑنی پڑی۔ سندھ میں ان کا کوئی حامی و مدد گار نہ پیدا ہوا۔ اور فقیروں کی یہ جنگ ایک وقتی اور مقامی سانحے سے زیادہ اہمیت نہ اختیار کرسکی۔
یہ محاکمہ اپنی جگہ لیکن صوفی شاہ عنایت کا یہی تاریخی کارنامہ کیا کم ہے کہ انھوں نے اجتماعی کھیتی کا کامیاب تجربہ کرکے ثابت کردیا کہ زمیندار اور جاگیردار حائل نہ ہوں تو کھیتی باڑی زیادہ خوش اسلوبی سے ہو سکتی ہے اور رقابت و دشمنی کے بجائے یگانگت اور امدادِ باہمی کے جذبات فروغ پا تے ہیں اور یہ بھی واضح ہوگیا کہ ریاست کی قوتِ قاہرہ حق و انصاف کی حمایت کرنے کے بجائے اب تک ہمیشہ عوام کے خلاف اورنچے طبقوں کے مفاد کی حمایت کرتی رہی ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ تاریخ کی درسی کتابوں میں محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا ذکر تو بڑی شدو مد سے کیا جاتا ہے لیکن ہماری نئی نسل صوفی شاہ عنایت شہید کے نام سے بھی واقف نہیں۔
حوالہ جات و حواشی
1۔ میرعلی شیرقانع ٹھٹھوی، تحفتہ الکریم ، حصہ دوئم، کراچی سندھی ادبی بورڈ، 1959ء ص 492
2۔ ایضاً۔ ص 494۔ میرعلی شیرقانع سندھ کا مشہور مورخ، شاعر اور تذکرہ نویس 42 کتابوں کا مصنف ہے۔ اس نے اپنی دو کتابوں ۔۔۔ مقالاتِ الشعرا (1760ء) اور تحفتہ الکرام (1762) میں شاہ عنایت کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ وہ اگرچہ شاہ عنایت کے جانی دشمن کلہوڑوں کے دربار کا وقائع نگار تھا لیکن شاہ عنایت کا ذکر وہ ہمیشہ بڑے ادب و احترام سے کرتا ہے اوران کے حالات بڑی غیر جانبداری سے بیان کرتا ہے۔
3۔ Kautilya, Arthastra, Book 111, ch.9,10Al-Biruni, Kitabul Hind vol,11. Tr. Sachau p.149
4۔ تاریخ سندھ، حصہ ششم، جلد اول، صفحہ 35۔70 ، کراچی، سندھی ادبی بورڈ، 1957ء
5۔ تاریخ سندھ، حصہ اول، لاہور، مرکزی اردو بورڈ، 1971ء ص 417
6۔Herodotus, The Histories, London, Penguin. 1959, p. 215
7۔ دیکھیے پروفیسر شیخ عبدالرشید کا نگریزی مقالہ” سلاطین دہلی کے عہد میں نظام اراضی”، 1962ء
8۔ Pillip K. Hitti, History of the Arabs, London, 1958, o. 232
9۔ M.A Shaban,Islamic History, vol,11, London, 1976.p.75
10۔ ضیاء الدین برنی، تاریخ فیروز شاہی ، ص 3، بحوالہ پروفیسر شیخ عبدالرشید
11۔ M.A. Rahim, Afghan in India, Karachi, 1961,p.31
12۔ ایضاً ص 45
13۔ عبدالقادر بدایوانی مصنف منتخب التواریخ دونوں اصطلاحیں استعمال کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے کہ ہمایوں نے غزنی اور اس کے ماتحت علاقے اکبر کو بطور اقطاع عطاکیے۔ جلد اول ص 587 (انگریزی) کلکتہ 1898ء۔ البتہ جاگیر کو جاءگیر لکھتا ہے۔ مثلاً سلطانہ رضیہ نے ملک اعزالدین الیاس صوبیدار لاہور کو ملتان بھی بہ طور “جاءگیر”دے دیا۔ ص 597
14۔ Dr. Ansar Zahid Khan, History and Culture of Sind, Karachi, 1970, p. 127
15۔ ایضاً۔ ص 127
16۔ پروفیسر عرفان حبیب
17۔ خانی خاں بحوالہ پروفیسر عرفان حبیب، ص 278
18۔ یوسف میرک ، تاریخ مظہر شاہ جہانی، کراچی و حیدر آباد، سندھی ادبی بورڈ، 1962، ص 190
19۔ R.C. Manjumdar: Advanced History of India, London, 1961, p. 556
20۔ تاریخ مظہر شاہ جہانی، ص 53
21۔ ڈاکٹر انصار زاہد خان، ص 127
22۔ ایضاً۔ ص 129
23۔ منقول از پروفیسر عرفان حبیب، ص 153
24۔ منتخب التواریخ، جلد دوئم (انگریزی)، کلکتہ، 1888ء ص 47
25۔ ایضا۔ ص 51
26۔ تاریخ مظہر شاہ جہانی، ص 191
27۔ ایضا۔ ص 131
28۔ ایضاً۔ ص 153
29۔ایضاً۔ ص 54
30۔ رقعاتِ عالمگیری، ص 40
31۔ سرجاود ناتھ سرکار William Irvine, Later Mughals, vol. 11 London.P. 311 .
32۔ تحفتہ الکرام ص 309۔310
33۔ شیخ محمد اکرم، رودِ کوثر، لاہور، ص 30، سید شمس الدین مسطفائی، مہدوی تحریک، شہداد پور، سندھ، ص 63
Dr. S.A.A. Razvi, Mahdavi Movement, Karachi, 1958, p.12
34 ۔ تحفتہ الکرام، ص 170
35۔ ایضاً۔ ص 495
36۔ میرعلی شیر قانع، مقالات الشعرا (فارسی) ، ص 30
37۔ایضاً۔ ص 495
38۔ مولانا غلام رسول مہر، تاریخ سندھ، ص 280
39۔ مقالات الشعرا، ص 31
40۔ ایضاً۔ ص 31
41۔ میاں نور محمد خدایار خان، منشور الوصیت، حیدر آباد، سندھی ادبی بورڈ، 1964۔ اس خندق کے بعض حصے اب تک موجود ہیں اور ان میں پانی بھرا ہے۔
42۔ یہ تمام اقتباسات منشورالوصیت ص 33 تا 45 سے ہیں۔
43۔ ایضاً۔ ص 39
44۔ تحفتہ الکرام، ص 311
45۔ ایضاً
46۔ مقالات الشعرا (فارسی)، ص 33
47۔ ایضاً۔ ص 34۔35
48۔ ایضاً۔ ص 35۔36
باب پنجم: پہلا باغی، پہلا سیاسی قیدی
” پرومی تھیوس” کا المیہ ڈرامہ ایس کائی لس کا شاہکار ہے۔ آج تک کسی فن کار نے علم اور توہم پرستی ، روشن خیالی اور تاریک بینی، فطانت اور اذعان کے درمیان پیکار کی اتنی عمدہ نقاشی نہیں کہ اورنہ کوئی شخص ؑلامت اور ابلاغ کو اتنی بلندی پر لے جا سکا۔
یروشلم کے یہودی علما نے توریت کی ترتیب کے دوران جس وقت کتابِ پیدائش میں 1؎ شیطان کی بغاوت کی داستان رقم کی تو ان کو غالباً خبر نہ تھی کہ یونان کا کسان شاعر ہیسیڈ (750 ق۔م) تقریباً دو ڈھائی سوبرس قبال ایک اورباغی کا قصہ نظم کرچکا تھا۔ اس باغی کا نام پرومی تھیوس 2؎ Prometheus تھا جس نے قدیم یونانیوں کے ربِ اعلیٰ زیوس کی حکم عدولی کی تھی اور سزا پائی تھی مگر شیطان کی سامی الاصل داستان اور پرومی تھیوس کی آریا الاصل داستان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ روایت کے مطابق شیطان بنی نوعِ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس کاکام انسانوں کو بہکانا اور گمراہ کرنا ہے۔ وہ بدی کی علامت ہے۔ جب کہ پرومی تھیوس بنی نوعِ انسان کا دوست اور محسن ہے۔ زیوس کی نظروں میں اس کا قصور ہی یہ ہے کہ اس نے انسان کو مختلف علوم و فنون سکھائے حتیٰ کہ آگ کے استعمال سے بھی آگاہ کردیا جو زیوس کا سب سے خفیہ راز تھا۔
آسمانی طاقتوں کے خلاف بغاوت کا تصور چوں کہ ارضی طاقتوں کے خلاف بغاوت ہی سے وابستہ ہے لہٰذا بغاوت کی سماجی نوعیت پر غورکرنا بے محل نہ ہوگا۔ بغاوت نام ہے حکومتِ وقت یا مروجہ قوانین و ضوابط یا مروجہ عقاید و اقدار سے اعلانیہ انحراف کا۔ بغاوت فکرو عمل کا منفی انداز ہے جو حال کے جبر سے نشو و نما پاتا ہے۔ باغی کو اس سے سروکار نہیں ہوتاکہ جس تخریب کے وہ درپے ہے اس کے ملبے پر کوئی بہتر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ حال کی سخت گیریاں اُس پر اتنی حاوی ہوتی ہیں کہ وہ مستقبل کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا بلکہ عاجز آکر چیخ اُٹھتا ہے کہ
جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روٹی
اس کھیت کے ہر خوشئہ گندم کو جلا دو
(اقبال)
یا مخدوم کا یہ نعرہ کہ
پھونک دو کن کو اگر کن کا تماشا ہے یہی
زندگی چھین لو دنیا سے جو دنیا ہے یہی
یہ بھی ضروری نہیں کہ بغاوت سماجی رشتوں میں تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ مثلا کسانوں، غلاموں اور دست کارو ں کی پہلی بغاوت جس کی دستاویزی شہادت موجو د ہے 18 ویں صدی قبلِ مسیح میں مصر میں ہوئی۔
اس بغاوت سے پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ ” فرعون کو تخت سے دست بردار ہونا پڑا اور امرا اور رؤسا اپنی حویلیاں چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پرانے فرعونوں کے مقبروں میں جو دولت دفن تھی لوٹ لی گئی۔ غلوں کے شاہی گوداموں اور خزانوں پر باغیوں نے قبضہ کرلیا اور جو مال و متاع ہاتھ لگا اس کو آپس میں بانٹ لیا اور خراج اور محاصل کے تمام سرکاری کاغذات جلا دیے گے۔ ایک قدیم وقائع نویس کے بیان کے مطابق زمین کمھار کے چاک کی ماند گھوم گئی۔ کیوں کہ غریب پانے دولت مند آقاؤں کی حویلیوں میں جا بسے تھے اوران کے لباس پہن کر ان کو کام کرنے پر مجبور کرنے لگے تھے”۔3؎
مگرجس طرح تالاب کے بند پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں اٹھتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں اسی طرح مصریوں کی بغاوت بھی چند روزہ ثابت ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ محنت کش عوام تشدد اور استحصال کی ناقابلِ برداشت صعوبتوں سے تنگ آکر ریاستی نظام کو درہم برہم تو کرسکتے تھے لیکن اس وقت تک پیداواری قوتوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ اقتدار پر قبضہ کر کے فراعنہ کے غلامی کے نظام کی جگہ سرمایہ داری یا سوشلسٹ نظام رائج کیا جاتا جیسا کہ انقلاب فرانس یا انقلابِ روس کے بعد ہوا۔ لہٰذا مصر میں بہت جلد فرعونی اقتدار بحال ہوگیا۔ ممکن ہے کہ بغاوت کے باعث غلاموں، دہقانوں اور دست کاروں کو کچھ مراعات مل گئی ہوں لیکن باغی عناصر ملک کے سماجی اورپیداواری رشتوں میں کوئی بنیادی تبدیلی نہ لا سکتے تھے اور نہ لائے۔
سماجی اور پیداواری رشتوں میں بنیادی تبدیلیاں لانے کا نام انقلاب ہے۔ معاشرتی ارتقا کی یہ وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر فکرو عمل کا منفی انداز مثبت صورت اختیار کرلیتا ہے اور حال سے انکار ایک بہتر مستقبل کا مژدہ سناتا ہے۔ انقلاب تخریب بھی ہے تعمیر بھی۔ چنانچہ ہر انقلابی کے لیے باغی ہونا شرط ہے لیکن ہر باغی انقلابی نہیں ہوتا اور نہ ہر بغاوت انقلاب کی نقیب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے شیطان باغی تو ہے مگر انقلابی نہیں جب کہ پرومی تھیوس باغی بھی اور عظیم انقلابی بھی جس نے داستان کے مطابق انسان کو حیوانوں کی صف سے نکال کر اشیا کا ایک باشعور خالق بنادیا۔
بغاوت کا تصور طبقاتی معاشرے کا منطقی ردّعمل ہے۔ باغیانہ خیالات غیر طبقاتی قبیلہ داری معاشرے کے ذہن میں ابھرہی نہیں سکتے تھے کیوں کہ قبیلہ داری معاشرہ ایک وحدت ہوتا تھا اقتصادی اعتبار سے بھی اور اعتقادی اعتبار سے بھی۔ اُس میں حاکم و محکوم، زبردست اور زیردست، امیر اور غریب کے مابین فرق و امتیاز کی قطعاً گنجائش نہ تھی۔ قبیلے کے قاعدے ضابطے قبیلے کے اپنے تجربوں اور زندگی کے تقاضوں سے اخذ کیے جاتے تھے اور قبیلے کی اجتماعی مرضی کی نمائندگی کرتے تھے۔ کوئی بیرونی قوت ان ضابطوں کو نہ وضع کرتی تھی اور نہ اوپر سے نافذ کرتی تھی۔ چنانچہ انیگلز کے بقول قبیل داری نظام میں۔
” معاشرے کے حالات زیست میں ایک طرح کی مساوات پائی جاتی تھی اور خاندانوں کے سر براہوں کے درمیان سماجی مرتبے کی برابری ملتی تھی۔ کم سے کم سماجی طبقے ناپید تھے۔ یہ صورت بعد میں مہذب قوموں کی قدیم زرعی بستیوں میں بھی باقی رہا۔ ایسی ہر ایک جمعیت میں ابتدا ہی سے بعض ایسے مشترکہ مفادات موجود ہوتے تھے جن کے تحفظ کی ذمہ داری افراد کے سپرد ہوتی تھی البتہ پوری جمعیت کی نگرانی میں مثلاً آپس کے جھگڑوں کا چکانا، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کی حرکتوں کی روک تھام، پانی کی فراہمی کی دیکھ بھال بالخصوص گرم ملکوں میں بالکل ابتدائی دور میں مذہبی رسوم کی ادائیگی”۔ 4؎
قبیلے کے اندر اختیاراور اطاعت کا رشتہ ضرور موجود تھا لیکن صاحبِ اختیار افراد کے پاس قبیلے کی اخلاقی قدروں کے علاوہ کوئی قوت قاہرہ نہ تھی۔ نہ پولیس، نہ فوج، نہ قید خانہ۔ قوتِ قاہرہ کے اس فقدان کے باوجود قبیلے کے لوگ بقول اینگلز اپنے صاحبِ اختیار بزرگوں کی صدق دل سے عزت کرتے تھے۔ ” جو اختیار ان بزرگوں کو حاصل تھا اور جو محبت ان کے قبیلہ والوں سے ملتی تھی وہ بعد میں بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوئی”۔
بغاوت کے تصور کا پیدا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ معاشرے میں وہ اگلی سی وحدتِ فکر و عمل باقی نہیں رہی بلکہ اب وہ طبقوں میں بٹ گیا ہے جن کے مفاد آپس میں ٹکراتے تھے۔ طبقوں میں تقسیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ پرانے حالاتِ زیست بدل گئے ہیں۔ دولت اور دولت آفرینی کے ذرائع کسی مخصوص گروہ کی ذاتی ملکیت بن گئے ہیں اور وہ دولت پیدا کرنے والے غلام، کاشت کار اور ہنر مندوں کی قوتِ محنت کا استحصال کرتا ہے۔ ریاستیں اسی نظام جبرو استحصال کے تحفظ کی خاطر وجود میں آئیں اور تب معاشرے میں بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیاسی اور فکری بغاوتوں کا۔ ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے ہم کو کسی ارضی یا سماجی بغاوتوں کا نشان نہیں ملتا۔
یہ درست ہے کہ انسان نے مظاہرِ قدرت کی پرستش ریاست سے بہت پہلے شروع کردی تھی۔ جو قوتیں اس کو آرام یا فائدہ پہنچاتیں ان سے وہ محبت کرتا تھا مثلاً مادر گیتی جو سب کی پالن ہار سمجھی جاتی تھی اور سورج، چاند ، آگ، پانی وغیرہ۔ اس کے برعکس جن قوتوں سے اس کو ضرر پہنچتا تھا ان سے وہ ڈرتا تھا اور ان کی رضا جوئی کی کوشش کرتا تھا۔ مثلاً سیلاب، طوفان، آندھی، بیماری، موت وغیرہ۔ مفید قوتیں “خیر” تھیں، مضر قوتیں “شر” لیکن ان مظاہر قدرت کے مربوط دیو مالائی نظام کی باقاعدہ تشکیل ملوکیت کے دور ہی میں ہوئی۔ چنانچہ ارباب النوع کو ان تمام اوصاف سے آراستہ کیا گیا جو بادشاہ اور اس کے درباریوں میں نظر آئے۔ رب الارباب کائنات کا مالک و فرماں روا ٹھہرا۔ اور بقیہ ارباب النوع کو اس کے وزرا، مصاحبین اور اولاد کا مرتبہ دیا گیا۔ پوری کائنات کے حاکم اعلیٰ ہونے کے ناتے رب الارباب کے اختیارات بھی ارضی بادشاہوں سے فزوں تر قرار پائے۔ مصر میں یہ مرتبہ آمون رع کو ملا، بابل میں مردوک کو، ایران میں یزداں کو، ہندوستان میں برھماکو اور یونان میں زیوس کو۔ ان ملکوں بالخصوص یونان کی دیو مالا پڑھو تو یوں لگتا ہے کہ گویا قرونِ وسطیٰ کی کسی بادشاہت کا حال پڑھ رہے ہیں۔ وہی اقتدار کی جنگیں، وہی درباری سازشیں، وہی عیاشیاں اور عشق و عاشقی کے مشعلے اور وہی رنگ رلیاں جو شاہی محلوں کا معمول تھیں کوہِ اولمپس کے خداؤں کے ذوق و شوق کی تسکین کے سامان بھی فراہم کرتی تھیں۔
جس طرح زمین کے بادشاہ تاج و تخت کی خاطر اپنے باپ بھائی اور اولاد سے جنگ کرنے اور ان کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے اسی طرح زیوس بے بھی عالم کی فرماں روائی اپنے باپ کرونس (زمانہ= Cronus ) سے لڑکر حاصل کی تھی۔ کہتے ہیں کہ زیوس کے دادا یورانس (عرش = Uranus ) کے نطفے اور مادر گیتی کے بطن سے سات بیٹے پیدا ہوئے جن کا مشترکہ نام طیطان (Titan ) تھا۔ پھر کچھ اور بیٹے پیدا ہوئے جو سائیکلوپ کہلائے سائیکلوپ بڑے سرکش نکلے لہٰذا عرش نے ناراض ہو کر ان کو پاتال میں پھینک دیا۔ مادرِ گیتی کو عرش کا یہ ظالمانہ برتاؤ بہت برا لگا۔ اس نے طیطانوں کو بدلہ لینے پر آمادہ کیا چنانچہ سب سے چھوٹے بیٹے کرونس نے ایک تیز ہنسئے سے عرش کا عضو تناسل کاٹ ڈالا اور باپ کی جگہ خود کائنات کا مالک بن گیا (ایشیائے کوچک کی حتی قوم کی دیو مالا میں کرونس کا نام کماربی اور آسمان کے دیوتا کا نام انو ہے۔ مورخین کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ طیطان دراصل یونان کے اصلی باشندے تھے جنھوں نے ان آریائی قوموں کو شکست دی تھی جو ایشیائے کوچک سے ترکِ وطن کرکے یونان میں آبسے تھے) کرونس نے مالکِ کائنات ہو کر اپنی بہن رِھیا Rhea سے شادی کرلی لیکن عرش نے مرتے وقت پیشن گوئی کی تھی کہ کرونس کا بیٹا بھی اس کو تخت سے اتارے گا۔ لہٰذا رھیا کے جو بیٹا ہوتا کرونس اس کو نگل جاتا مگر زیوس کی ولادت کے وقت رھیا ایک غار میں چھپ گئی۔ زیوس پیدا ہوا تو رھیا نے اس کو ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیا اور جب کرونس نومولود کو کھانے آیا تو رھیا نے پتھر کے ایک موسل کو کپڑا میں لپیٹ کراس کے گلے میں اتار دیا۔ اور کرونس سمجھا وہ نولود ہے۔
زیوس کی پرورش ایک گڈریے نے کی۔ جب وہ جوان ہوا تو اپنی ماں رھیا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے ماں مجھ کو کرونس کا پیالہ بردار بنا دے تاکہ میں اس سے بھائیوں کا انتقام لے سکوں۔ رھیا نے اس کو سرسوں اور نمک دیا اور کہا کہ جا کر کرونس کے شہد کے پیالے میں ملادے۔ کرونس نے شہد پیا تو اس کو قے ہوئی اور اس نے زیوس کے بھائیوں کو اُگل دیا جو زندہ تھے۔ تب زیوس نے بھائیوں کی مدد سے کرونس کے خلاف اعلانِ جنگ کردیا۔ یہ لڑائی دس سال تک جاری رہی۔ آخر زیوس نے اپنے باپ کو بجلی گرا کر ہلاک کردیا اور کوہِ لمپس کا فرماں روا بن گیا۔
اس جنگ میں پرومی تھیوس کے طیطان بھائیوں نے کرونس کا ساتھ دیا تھا لیکن ” دور اندیش” پرومی تھیوس نے زیوس کو ترجیح دی تھی۔ لہٰذا زیوس نے پرومی تھیوس کو بطور انعام دیوتاؤں کا درجہ دے دیا تھا۔
زیوس بڑا عاشق مزاج تھا۔ اس نے میتس نامی ایک طیطانی دوشیزہ سے زبردستی صحبت کی تب مادر گیتی نے غیب سے ندادی کہ میتس کے لڑکی ہوگی لیکن زیوس نے اگر دوبارہ یہی حرکت کی تو میتس بیٹا جنے گی اور اس کے ہاتھوں زیوس کا وہی انجام ہوگا جو کرونس کے ہاتھوں یورانس کا اور زیوس کے ہاتھوں کرونس کا ہوا تھا۔ زیوس نے یہ سنا تو میتس کو پیارکے بہانے پاس بلایا اور زندہ نگل گیا مگر تھوڑی دیر میں اس کا سر درد پھٹنے لگا۔ اس وقت پرومی تھیوس نے زیوس کے سرمیں بڑا سا سوراخ کیا جس سے درد جاتا رہا اور سوراخ سے عقل و دانش کی دیوی اے تھی نابرآمد ہوئی۔ زیوس نے پرومی تھیوس سے کہا میں تیرا احسان کبھی نہ بھولوں گا۔
اے تھی نانے پرومی تھیوس کو گھر بنانے اور کھیتی باڑی کرنے کے ہنر سکھائے اور علم نجوم، معدنیات، طب ، ریاضی اورجہازرانی کی تعلیم بھی دی۔ پرومی تھیوس نے انسانوں کو ان تمام علوم و فنون سے آگاہ کردیا لیکن زیوس کو پرومی تھیوس کا یہ طرزِ عمل پسند نہیں آیا لہٰذا اس نے نسل انسانی کو یکسر نیست و نابود کرنے کا تہیہ کرلیا۔ پرومی تھیوس کو خبر ہوئی تو اس نے جاکر زیوس کی منت سماجت کی اور زیوس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ تب پرومی تھیوس نے ایک مشعل بنائی، اس کو سورج سے روشن کیا اورچپکے سے انسانوں کو دے آیا۔ اس طرح وہ آگ کے استعمال سے واقف ہوگئے۔
اس خفیہ راز کا افشاں ہونا تھا کہ اولمپس میں تہلکہ مچ گیا۔ زیوس کو پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہوگیا اور حکم دیا کہ پرومی تھیوس کو گرفتار کرکے کوہِ قاف کی سب سے اونچی چوٹی سے باندھ دیا جائے اور ایک گدھ مقرر کردیا جس کا کام یہ تھا کہ دن بھر پرومی تھیوس کا کلیجہ نوچ نوچ کرکھاتا رہے اور یہ شرط بھی لگا دی گئی کہ جب تک پرومی تھیوس اپنے جرم کا اعتراف نہ کرے اور معافی نہ مانگے یہ اذیت ناک سزا بھگتتا رہے۔ پرومی تھیوس نے معافی مانگنے سے انکارکردیا۔
اس طرح وہ تیس ہزار سال تک قیدو بند کی اذیتوں میں مبتلا رہا۔ ایک روز اتفاقاً مہم جو ہرا کلیز ہفت خواں کا راستہ تلاش کرتا وہاں وارد ہوا۔ اس کو پرومی تھیوس کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ اس نے گدھ کو تیر مار کر ہلاک کردیا۔ پرومی تھیوس کی زنجیریں، بیڑیاں کاٹ ڈالیں اور زیوس کے پاس جا کر معافی کا طالب ہوا۔ زیوس نے ہرا کلیز کی التجا قبول کرلی۔ اس طرح یہ داستان اقتدار اورسرکشی کے مابین سمجھوتے پر تمام ہوگئی۔
پرومی تھیوس کے قصے میں وقتاً فوقتاً ترمیمیں ہوتی رہی ہیں مگر وہ ہردور میں بغاوت کی علامت رہا ہے۔ البتہ بعض مشاہیرے پرومی تھیوس کی تعریف کی ہے اور بعضوں نے مذمت۔ مثلاً افلاطون، بیکن، گوئٹے، بائرن، شیلی، والٹیر، کارل مارکس اور پکا سونے اس کی انسان دوستی، پامردی اور اخلاقی جرات کو خوب سراہا ہے۔ یونانی ادب کے ایک مغربی نقاد کی نظر میں تو پرومی تھیوس ” محنت کشوں کا پہلا پیر تھا”۔ 5؎
اس کے برعکس اقتدار پرست حلقوں نے پرومی تھیوس کو برا بھلا کہا ہے اور زیوس کے طرزِ عمل کی حمایت کی ہے۔ مثلا ہیسیڈ اوراٹلی کے فاشسٹ شاعر گیبریل اننزیو نے۔ ہیسیڈ کسان ہونے کے باوجود ایتھنز کے رؤسا کا طرف دار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پرومی تھیوس کی خود سری ہی ہماری مصیبتوں کا سبب بنی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ ہنسی خوشی زندگی بسرکرتے تھے۔ کسی کو محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی بلکہ زمین بلا جوتے بوئے از خود اناج اگلتی رہتی تھی لیکن یہ عہدِ فرصت و شادمانی پرومی تھیوس کی ضد اور شرارت سے ختم ہوگیا۔
جس فن کار نے پرومی تھیوس کی داستان کو بقائے دوام بخشی وہ ایتھنز کا مشہور ڈرامہ نویس ایس کائی لس Aeschylus تھا۔ وہ 525 قبل مسیح میں ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب داریوش اعظم ایشیائے کوچک کی تسخیر کے بعد یونان پر حملے کررہا تھا۔ چنانچہ ایس کائی لس بھی میرا تھن (490 ق۔ م) اور سلامیز(480ق۔م) کی تاریخی جنگوں میں شریک ہوکر وطن کی حفاظت کے لیے لڑا اوراپنی دلیری کے سبب مشہور ہوا۔ اس کو ڈرامہ نویسی میں اول انعام چالیس سال کی عمر میں ملا (ایتھنز میں ہرسال موسمِ بہار کے عظیم الشان تیوہار کے موقعے پر کئی دن تک نو تصنیف ڈرامے اسٹیج پر کھیلے جاتے تھے۔تھیٹر میں داخلہ مفت تھا۔ سقراط بھی ان ڈراموں کو بڑے شوق سے دیکھتا تھا) کہتے ہیں کہ ایس کائی لس نے نوے ڈرامے لکھے مگراب فقط سات باقی ہیں۔ اس کو تیرہ بار اول انعام ملا۔ 458 ق۔م میں وہ سسلی کے حاکم ہیرون کی دعوت پر سیراکوز گیا اوردو سال بعد وہیں فوت ہوگیا۔
ایس کائی لس نے پرومی تھیوس کے قصے کو تین ڈراموں میں پھیلایا ہے۔ 1۔ پرومی تھیوس آتش رسا Prometheus, Fire Bringer 2۔ پرومی تھیوس زنجیر بستہ Prometheus Bound 3۔ پرومی تھیوس زنجیرکشادہ Unbound ۔ لیکن ان میں فقط زنجیر بستہ زمانے کی دست برد سے بچا۔ بقیہ دونوں ڈرامے تلف ہوگئے۔ دس پانچ مصرے اگرکہیں ملتے ہیں تو ان سے نفسِ مضمون کا اندازہ نہیں ہوتا۔
“زنجیرِ بستہ” کی جائے وقوع سمندر کے کنارے ایک اونچی چٹان ہے۔ زیوس کے کارندے ” طاقت” اور” تشدد” پرومی تھیوس کو جو زنجیروں سے بندھا ہے گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں اور لوہار دیوتا سے جو آگ کا محافظ بھی تھا کہتے ہیں کہ:
” آؤ اب اس باغی پرومی تھیوس کو ہمیشہ کے لیے چٹان سے باندھ دیں۔ اس نے آگ کی گلنار تابانی کو چھپے چوری انسانوں کے حوالے کردیا۔ دیوتاؤں کے نزدیک یہ ناقابلِ معافی جرم ہے اوراب پرومی تھیوس کو اس جرم کی سزا بھگتنی چاہیے یہاں تک کہ وہ زیوس کی خدائی کو تسلیم کرلے اور نسل انسانی کی اعانت سےباز آجائے۔”
مگرلوہارکوپرومی تھیوس سے ہمدردی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ شخص آخرہم ہی میں سے ہے پھرکس دل سے اس کے ہاتھوں ، پیروں اور پسلیوں میں کیلیں ٹھونکوں لیکن حکمِ حاکم مرگِ مفاجات۔ وہ پرومی تھیوس سے مخاطب ہوکر کہتا ہے کہ
کوہ پیکر خیالات کے دیوتا،
اب میں تم کو بڑے دکھے دل سے باندھوں گا
کانسے کی زنجیروں سے جو ہلائے نہ ہلیں گی
اس سنسان چوٹی سے
جہاں تم کوئی آواز نہ سن سکو گے
اورنہ تم کو کس فردِ بشر کی شکل دکھائی دے گی۔
تمھارا بدن سورج کی شعلہ فگن شعاعوں سے جھلس کر
اپنی تازگی اورشادابی کھودے گا۔
تم رات کے آنے پر خوش ہوگے
جو دن کو اپنے سیاہ لبادے میں چھپا لیتی ہے۔
اورجب بھور ہوتے ہی سورج کی گرمی سے
پالے کی تہیں پگھل جائیں گی
توتم پھر خوش ہوگے
مگرہرگزرتی ساعت تمھارے جسم پر
درد کے تازیانے لگائے گی
نسلِ انسانی پر تمھاری شفقت و عنایت نے تم کو یہ دن دکھائے ہیں۔
تم وہ دیوتا ہو جو دیوتاؤں کے عتاب کے آگے نہیں جھکا۔
لیکن تم اپنی حد سے آگے بڑھ گئے
اورفانی انسان کو مراعات دے دیں۔
اب اس کی پاداش میں تم اس چٹان کا پہرہ دو،
سیدھے کھڑے رہ کر، بے خواب آنکھوں سے، آرام سے محروم۔
تمھاری چیخیں اور کراہیں سب بے سود ہوں گی
کیوں کہ زیوس کا دل پسیجنے والا نہیں۔
نیانیا اقتدار بڑا شقی ہوتا ہے
” طاقت ” اور ” تشدد” پرومی تھیوس پر خوب خوب طنز کرتے ہیں مگروہ خاموش کھڑا رہتا ہے البتہ جب وہ پرومی تھیوس کو چٹان سے باندھ کر چلے جاتے ہیں تو پرومی تھیوس اپنے ہمدرد دیوتاؤں کو پکارتا ہے۔
اے مقدس آسمان، اے تیز ہواؤ اوراُبلتے چشمو!
اے سمندر کی ہنستی ہوئی ان گنت موجو!
اے زمین! زندگی کی ماں!
تم سب گواہ رہنا اور سورج بھی جس کی آنکھوں سے کچھ پوشیدہ نہیں
کہ دیوتاؤں نے ایک دیوتا سے کیا سلوک کیا۔
دیکھو، دیوتاؤں کے نئے آقا نے میرے لیے
کیسا قید خانہ بنایا ہے!
نسلِ انسانی کو تحفے دینے کی پاداش میں
مجھ کو یہ اذیت ناک سزائیں مل رہی ہیں۔
میں وہ ہوں جس نے آگ کی جگہ ڈھونڈ نکالی
اورآگ انسان کے لیے تمام فنون و ہنر کی معلم ثابت ہوئی۔
ایک عظیم الشان ذریعہ
اتنے میں جل پریاں کورس کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں۔ وہ پرومی تھیوس سے اظہار ِ ہمدردی کرتےہوئے کہتی ہیں کہ :
اولمپس کی عنانِ اقتدار اب ایک نئے آقا کے ہاتھ میں ہے زیوس کے ظالمانہ قوانین جن سے وہ جبر یہ حکومت کرتا ہے
بالکل انوکھے ہیں۔
وہ ماضی کی درخشاں روایتوں کو ملیا میٹ کررہا ہے۔
سب دیوتا تمھارے دکھ درد میں شریک ہیں،
زیوس کے سوا۔
انتقام لیے بغیر اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں
یا کوئی ایسی سازش جو اس ناقابلِ تسخیر سلطنت کو
اس کے ہاتھ سے چھین لے۔
پرومی تھیوس ۔۔۔۔۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ
ہرچند کہ میں آج ذلیل و خوار ہوں
اورمیرے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھے ہیں
لیکن خداؤں کے اس خدا کو
ایک دن میری حاجت ہوگی
یہ جاننے کے لیے کون اس کے اقتدار اور شان و شوکت کے درپے ہے
مگراس کی چکنی چپڑی باتوں کا جادو مجھ پر نہیں چلے گا
اورنہ میں اس کی دھمکیوں سے ڈرنے والا ہوں
کورس۔۔۔۔ بے شک تم نڈر ہو اور
تمھاری روح اذیتوں کے باوجود بنا نہیں جانتی
لیکن تم اس مصیبت سے کیسے نجات پاؤ گے
کیوں کہ کرونس کا بیٹا مد مزاجی میں یکتا ہے
اورکوئی چیز اس کے دل کو نرمانے والی نہیں۔
پرومی تھیوس ۔۔۔ میں جانتا ہوں کہ زیوس بڑا کٹھور ہے
اورقانون کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے
مگر میری باتیں جب سچ نکلیں گی
اوراس کا راج سنگھاسن ڈولنے لگا
تب اس کا مزاج درست ہو جائے گا
اوروہ مجھ سے دوستی کی درخواست کرے گا۔
کورس۔۔۔۔ اچھا یہ بتاؤ زیوس نے تم کو کس جرم میں پکڑا۔
اورایسی بے شرمی اور سنگ دلی کا سلوک تمھارے کیوں کہ۔
پرومی تھیوس کرونس اور زیوس کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ماں، مادرِ گیتی نے مجھ کو آگاہ کردیا تھا کہ اس لڑائی میں فتح ہوشیاری اور عقل مندی کی ہوگی نہ کہ جسمانی طاقت کی چنانچہ میں نے قوی ہیککل اور دیو پیکر طیطانوں کو جو عقل و فہم سے بالکل عاری ہیں بہتیرا سمجھایا مگران کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ انھوں نے میری بات نہ مانی لہٰذا میں زیوس کے لشکرمیں شامل ہوگیا اورمیری بتائی ہوئی تدبیروں ہی سے زیوس جیتا” اب میری رفاقت کا بدلہ مجھ کو یہ مل رہا ہے۔”
دوستوں کو شک و شبہے کی نظرسے دیکھنا،
یہ بیماری ہر ظالم سفاک کو شاید ورثے میں ملتی ہے،
زیوس خفگی کا سبب بیان کرتے ہوئے پرومی تھیوس کہتا ہے:
تم پوچھتی ہو ، زیوس مجھ کو کیوں دُکھ دے رہا ہے
تو سنو!
باپ کے تخت پر بیٹھتے ہی اس نے دیوتاؤں کو مختلف منصب سونپ دیے لیکن خاکی انسان کا بالکل خیال نہ کیا
بلکہ ان کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنانے لگا
مگرمیرے سوا کسی کو اس منصوبے کی مخالفت کی جرات نہ ہوئی۔
میں نے ہمت دکھائی اور فانی انسان پر ترس کھایا۔
پرمیں رحم کا مستحق نہ تھا
لہٰذا مجھ کو یہ سبق پڑھایا جارہا ہے۔
کورس۔۔۔ شاید تم نے کوئی اس سے بھی بڑا جرم کیاہو؟
پرومی تھیوس۔۔۔۔ ہاں، میں نے انسانوں کو موت کی پیش بینی کرنے سے روک دیا۔
کورس۔۔۔۔ تم نے ان کے دُکھوں کی کیا دوا تجویز کی؟
پرومی تھیوس۔۔۔۔ میں نے ان کے دلوں میں امید کے سدابہار پھول کھلا دیے۔
کورس۔۔۔۔ یہ تحفہ تو ان کے لیے بری نعمت ثابت ہوا ہوگا؟
پرومی تھیوس۔۔۔۔ میں نے ان کو اس سے بھی بڑی چیز عطا کی۔ میں نے آگ ان کے حوالے کردی۔
کورس۔۔۔۔ انسانوں کو! جن کی زندگی چند روزہ ہوتی ہے۔ گویا وہ اب آگ کی گرم روشنی کے مالک ہیں۔
پرومی تھیوس۔۔ ۔ ۔ ہاں اوراس کی مدد سے اب وہ ان گنت ہنروں کے ماہر ہو جائیں گے۔
اسی اثنا میں سمندر کا دیوتا نمودار ہوتا ہے اور پرومی تھیوس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بتاؤں میں تمھاری کیا مدد کرسکتا ہوں۔ وہ پرومی تھیوس کو زیوس سے سمجھوتہ کرلینے کا مشورہ دیتا ہے۔
سمندر دیوتا۔۔۔۔ دیکھو پرومی تھیوس، ایک نیا بادشاہ ہمارا حاکم بنا ہے لہٰذا اپنی حقیقت پہچانو اور وقت کے ساتھ چلنا سیکھو۔ اگرتم زیوس کو اسی طرح جلی کٹی سناتے رہے تو اس کو بھی خبر ہو جائے گی اور تمھاری تکلیفیں اور بڑھ جائیں گی۔
پرومی تھیوس سمندر کے دیوتا کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دوسروں پر بھی عتاب آئے لہٰذا تم بیچ میں نہ پڑو۔ سمندر دیوتا کے رخصت ہونے پر کورس اور پرومی تھیوس کے درمیان مکالمہ پھر شروع ہوجاتا ہے۔ یہ مکالمہ فنّی اعتبار سے ایس کائی لس کا شاہ کار ہی نہیں بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ یونانیوں کا ذہن اب سے ڈھائی ہزار برس پیش تر بھی تہذیبِ انسانی کے ارتقائی تصور سے آشنا تھا۔ افلاطون نے ” مکالماتِ فرو تا غورث” اور ” قوانین” میں انسانی معاشرے کے ارتقا کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ پورے ایک سو سال بعد کی تصنیف ہے۔
پرومی تھیوس انسانوں میں اپنے احسانات گنواتے ہوئے کہتا ہے کہ:
ابتدا میں ان کے پاس دماغ نہ تھا۔
میں نے ان کو عقل و فہم عطا کی۔
مگرجوکچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے انسانوں کی تحقیر مقصود نہیں
بلکہ یہ بتانے کےلیے کہ میں نے ان کو جو تحفہ بھی دیا
نیک نیتی سے دیا۔
ان کے آنکھیں تھیں لیکن بصیرت سے محروم،
وہ آوازیں سنتے تھے مگر ان کے معنی و مفہوم سے بے خبرتھے۔
وہ زندگی کا سفریوں طے کررہے تھے۔
گویا بھیڑیں ہیں جو خواب دیکھ رہی ہوں۔ بے مقصد اور آشفتہ سر
اینٹوں کے بنے اور سورج کی حرارت سے گرم گھروں کا ان کو کوئی تصور نہ تھا۔
نہ وہ لکڑی کا سامان بنا سکتے تھے۔
وہ چیونٹیوں کی طرح بلوں میں رہتے تھے
یا اندھیرے غاروں میں۔
ان کو سردی کی یا پھولوں سے مہکتی بہار یا میووں سے لدی گرمی
کی تمیز نہ تھی۔
ان کا ہرکام ادراک و آگہی سے خالی تھا۔
یہاں تک کہ میں نمودار ہوا۔
میں نے ان کو ستاروں کی حرکت کا حساب سکھایا،
جو مشکل فن تھا۔
پھر علم ریاضی جو بنیادی علم ہے، میں نے ان کے لیے وضع کیا
اورلفظوں کو لکھنے کا ہنر
جس کے ذریعے سب کچھ محفوظ کرلیا جاتا ہے
اورجو بے شمار فنون کی تخلیق کا سرچشمہ ہے۔
میں نے جانوروں کو جوا پنہا کر انسان کا غلام بنایا
کہ وہ بھاری سے بھاری بوجھ اٹھائیں
اورگھوڑوں کو رتھ میں ہانکیں
اوروہ اس کی لگام کے اشارے پر دوڑیں۔
کسی نے مجھ سے پہلے ملاحوں کی گاڑی نہیں ایجاد کی تھی،
وہ سواری جو کپڑے کے پر لگا کر سمندروں میں سیر کرتی پھرتی ہے۔
میں نے انسان کو یہ سارے آلات و اوزار فراہم کیے
مگرآج مجھ کو اس اذیت سے نجات کا کوئی گرنہیں آتا۔
کورس۔۔۔۔ تم وہ طبیب ہو جو اپنا علاج نہ کرسکا۔
پرومی تھیوس۔۔۔۔۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی:
سب سے اہم یہ کہ آدمی بیمار ہوتا تھا تو اپنا علاج نہ کرسکتا تھا
اس کو کوئی عرق، معجون یا مرہم میسر نہ تھا۔
دوانہ ہونے کہ وجہ سے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کردم توڑدیتا تھا۔
میں نے ان کو شفا بخش جڑی بوٹیوں کا استعمال سکھایا
تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔
پھر میں نے زمین کے خزانوں کے دران پر کھول دیے۔
کانسہ، لوہا، چاندی، سونا جو زمین کی تہوں میں پوشیدہ تھا۔
مختصر یہ کہ انسان کے سارے علم و فن اسی بد نصیب پرومی تھیوس کا تحفہ ہیں۔
اُسی وقت زیوس کا ناجائز بیٹا ہر مینرایلچی بن کر آتا ہے۔ پرومی تھیوس اس کو بڑی حقارت سے دیکھتا ہے اور دونوں میں تو تو میں میں ہونے لگتی ہے۔
ہرمیز۔۔۔۔ میرے باپ نے پوچھا ہے کہ وہ کون سی شادی ہے جس کے باعث تم کہتے ہو کہ
زیوس اقتدار سے محروم ہو جائے گا۔
خبردار پہیلیاں نہ بجھانا
بس سچ سچ بتانا
تاکہ مجھ کو دوبارہ اتنی دُور نہ آنا پڑے۔
پرومی تھیوس۔۔۔۔ دیوتاؤں کے اس چپڑ قناتی کی بکواس تو سنو!
کیسی اپنی اہمیت جتاتا ہے۔
تم اور تمھاری طاقت ابھی نئی نئی ہے
اورتم کو غرہ ہے کہ تمھارا قلعہ کوئی سرنہ کرسکے گا ۔
لیکن میں نے دو پشتوں کا زوال دیکھا ہے
اورتیسرے کی تباہی بھی دیکھوں گا
جو اپنے پیش رؤں سے زیادہ ذلت و خواری سے منھ کے بل گرے گا
اورجلد ہی۔
تیرا خیال ہے کہ میں نو دولتیوں کے سامنے گڑ گڑاؤں گا۔
بس تو دُم دبا کر یہاں سے بھاگ جا۔
تجھ کو کچھ نہ ملے گا۔
ہرمیز۔۔۔۔۔ گستاخ ، زبان دراز، ضدی، انھیں حرکتوں نے تیرا یہ حشرکیا۔
پرومی تھیوس۔۔۔۔ کان کھول کر سن لے۔ میں اپنی اس اذیت ناک تقدیر کو تیری غلامانہ چاپلوسیوں سے کبھی نہ بدلوں گا۔
ہرمیز۔۔۔۔ تیری دیوانگی لا علاج ہے پرومی تھیوس۔۔۔ شاید، اگردشمنوں سے نفرت دیوانگی ہے۔
ہرمیز۔۔۔ میں لاکھ سمجھاتا ہوں مگر تجھ پر اثر ہی نہیں ہوتا۔
اچھا تو سن لے کہ
انکار کی صورت میں تجھ پرلیا گزرنے والی ہے۔
اگرتونے میری بات نہ مانی تو
زیوس کا عتاب آسمان سے اونچی لہروں کی صورت میں تجھ پر نازل ہوگا
یہ پہاڑ بجلی گرنے سے پاش پاش ہو جائے گا
اورتو پاتال میں سماجائے گا
یونہی چٹان سے بندھا ہوا۔
پھرہزاروں برس بعد تو پھر اوپر آئے گا
اورتب زیوس کا کالے پروں والا خوں خوارکتا
ناخواندہ مہمان کی طرح تجھ پر جھپٹے گا
اوردن بھر تیری بوٹیاں نوچتا رہے گا
اورتیرے جگر کے ٹکڑے چبا چبا کر کھائے گا۔
یہ خالی خولی دھمکیوں نہیں بلکہ
زیوس کا فرمان ہے۔
لہٰذا اپنی ضد سے باز آجا۔
(ہرمیز چلا جاتا ہے)
پرومی تھیوس۔۔۔۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ہر میز کس لیے آیا ہے۔
مگردشمن کے ہاتھوں دُکھ اٹھانا عین عزت ہے۔
بے شک مجھ کو بجلی کے کوڑے لگائے جائیں
ہوا خشمناک آندھیوں کا جوش و خروش لے کر آئے۔
طوفان زمین کی بنیادوں کو جڑ سے اُکھاڑدے
سمندر کی گرج دار اور وحشی لہریں اٹھ کر
ستاروں کی راہ روک دیں
زیوس مجھ کو ظلمات کے گھپ اندھیرے میں پھنکوا دے
تباہی کے سفاک سیلاب میں
لیکن وہ مجھ کو جھکا نہیں سکتا
سنو!
زمین ہلنے لگی،
گھن گرج کی گونج پھیلنے لگی
بجلی کی کڑک چمک
ریت کے ذرے فوارے کی طرح گردش کرنے لگے
ہوائیں چار سمت سے آآکر ٹکرانے لگیں۔
آسمان اورسمندر چنگھاڑ رہے ہیں
میں بھنور کے گرداب میں پھنس رہا ہوں۔
اوزمین! میری ماں۔ میری مقدس ماں!
اوآسمانو! جن کو سورج چاند باری باری منّور کرتے ہیں
دیکھو، مجھ پر کیا ظلم ہو رہا ہے
(چٹان پھٹ جاتی ہے اور پرومی تھیوس غائب ہو جاتا ہے)6؎
اس ڈرامے میں ایس کائی لس پرومی تھیوس کا ہم نوا ہے۔ اس کی ہمدردیاں اپنے ہیرو کے ساتھ ہیں جو انقلابی ہے مگرایس کائی لس خود انقلابی نہیں تھا۔ یہ درست ہے کہ اس کو ایتھنز کے اربابِ اقتدار پسند نہیں تھے اورنہ وہ ان کے خداؤں کا چنداں معتقد تھا۔ چنانچہ وہ پرومی تھیوس کی زبان سے ایتھنز کے حاکموں کی اور زیوس دونوں کی جی بھر کے مذمت کرتا ہے لیکن وہ فقط سماجی نقاد ہے۔ افلاطون کی طرح مفکر نہیں جو کسی متبادل معاشرتی نظام کا منصوبہ پیش کرتا۔ یوں بھی ایس کائی لس کو ایتھنز کی رائے عامہ کا خیال کرنا پڑتا تھا کیوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈرامے میں اس قلم سے فقط ایک فقرہ ایسا نکل گیا تھا جس کی وجہ سے اس پر بے دینی کا الزام لگا تھا اور وہ سزائے موت سے بال بال بچا تھا۔ ان اسباب کی بنا پر اس نے داستان کے رایتی انجام کی پیروی کی اور ظالم و مظلوم میں مفاہمت کروادی۔
مگر 22 سو برس بعد جب برطانیہ کے جواں مرگ انقلابی شاعر شَیلی (1792۔1822) نے 1818ء میں ” پرومی تھیوس زنجیرِ بستہ” لکھی تو اس کو ایس کائی لس کی سی کوئی مجبوری نہ تھی۔ وہ دہریت کی تائید میں ایک مقالہ لکھنے پر آکسفورڈ یونیورسٹی سے نکالا جا چکا تھا اور برطانیہ کے روایت پرست ماحول سے تنگ آکر اٹلی میں رہنے لگا تھا۔ ہرچند کہ انقلاب فرانس اور نپولین کی شکست کے بعد یورپ میں رجعت پرستوں کا زور تھا مگر انقلابی روح ہرجگہ پوری قوت سے سرگرمِ عمل تھی لہٰذا شَیلی ان پابندیوں سے آزاد تھا جو ایس کائی لس کو لاحق تھیں لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ فکری اور عملی طورپر خود انقلابی تھا۔ پس اس کا ہیرو بھی آخر دم تک زیوس کے اقتدار سے سمجھوتہ نہیں کرتا۔ شَیلی اپنے اس طرزِ فکر کی تشریح کرتے ہوئے ڈرامے کے دیباچے میں لکھتا ہے کہ
” یونان کے المیہ نویس مصنف اپنی قومی تاریخ یا دیو مالا سے موضوع سخن اخذ کرتے وقت اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے تھے۔ وہ اپنے فن کو روایتی تاویل کا پابند نہیں تصور کرتے تھے اورنہ اپنے حریفوں یا پیش روؤں کی روش کی تقلید ضروری سمجھتے تھے۔ میں نے بھی یہی آزاد روش اختیار کی ہے۔ یوں بھی ظالم و مظلوم کے مابین مفاہمت سے اتنے عظیم المیے کی روح مجروح ہوجاتی۔ اگرپرومی تھیوس اپنے سفاک حریف کے آگے گڑ گڑانے لگتا تو داستان کی اخلاقی دل چسپی جو پرومی تھیوس کی مصیبتوں اوراس کے عزم و استقلال اوراس کی قوتِ برداشت کے باعث پوری شدت سے برقرار رہتی ہے ضائع ہو جاتی۔۔۔۔۔ پرومی تھیوس شیطان سے کہیں بہتر شاعرانہ کردار ہے۔ اس لیے کہ وہ ذاتی حرص و ہوس ، رشک حسد یا انتقام اور منفعت کے جذبات سے پاک ہے۔ وہ اخلاقی اور ذہنی صلاحیتوں کا نہایت مکمل نمونہ ہے۔ اس کے مقاصد نہایت اعلیٰ اور نیک ہیں اور اس کے محرکات نہایت سچے۔” 7؎
(2)
سوال یہ ہے کہ آگ میں وہ کیا خاص بات ہے کہ زیوس اس کو انسانوں سے خفیہ رکھنا چاہتا تھا اور راز کے افشا ہونے پر پرومی تھیوس کو اتنی کڑی سزا دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں آگ کیا شے ہے اور اس نے انسانی معاشرے کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا ہے؟
آگ ایک کیمیاوی عمل ہے (شے نہیں ہے) جو آکسیجن گیس اور کاربن اور دوسرے نامیاتی عناصر کے آپس میں اس طرح ملنے کا نام ہے کہ اس آمیزش سے حرارت، شعلہ اور روشنی پیدا ہو۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب کیمیاوی عناصر گیس میں تبدیل ہو جائیں۔ آگ مادی اشیا سے بنتی ہے اور مادی اشیا ہی کی ایک کیفیت ہے۔ وہ سب سے بڑی انقلابی قوت ہے جس کے عمل سے مادی چیزوں کی ہیئت اور ماہیت میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ وہ کبھی ٹھوس مادے کو مثلاً کوئلہ، کافور، لکڑی وغیرہ اور کبھی رقیق مادے کو مثلاً پانی ، تیل، پیٹرول وغیرہ کو گیس میں بدل دیتی ہے، کبھی ٹھوس اشیا کو رقیق بنا دیتی ہیں مثلاً سونا، چاندی، لوہا وغیرہ کو اورکبھی ان سے نئی چیز خارج کرتی ہے جو رقیق ہوتی ہے مثلاً شنجرف سے پارہ اور کبھی کسی ٹھوس مادے سے نیا ٹھوس مادہ بنا دیتی ہے مثلاً ریت سے شیشہ، پتھر سے چونا۔
یہ کیمیاوی عمل آگ کا سب سے بڑا وصف ہے ۔ چنانچہ پروفیسر فیرکٹن کے بقول ” کیمسٹری کے فن میں آگ ہماری سب سے بڑی معلم ہے۔ اس نے ہم کو بہت کچھ سکھایا ہے۔” 8؎ اس ضمن میں وہ روما کے مشہور سائنس دان پلائنی کبیر(23۔79ء) کا بصیرت افروز اقتباس پیش کرتے ہیں جس نے لکھا تھا کہ
” میں نے انسان کی قوتِ ایجاد کا تذکرہ مکمل کرلیا۔ مجھ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تقریباً ہر موقعے پر آگ ہی نے “فعال عامل” Active Agent کا کردار ادا کیا ہے۔ آگ ریت کو کبھی شیشے میں بدلتی ہے کبھی چاندی میں، کبھی شنجرف میں، کبھی طرح طرح کےجستوں میں، کبھی رنگوں میں کبھی دواؤں میں۔ آگ ہی سے پتھر کو پگھلا کر کانسہ بناتے ہیں، لوہے کو ڈھالتے ہیں اورسونا تیار کرتے ہیں۔ آگ ہی کنکر پتھر کو جلا کر چونا بنا دیتی ہے جس سے ہم اپنے گھروں کی چھتوں، دیواروں کو مستحکم کرتے ہیں۔ پھر ایک ہی شے پہلی آنچ میں کچھ ہوتی ہے دوسری آنچ میں کچھ، اورتیسری آنچ میں کچھ اور، مثلاً کوئلے میں بجھنے کے بعد ہی طاقت آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اب دم نہیں رہا حالاں کہ اس کی طاقت اور بڑھ چکی ہوتی ہے۔ او آگ! قدرت کا وہ مظہر جس کی نہ تھاہ ہے نہ جس کا پیٹ کبھی بھرتا۔ ہم تجھ کو کیا کہیں؟ خالق یا ہالک؟”
جس شے میں اتنی خوبیاں ہوں اس کی چوری پر زیوس برہم نہ ہوتا تو کیا خوشی کے گیت گاتا۔
یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ ابتدائی انسان نے آگ کا استعمال کب اور کیسے دریافت کیا۔ پروفیسر ول ڈیورنٹ نے 1954ء میں یہ خیال ظاہر کیا تھا بنی نوع انسان نے آگ جلانا تقریباً چالیس ہزار برس پہلے سیکھا۔ دلیل یہ تھی کہ پیکنگ (چین) کے انسانی زندگی کے جو قدیم ترین آثار غاروں میں ملے ان میں جانوروں کی جلی ہوئی ہڈیاں بھی تھیں۔ یہ آثار کم از کم پچاس ہزار برس پرانے ہیں۔9؎ لیکن گزشتہ تیس پنتیس سال کے دوران کینیا (افریقہ) اور دوسرے مقامات پر آدمی کے جو دانت، کھوپڑیاں اور جبڑے ملے ہیں وہ چار پانچ لاکھ برس پرانے ہیں۔ پروفیسر بروناسکی نے غالباً اسی بنا پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسان چارلاکھ برس پہلے بھی آگ کے استعمال سے واقف تھا 10؎ انسان کے عضوی ارتقا کا یہ وہ زمانہ تھا جب وہ پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہونے لگا تھا، اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے تھے اور اس کے بھیجے کی جسامت 12 سو کیوبک میٹرہو گئی تھی جب کہ اس نوع سے مشابہ دونوں پاؤں پر کھڑے ہوئے نیم انسان نیم بوزینہ کے مغز کی جسامت فقط 5 سو کیوبک میٹر تھی۔ پروفیسر کارل سگین نے جدید ترین تحقیقات کی روشنی میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ انسان پانچ لاکھ برس سے آگ استعمال کررہا ہے۔11؎ وہ ہاتھوں کی مدد سے پتھر، لکڑی اور ہڈی کے طرح طرح کے آلات و اَوزار بنانے لگا تھا اوراپنے تجربات، خیالات اور احساسات کو بامعنی آوازوں (الفاظ) کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے بھی لگا تھا۔
مگرانسان ابتدا میں آگ کو مصنوعی طورپر خود” پیدا” نہیں کرسکتا تھا بلکہ جو آگ قدرتی طورپر دستیاب ہوتی اسی سے کام لیتا تھا۔ یہ استعمال اس نے جانوروں سے نہیں سیکھا کیوں کہ انسان کے علاوہ کوئی حیوان آگ استعمال نہیں کرتا نہ آگ کے قریب جاتا ہے بلکہ اس سے بے حد ڈرتا ہے جب کہ آدمی کا گھٹنیوں چلتا بچہ بھی آگ سے بالکل خوف نہیں کھاتا۔ اس کو اگر روکا نہ جائے تو وہ آگ کو بھی چمکتا کھلونا سمجھ کراس کو چھولے۔ آلات و اوزار بنانا بڑا شعوری عمل ہے اورانسان کی سوجھ بوجھ میں ترقی کا ثبوت بھی اورجب وہ اس تخلیقی عمل پر قادر ہوگیا تواس کے ذہن کا آگ کے استعمال کی جانب منتقل ہونا اچنبھے کی بات نہ تھی۔ شاید سورج کی گرمی کے فوائد محسوس کرکے، شاید پتھر توڑتے وقت ہو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کے تجربے سے، شاید جنگل میں اچانک آگ لگنے کے مشاہدے سے یا بجلی گرنے اور آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے۔ بہرحال جو ماجرا بھی پیش آیا ہو، یہ واقعہ ہے کہ انسان نے اوّل اوّل آگ کے قدرتی مظاہر ہی سے استفادہ کیا۔ چنانچہ بعض پس ماندہ قومیں ابھی کل تک آگ “پیدا” نہیں کرسکتی تھیں مثلاً جزیرہ انڈمان (کالا پانی) اور جزیرہ پہیپوا (بحرالکاہل) میں بیسویں صدی کی ابتدا تک ایسے قبیلے موجود تھے جو آگ “بنا” نہیں سکتے تھے۔ ان کی آگ اگرکسی وجہ سے بجھ جاتی تو وہ میلوں کا سفرطے کرکے کسی دوسری بستی سے جلتا کوئلہ لے آتے تھے۔ آسٹریلیا میں اور افریقہ کی حریرو قوم میں جلتی آگ کی حفاظت کنواری لڑکیوں کا فریضہ تھا۔ قدیم روما میں گھر اور چولھے کی دیوی کا نام وستا تھا۔ اس کی عبادت گاہ میں جہاں سدا آگ جلتی رہتی تھی آگ کی نگرانی کنواری دیو داسیوں کے سپرد تھی اورآگ بجھ جاتی تو دیوداسیوں کی نگراں کو قتل کردیا جاتا تھا۔ آگ کو بجھنے نہ دینے کی قدیم روایت اب بھی زندہ ہے۔ مثلاً پیرس کے عین وسط میں ” محرابِ نصرت” کے اندر گیس کے شعلے کبھی بجھنے نہیں پاتے۔ یہی منظر ماسکو میں ” گمنام سپاہی” کی قبر پر نظر آتا ہے۔ بچوں کی سالگرہ کے موقعے پر شمعیں جلانا اور خوشی کی تقریبوں میں روشنی کرنا بھی دراصل پرانے دنوں ہی کی یادگار ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ آگ، روشنی ، حرارت، توانائی اور زندگی سب ہی کچھ ہے۔
انسان نے منصوعی طورپر آگ پیدا کرنے کا ہنر بھی قدرت ہی سے سیکھا۔ گرم اور خشک موسم میں جنگلی درختوں کی شاخوں کے آپس میں رگڑ کھانے سے شعلے اچانک بھڑک اٹھتے ہیں اور جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ ابتدائی انسان نے اسی قدرتی عمل کی تقلید کی اور دو لکڑیوں کو آپس میں رگڑ کر آگ پیدا کی۔ چنانچہ سماترا، شری لنکا، جنوبی امریکہ، جزائر ہوائی اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں ابھی تک ایسی قومیں موجود ہیں جو لکڑیوں کو رگڑ کر آگ پیدا کرتی ہیں۔ (چقماق پتھرلینی فلنٹ کو رگڑ کر آگ نکالنا اسی عمل کی ایک شکل ہے اور ہماری دیا سلائی یعنی ماچس بھی جو 1830ء ایجاد ہوئی اور سب سے پہلے ہمارے ملک میں غالبؔ نے جس کی تعریف کی )۔ نظریہ ارتقا کا بانی چارلس ڈارون (1809ء۔1882ء) اپنے سفر نامے Voyage of the Beagle میں لکھتا ہے کہ میں نے جزیرہ تہیتی (بحرالکاہل) میں ایک شخص کو دیکھا جس نے دو لکڑیوں کو آپس میں رگڑ کر پل جھپکتے آگ نکال لی لیکن مجھ کو اسی کام میں بڑی دیر لگی اور میں بار بار کوشش کرنے کے بعد کامیاب ہوا۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹینکا میں ایک تصویر نظر سے گزری جس میں اَرواک قوم کے دو نیم برہنہ مرد زمین پر گھٹنے ٹیکے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص لکری کی تختی کو جس میں چھوٹا سا گول خانہ بنا ہے زمین پر رکھ کردونوں ہاتھو ں سے زورسے دبائے ہوئے ہے جب کہ دوسرا آدمی ایک چھڑی کو جس کا ایک سرا تختی کے خانے ممیں پیوست ہے دونتوں ہتھیلیوں سے چکر دے رہا ہے جیسے گاؤں کی عورتیں چھاچھہ بلوتے وقت متھنی کو تیز تیز گھماتی ہیں۔ چھڑی کی گردش سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ 12؎
دو لکڑیوں کو رگڑ کر آگ پیدا کرنے کا تاریخی ثبوت رگ وید میں ملتا ہے جو دنیا کی سب سے پرانی کتاب ہے اور جس کی تصنیف وادیِ سندھ میں اب سے کم از کم تین ساڑھے تین ہزار برس پہلے ہوئی تھی۔ رگ وید کے 31 ویں بھجن میں شاعر اگنی دیوتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ
دو ماؤں کے بطن سے نکلے ہوئے، عاقل و دانا
ہستی عالم میں رواں دواں،
زندہ انسان کی خاطر ان گنت جگہوں میں موجود 13؎
ایک اورجگہ دو لکڑیوں کو رتھ کے دو گھوڑوں سے تشبیہہ دی گئی ہے اور دھوئیں کو لشکر کے پرچم سے 14؎
ایک اورجگہ لکھا ہے کہ
اگنی کے آگے ٹھوس سے ٹھوس چیز جھک جاتی ہے
چکنی لکڑیاں جو گرم ہو کر آگ دینے لگتی ہیں
رالف گریفتھ رگ وید کے مشہور مفسر سائن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ان لکڑیوں سے مراد وہ دو لکڑیاں ہیں جن کو رگڑ کر آگ پیدا کرتے تھے۔ وہ حاشیہ میں لکھتا ہے کہ ہون کی مقدس آگ کو آج بھی (1889ء میں ) اسی طرح روشن کیا جاتا ہے۔
دو لکڑیوں کو رگڑ کر آگ نکالنے کے ہنر کی تاریخی اہمیت پر تبصرہ کرتے ہوئے اینگلز لکھتا ہے کہ
” بھاپ کے انجن نے ہرچند کہ سماجی دنیا میں زبردست انقلاب برپا کردیا ہے۔۔۔۔ لیکن اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ لکڑیوں کورگڑ کر آگ پیدا کرنے کے عمل کا انسان کے قادر اورخود مختار ہونے میں بڑا دخل ہے کیوں کہ رگڑ سے آگ پیدا کرنے کے باعث اُس کو پہلی بار ایک قدرتی طاقت پر اختیار حاصل ہوا۔ اس طرح وہ اقلیم حیواناں سے ہمیشہ کے لیے الگ ہوگیا۔
” ہم ماضی کی پوری تاریخ کو میکانکی حرکت کو حرارت میں تبدیل کرنے کی کار آمد دریافت سے حرارت کی میکانکی حرکت میں تبدیلی تک سفر کرنے کا عہد کہہ سکتے ہیں۔” 15؎
آگ کی دریافت نے انسانی زندگی کی کایا پلٹ دی۔ اُس کو سورج کا بدل ہاتھ آگیا جو روشنی اورگرمی کا واحد ذریعہ تھا۔ اب اس کے غار اندھیرے نہیں رہیں گے۔ اندھیرا جو خوف پیدا کرتا ہے اور جس کی موجودگی میں ہاتھ پاؤں بے کار ہو جاتے ہیں اوربات چیت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اورکچھ سجھائی بھی نہیں دیتا۔ اب خوں خوار درندے اس کے قریب نہ آسکیں گے۔ اب وہ گوشت اور سبزیاں بھون کر کھائے گا جس کی وجہ سے اس کا ہاضمہ بہتر ہوجائے گا اورتوانائی بڑھ جائے گی اور شرح اموات گھٹے گی اور آبادی میں اضافہ ہوگا۔ اب وہ گرم علاقوں میں بودوباش پر مجبور نہ ہوگا بلکہ سرد علاقوں کو بھی آباد کرے گا۔ اب وہ مٹی کے کچے برتنوں کو پکا کر پتھر کی مانند پائیدار اور دھنک کی مانند خوش رنگ بنا لے گا۔ وہ تانبہ، ٹن، لوہا اور دوسری دھاتوں کو پگھلا کر نئے نئے آلات و اوزار تیار کرے گا جس سے اس کی پیداواری قوت بہت بڑھ جائے گی۔ وہ مصنوعات کی طرح ڈالے گا جو قدرت کے کارخانے میں موجود نہ تھین۔
آگ کے استعمال سے انسان کو تسخیرِ قدرت کا نسخہ ہاتھ آگیا۔ اب تک وہ شیا میں کسی قسم کی کیفیتی یا کمیتی تبدیلی کرنے سے قاصر تھا۔ آگ کو کام میں لاکر پروفیسر گورڈن چائلڈ کے بقول ” تاریخ میں پہلی بار قدرت کا ایک مخلوق ایک نہایت طاقت ور قوت پر حکم لگانے کا اہل ہوا۔ اس نے دوسرے جانوروں کی طرزِ زیست سے انقلابی علیحدگی اختیارکرلی۔ وہ اشیا کو عدم سے وجود میں لاکر شعوری طورپر ان کا خالق ہوگیا۔ اس طرح اس نے اپنی انسانیت کا لوہا منوایا اور اپنی ذات کی تکوین کی۔” 16؎
حقیقت یہ ہے کہ انسان نے اگرآگ کا استعمال نہ سیکھا ہوتا تو ہنوز پتھر کے زمانے ہی میں زندگی بسرکرتا اورجانوروں کی طرح قدرت کا محتاج اور مجبور ہوتا نہ کہ قدرت کا حاکم و آقا۔ آگ ہی کے طفیل وہ پتھر کے عہد سے دھاتوں کے عہد میں داخل ہوا۔
پرانے زمانے میں آگ کے عجیب و غریب استعمال رائج تھے۔ مثلاً آگ کے الاؤ سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایس کائی لس کے ایک ڈرامے میں یونان کے بادشاہ آیگ ممنان کی ملکہ کلائی ٹم نس ٹرا کو جنگ ٹرائے کے سرہونے کی خوش خبری شعلوں ہی کی زبانی ملتی ہے۔ آسٹریلیا کی پرانی قومیں دھوئیں کے ذریعے دو دو تین تین ہزار میل تک اپنے پیغام پہنچا دیا کرتی تھیں۔ جہازوں کی رہنمائی بھی ساحل پر روشنی کر کے ہوتی تھی۔ جنگ میں دشمن کی صفوں یا قلعوں پر شعلہ فگن گولے یا مشعلیں پھینکی جاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ سسلی کے دارالحکموت سیرا کوز کے محاصرے میں مشہور سائنس دان ارش میدیس (212۔287ء) نے رومی جہازوں کو محدب شیشوں سے سورج کی تیز کرنیں پھینک کر جلادیا تھا۔ یہ وہی ارش میدیس ہے جس نے کہا تھا کہ مجھ کو زمین کے سرے پر لیور (بیرم) رکھنے دو، میں زمین کو اوپر اٹھادوں گا۔
آگ کا استعمال اگرچہ گرم علاقوں کی دریافت ہے مگر آگ سے پیار قدرتی بات ہے کہ سرد ملکوں کے رہنے والوں ہی نے کیا۔ افریقہ اور مصریا عرب، شام و عراق کے جلتے تپتے صحرا کے باشندوں کے فکرو احساس پر آگ کے تخریبی خصائل ہی نے اپنا اثر جمایا۔ ان کے نزدیک آگ کی نمایاں خصوصیت بس یہی تھی کہ وہ جلاتی اور اذیت پہنچاتی ہے۔ جہاں سال میں آٹھ مہینے قیامت کی گرمی پڑتی ہو اور آگ کے قریب جانا عذاب سے کم نہ ہو وہاں آگ کے تخلیقی اور فیض بخش پہلوؤں پر کون غورکرسکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گرم ملکوں میں نمودار ہونے والے مذاہب نے بھی آگ کا بڑا بھیانک نقشہ پیش کیا ہے۔ آخر جہنم میں آگ ہی کے شعلے تو بھڑکیں گے۔ البتہ ریگستانی علاقوں میں آگ کے بجائے پانی اور درختوں کی بڑی اہمیت ہے اور وہاں کے لوگ ان چیزوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں لہٰذا جنت میں آگ کا گزر نہیں بلکہ وہاں میووں سے لدے درخت ہوں گے، ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں ہوں گی اور کوثرو تسنیم کا شفاف پانی ہوگا۔
اس کے برعکس سرد علاقوں میں رہنے والی آریائی قوموں میں آگ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آریاؤں کی زندگی کا دارو مدار بڑی حد تک آگ پر تھا اس لیے وہ آگ کو سینے سے لگائے پھرتے تھے۔ اس کی پرستش کرتے تھے اور اس کی ثنا و صفت میں بھجن گاتے تھے۔ مثلاً رگ وید میں کہ 1017 بھجنوں پر مشتمل ہے اِندرا کے بعد سب سے زیادہ گیت اگنی دیوتا ہی کی شان میں ہیں۔ اندرا کی فضیلت کا سبب یہ تھا کہ وہ وادی سندھ میں آریوں کا سب سے بڑا ہیرو تھا جس کی سربراہی میں انھوں نے یہاں کی پرانی قوموں۔۔۔۔ اسورا اور داسیووغیرہ۔۔۔ ۔ کو زیرکیا تھا۔ اس کے باوجود رگ وید کا آغاز اگنی دیوتا کی مدح میں لکھے گئے بھجنوں سے ہوتا ہے۔ رگ وید کے شاعروں نے اگنی کے بے شمار فضائل و اوصاف بیان کیے ہیں۔ وہ مطہر ہے، جاوداں ہے، رزّاق ہے، پیغام برہے، انسان کی دوست ہے، آریاؤں کی آنکھ ہے، اندھیرے کو نیست و نابود کرنے والی ہے، خوش شکل ہے، تاریکی میں بھی دیکھ لیتی ہے، دولت کی کنجی ہے، بے خطا اور معصوم ہے۔ دانا، عاقل اور سخی ہے، ان داتا ہے اور پھلوں کو پکاتی ہے۔
او اگنی! تیرے اَن گنت نام ہیں
تو لافانی ہے، مقدس ہے، خدا ہے 17؎
زرتشتی مذہب میں بھی آگ کو بہت مقدس اور پاکیزہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں تھوکنا یا کوئی گندی چیز پھینکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پارسیوں کی عبادت گاہ کا نام ہی آتش کدہ ہے جہاں آگ جلتی رہتی ہے۔ شاید وہ کسی زمانے میں آگ کی پرستش بھی کرتے ہوں۔
(3)
پرومی تھیوس کی داستان اور آدمؑ کے قصے میں کوئی شے اگر مشترک ہے تو وہ امتناعی حکم ہے۔ زیوس کا حکم تھا کہ آگ کا راز انسان سے مخفی رکھا جائے۔ پرومی تھیوس اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے لہٰذا سز پاتا ہے۔ آدمؑ جنت سے نکالے جاتے ہیں کیوں کہ انھوں نے شیطان کے بہکانے پر شجرِ ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا۔ زیوس کا یہ اندیشہ بے جانہ تھا کہ آگ کے استعمال سے آگاہ ہوکر انسان کہیں اس کی خدائی ہی سے منکر نہ ہو جائے۔ اس کی عطا و بخشش کا محتاج نہ رہے بلکہ آگ کی مدد سے نئی نئی چیزیں خود پیدا کرنے لگے اور ایسا ہی ہوا اورایک دن آیا جب انسان اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ
تو شب آفریدی، چراغ آفریدم
اقبالؔ
(وہ بھی آگ ہی کے حوالے سے )
مگرآدم کو جب یہ حکم ملا کہ جنت میں آرام سے رہو۔ جو چاہو کھاؤ پیو لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا(سورہ بقرہ 34) تو مشیتِ الہٰی کیا تھی؟ یہ سوال قدرتی طورپر ذہن میں ابھرتا ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا اور اس میں کیا خاصیت تھی کہ اس کا پھل کھانے پر آدمؑ کو بہشت سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن اس باب میں خاموش ہے البتہ عہدِ سابقہ کے مفسرین نے جن کو مغرب کا خوف نہ تھا ، خوب خوب قیاس آرائیاں کی ہیں لیکن دورِ حاضر کے علما درخت کی تفصیلات میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی بس اتنا کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ “خدا جانے وہ کیا درخت تھا” ۔ 18؎ مولانا مودودی ایک طرف یہ فتویٰ صادرفرماتے ہیں کہ ” یہ بحث غیر ضروری ہے (کیوں؟) کہ وہ کون سا درخت تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی” دوسری طرف خود ہی بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ ” منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اوراس سے آدمؑ اور حوا کو نقصان پہنچنے خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کرلینا کافی تھا اس لیے اللہ نے درخت کا نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا” 19؎
یہ تاویل ممکن ہے مولانا مودودی کے مریدوں کو مطمئن کرسکے لیکن قرآن کے الفاظ سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ پہلے کوئی بے بنیاد مفروضہ قائم کرنا اورپھر اس کی تردید کرنا مولانا کی خاص ادا ہے۔ بھلا کوئی پوچھے کہ جنت میں کسی نقصان دہ درخت کا ذکر کس نے کیا ہے؟ اسی آیت میں یہ تحریر ہے کہ ” ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤگے” سو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسئلہ اخلاقی ہے۔ آدمؑ کی صحت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دراصل مودودی صاحب کےذہن میں خدا کا تصور کسی آمرِ مطلق ، کسی جابر سلطان بلکہ پولیس کے افسرِ تفتیش سے چنداں مختلف نہیں ہے۔ ان کا خدا عام بندوں کا تو ذکر ہی کیا اپنے خلیفتہ الارض کو بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اورپھر سزا دیتا ہے۔ وہ کبھی خدا کی “عظیم الشان سلطنت” کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی عہدِ خداوند کی تشریح فرماتے ہوئے بادشاہ کے فرمان کی مثال دیتے20؎ اورکبھی وہ خدائی طرزِ حکومت کو خاکی فرماں رواؤں کے طرزِ حکومت کا چربہ بنا کر پیش کرتے ہیں 21؎ ان کے خیال میں خدا کے فرشتے ” پولیس کے بے وردی سپاہی” ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت 101 کی تشریح کرتے ہوئے جس میں ہاروت ماروت کا قصہ بیان کیا گیا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ
“رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا (جادو) جو بجائے خود بری تھی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خوار حاکم کو نشان زدہ سکے یا نوٹ لے جاکر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالتِ ارتکابِ جرم میں پکڑیں اوراس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔” 22؎
ایسی صورت میں اگرکوئی شخص کہے کہ ہمارے خدا کا تصور بادشاہ اور بادشاہت کے تجربوں کا ذہنی عکس ہے تو ہم اس کا منھ کیوں کربند کرسکتے ہیں۔
شجرِ ممنوعہ کے بارے میں مولانا مودودی کی تاویل سے توریت کی توجیہہ کہیں زیادہ قرینِ قیاس نظر آتی ہے۔ مثلاً کتابِ پیدائش میں لکھا ہے کہ
” اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایااور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خدا وند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اورکھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اورباغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔۔۔۔ اور خداوند نے آدمؑ کو حکم دیا اورکہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیوں کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔”23؎
مگر سانپ نے حوا کو بہکایا اور کہا کہ جس دن تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے۔ ” تو تمھاری آنکھیں کھل جائیں گی اورتم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔”
اب ہیوطِ آدمؑ کا سبب توریت کی زبان سےسنیے:
“اور خداوند نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہوگیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اورحیات کے درخت سے بھی کچھ لے کرکھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغِ عدن سے باہر کردیا۔۔۔۔ اور باغِ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔” 24؎
آگ کے عاملانہ کردار پر فلسفیوں میں سب سے پہلے ہرق لاطیس (535۔۔۔۔ 475 ق۔م) نے نہ صرف غورکیا بلکہ اپنے حرکت و تغیر کے جدلیاتی فلسفے کی بنیاد ہی آگ کی تغیر پذیری پر رکھی۔ اس کا قول تھا کہ ” اس دنیا کو جو سب کے لیے یکساں ہے نہ خداؤں میں سے کسی نے بنایا اورنہ انسانوں نے بلکہ وہ ہمیشہ سے تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ سدا جیتی آگ ہے جس کی ایک مقدار روشن ہوتی ہے اورایک مقدار بجھ جاتی ہے” 25؎ ہرق لاطیس Heraclitus آیونیا 26؎ کے شہر افی سوس کا رہنے والا تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ اس کا تعلق افی سوس کے پرانے شاہی خاندان سے تھا۔ اس نے شادی کبھی نہیں کی اورنہ اونچے طبقے والوں کی صحبت میں کبھی بیٹھا بلکہ اس نے اپنا سارا مال و متاع بھائی کو دے کر قلندرانہ زندگی اختیار کرلی۔ وہ جنگلوں ، پہاڑوں میں گھومتا پھرتا اور جب کبھی شہر آتا تو زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارتا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے تین حصے تھے۔ پہلا حصہ کائنات کے بارے میں تھا دوسرا سیاست کے بارے میں تیسرا مذہَبیات کے بارے میں۔ یہ کتاب توناپید ہے البتہ اس کے 1130 قوال یونانی فلسفیوں نے اپنی تصنیفات میں جابجا نقل کیے ہیں۔ افلاطون نے تو اپنی تصنیفات بالخصوص ” قراطائی ئس” (Cratylus) اور ” تھی ٹے ٹس” (Theatetos) میں ہرق لاطیس کے نظریوں کو رد کرنے کی پوری کوشش ہے۔
ہرق لاطیس کا شہر زرتشتی حاکموں کے زیرِ نگیں تھا لہٰذا ممکن ہے کہ اس نے زرتشتوں کی مذہبی کتابوں سے یا ان کے آتش کدوں سے متاثر ہوکر آگ کو کائنات کا اصل الاصول قرار دیا لیکن اس نظریات آیونیا کے نیچری فلسفیوں کی روایت کے بھی عین مطابق تھے بلکہ اسی کی ترقی یافتہ شکل تھے۔ مثلاً وہاں کے سب ہی نیچری فلسفیوں نے کائنات کے وجود کی تشریح کائنات ہی کے حوالے سے کی، کسی ماورائی قوت کو نہ تو کائنات کے وجود کا سبب بنایا اورنہ کسی دیوی دیوتا کو اس کا مالک تسلیم کیا جو اس کو چلاتا ہو۔ یہ نیچری فلسفی وحدت الوجود کے بھی قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کائنات جو بظاہر کثرت نظرآتی ہے اس کی اصل کوئی واحد عنصر ہے۔ طایسؔ نے پانی کو اصل الاصول کا مرتبہ دیا۔ انکسای نیز نے ہوا کو، انکسی ماندر نے پیکار کو اور دیمقراطیس نے ایٹم کو۔ اسی طرح یہ فلسفی کائنات کی حرکت کو بھی مانتے تھے۔
ہرق لاطیس نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ وہ کہتا تھا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ اشیا کیا ہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کیسے وہ ” ہوئیں” جو وہ ہیں۔ گویا اصل حقیقت “شدن” ہے نہ کہ ” بودن” نمود (Becoming) ہے نہ کہ وجود (Being) یعنی وہ ہم کو اشیا کو ان کی حالتِ حرکت و تغیر میں دیکھنے کی دعوت دیتا ہے نہ کہ عالمِ سکون و ثبات میں۔ مگراس تغیر پذیری کی نوعیت کیا ہے۔ اشیا کس اصول، کس قانون کے تحت حرکت کرتی اور بدلتی ہیں۔ اس قانونِ حرکت و تغیر کی دریافت جس کو جدلیت کا قانون کہتے ہیں ہرق لاطیس کا عظیم تاریخی کارنامہ ہے۔ لینن جن دنوں سوئزرلینڈ میں (1915ء) جلا وطنی کی زندگی بسر کررہا تھا تو اس نے 19 ویں صدی کے جرمن ” سوشلسٹ” لسال کی تصنیف “ہرق لاطیس” پڑھی اوراپنی بیاض میں اس پر کڑی نکتہ چینی کی البتہ ہرق لاطیس کے اس مقولے کے بارے میں جس کو ہم نے اوپر نقل کیا ہے لکھا کہ یہ ” جدلّی مادّیت کے اصولوں کی بڑی اچھی تشریح ہے۔” اور لسال کی شکایت کی کہ یہ شخص ہرق لاطیس کو ہیگل کا ہم خیال بنا رہا ہے اوراس کی “زندہ دلی، تازگی ، بھولے پن اور تاریخی بصیرت و دیانت کو برباد کررہا ہے” 27؎ جدلّیت سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اور انسان اور اس کے معاشرے میں کہ کائنات ہی کا ایک جز ہے دو متضاد قوتیں وحدت کی شکل میں ہر وقت آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں۔ اسی تصادم ، اس ” کشاکشِ پیہم” (اقبال) سے نئی اشیا وجود میں آتی اور وہ مسلسل حرکت کرتی اور بدلتی رہتی ہیں۔
ہرق لاطیس نے کائنات کی وحدت1، حرکت2 اور جدلیت 3 تینوں کی تشریح کے لیے آگ کو منتخب کیا۔ یہ کلیے شاید اس نے آگ کی طبعی خصوصیات ہی سے اخذ کیے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ دنیا بیک وقت وحدت بھی اور کثرت بھی اوریہ کہ ضدین کا باہمی تناؤ ہی اس وحدت کی بنیاد ہے” دانائی بہت سی چیزوں کا علم نہیں بلکہ ضدین کے تصادم میں جو وحدت پوشیدہ ہے اس کا ادراکِ دانائی ہے۔” مگر یہ کوئی منطقی مفروضہ نہ تھا بلکہ خالص مادی حقیقت تھی۔ یہ وحدت، یہ اصل الاصول کون سی شے ہے۔ وہ آگ ہے جس کی فطرت میں تمام دوسری اشیاء بن جاتا اورپھر دوسری تمام اشیا کا اس میں منتقل ہو جانا ہے۔ تمام اشیا آگ کا بدل ہیں اور آگ تمام اشیا کا بدل ہے ” جس طرح بازاری چیزیں سونے کا بدل ہیں اور سونا بازاری چیزوں کا ۔” ” ہر شے آگ ہی کی ایک شکل ہے خواہ مائل بہ نسبت مثلاً تمی، پانی، مَٹی جو آگ کی انجمادی کیفیت ہے، خواہ مائل بہ فراز”۔۔۔۔ ” اوپر جانے اور نیچے اترنے کا راستہ ایک ہے” 28؎ ” آگ کی تغیر شدہ شکل سمندر ہے جو آدھا مٹی آدھا ہوا ہے جو آب خرات بن کر اوپر جاتی ہے اورپھر پانی بن کر نیچے گرتی ہے۔” ” جب آگ کو دباتے ہیں تو وہ پانی بن جاتی ہے، پانی جم کر مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ نشیبی رحجان ہے۔ پھر مٹی پانی بنتی ہے۔ پانی اوپر اٹھتا ہے سمندر سے بھاپ بن کر۔ یہ فرازی رحجان ہے۔” انسان کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے جسم کی آگ (حرارت) مستقل پانی بنتی رہتی ہے اورپانی مٹی۔ انسان تین ” عناصر” سے بنا ہے۔ آگ، پانی اور مٹی۔ شعوری یعنی فعال عنصرآگ۔ ” جب آگ جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو پانی اور مٹی دونوں بے کار ہو جاتے ہیں۔ مردوں کی لاش گوبر سے بھی کم وقیع ہوتی ہے۔” ” لہٰذا ہم ہر لمحہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔”
آگ میں حرکت اور تغیر پذیری کی جو خاصیت ہے وہ اتنی واضح ہے کہ کسی طویل تشریح کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آگ کی لَو یا شعلے میں آگ کی مقدار بہ ظاہر یکساں رہتی ہے لیکن اس کا مادہ (ایندھن) مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ وہ مسلسل دھوان بن کر اوپر جاتا ہے اور نیا مادہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ گویا ہستی کی حقیقت ایک رواں دواں چشمہ ہے جس کو سکون و ثبات نہیں۔ لہٰذا ” ہم ایک دریا میں دوبار نہیں نہا سکتے۔” ” کوئی شے’ہے’ نہیں بلکہ ‘ہورہی’ ہے”۔ ” حرکت اورتغیر ہستی کے وجود کی شرط اور اس کے وجود کا انداز ہے۔”
روشن آگ جدلی عمل کی نمایاں مثال ہے۔ وہ گیس اورنامیاتی اشیا کے داخلی تضاد و تصادم ہی سے تو وجود میں آتی ہے لیکن ہرق لاطیس نے جدلیت کی دوسری مثالیں بھی دیں جو اس کی قوتِ مشاہدہ اور ذہانت پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ” لوگوں کو نہیں معلوم کہ جو شے بہ ظاہر اپنی مخالف نظرآتی ہے وہ درحقیقت موافق ہے۔ مثلاً کمان اور بربط۔ ” ایک اور جگہ کہتا ہے کہ ” کمان زندگی کہلاتی ہے (یونانی زبان میں ) مگر اس کا عمل موت ہے۔” اس کی رائے میں ضدین کی پیکار درحقیقت ان کی ہم آہنگی ہے۔ جیسے ہم بربط یا ستار کے تاروں سے نکلنے والی آوازوں کے آہنگ سے سُر ملاتے ہیں اسی طرح جب ہم کمان کھینچتے ہیں تو ہمارے دونوں ہاتھوں کی حرکت ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ سے ہم کمان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کو اپنے سے دُور لے جاتے ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ ” خیر اور شرایک ہیں۔” اس کے معنی یہ نہیں کہ نیکی اور بدی ایک ہیں بلکہ وہ ایک ہی حقیقت کے دو ناقابلِ انفکاک پہلو ہیں۔ تنہا آدمی اگر کسی جزیرے میں ہو تو خیرو شر دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں، نہ شر رہتا نہ خیر۔۔۔۔ وہ کہتا ہے کہ “ہومر کا یہ قول غلط ہے کہ کاش خداؤں اور انسان کے درمیان سے پیکار ہمیشہ اٹھ جائے” اس نے یہ نہ دیکھا کہ وہ کائنات کی ہلاکت کی دعا مانگ رہا تھا کیوں کہ اس کی دعا سن لی جاتی تو کائنات فنا ہو جاتی۔” ایک خط میں لکھتا ہے کہ ” انسان بھی قدرت ہی کی مانند حرکت کرتے ہیں لیکن حیرت ہے کہ وہ ان قوانین کو تسلیم نہیں کرتے جن کے مطابق قدرت حرکت کرتی ہے۔ مصور رنگوں کے فرق و امتیاز سے متناسب اور ہم آہنگ اثر پیدا کرتے ہیں، موسیقار پنچم اور مدھم سُروں سے یا دو آدمی جو لکڑی کو آرے سے چیرتے ہیں۔ رات اور دن ایک وحدت ہیں، یہ نہیں کہ رات دن ہے اور دن رات بلکہ وہ ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں یعنی آگ اورپانی کے ایک مقدار میں گردش کے۔ ایک کے بغیر دوسرا ممکن نہیں اور جو تشریح دن کی ہوگی وہی رات کی۔”
پرومی تھیوس کی داستان سے صرفِ نظر کرکے حال کی آنکھوں سے دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا آگ دور حاضر کے فلسفہ تاریخ اور فلسفہ انقلاب کے حق میں مشعلِ ہدایت ثابت ہوئی۔ چنانچہ ڈیکارٹؔ، اسپائنوزاؔ، روسوؔ، دیدروؔ، کانٹؔ، ہیگل، مارکسؔ، اورانیگلز نے جدلیت کو ہیگل کے تصوری خس و خاشک سے پاک کیا اور کہا کہ ” دنیا خواہ وہ قدرتی ہو، تاریخی ہو یا ذہنی، ایک مسلسل عمل ہے، سدا حرکت، تغیر، انقلابی تبدیلی اور ارتقا کے عالم میں” (انیگلز) یعنی حرکت تغیر قانونِ قدرت ہے جو پوری ہستی پر حاوی ہے۔ انھوں نے فلسفہ، تاریخ، اقتصادیات، ادب اور سائنس کی ٹھوس شہادتوں سے ثابت کیا کہ ہرشے کی کمیت کس طرح کیفیت میں کیفیت کمیت میں بدل جاتی ہے اور کس طرح ہرشے کے اندر اس کی نفی پوشیدہ ہوتی ہے جس کے عمل سے ایک نئی شے وجود میں آتی ہے۔ انھوں نے جدلی مادیت کی روشنی میں انسانی تاریخ بالخصوص سرمایہ داری نظام کا بالتفصیل جائزہ لیا اور بتایا کہ اس کا داخلی تضاد۔۔۔ ۔ پیداواری قوتوں اور پیداواری رشتوں کا تضاد۔۔۔۔ کس طرح محنت کش طبقوں کے ہاتھوں جو اِن حالاتِ زیست کی نفی کرتے ہیں بالآخر سماجی انقلاب کا سبب بنے گا۔
پرومی تھیوس کی داستان کے مطابق انسان کی تقدیر ایک دیوتا کی نگاہِ لطف و کرم سے بدلی۔ حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی تقدیر کا خود مالک رہا ہے۔ وہ خود اپنی محنت اور سوجھ بوجھ سے زندگی کے ہر شعبے میں بڑی بڑی انقلابی تبدیلیاں لایا ہے لیکن تقدیریں فقط آرزؤوں کے رنگین محل بنانے سے نہ کبھی بدلی ہیں اورنہ آئندہ بدلیں گی بلکہ زندگی کی تخلیقی قوتوں اور تخریبی قوتوں کے درمیان جو مسلسل پیکار جاری ہے، انسان نے اس پیکار میں شریک ہوکر اپنے معاشرتی تضادات جس حد تک دورکیے اس حد تک وہ اپنے حالاتِ زیست کو بدلنے میں کامیاب ہوا ہے۔
حوالہ جات و حواشی
1۔ شیطان یا ابلیس کا سراغ کتاب پیدائش سے پہلے کہیں نہیں ملتا۔ محققین کا خیال ہے کہ شیطان کا قصہ یہودیوں نے زرتشتیوں کی یزدان واہرمن کی داستان سے اخذکیا۔ عین ممکن ہے کہ یہودی جب شہنشاہ بخت نصر کی اسیری میں بابل گئے اور 48 برس (538۔ 586 ق۔م) تک وہاں رہے اورپھر زرتشتی مذہب کے پیرو شہنشاہ کورش اعظم کے حکم سے آزاد ہو کر یروشلم واپس آئے تو وہ یزدان داہرمن کا قصہ بھی اپنے ہمراہ لائے ہوں۔ توریت میں کوروش کو یہودیوں کا نجات دہندہ کہا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بابل میں رب الارباب مردوک اور قیامت (موت) کے مابین جنگ کا جو دس روزہ تیوہار موسم بہار کی آمد پر رام لیلا کی مانند ہرسال بڑی دھوم سے منایا جاتا تھا۔ یہودیوں نے اس سے اثر لیا ہو۔
2۔ لغوی معنی” دوراندیشی” بھگوت پران، میں ایک شخص پر مانسہ کا ذکرہے جس کے لفظی معنی بھی دوراندیش کے ہیں۔ ان کا نشان سواستیکا ہے جو سورج کی علامت ہے۔
3۔ Z.A. Manferd: A Short History of the World , vol. I, Moscow, 1974, p. 21
4۔ Fredrick Engels, Anti-Duhring, Moscow, 1962, p. 274
5۔ George Thomson, Aeschylus and Athens, London, 1946, p. 317
6۔ ہم نے ڈرامے کے اقتباسات کا لفظی ترجمہ نہیں کیا ہے بلکہ ایس کائی لیس کے مفہوم کو اداکرنے کی کوشش کی ہے۔
7۔ P.B. Shelley, Poetical Works, Oxford, 1956, pp. 204.05
8۔ Benjamin Franklin, The Greek Science, vol.1, Pelican, 1953, p. 26
9۔ Will Durant, Story of Civilization, vol.1, New York, 1954, p. 95
10۔T. Boronoski, The Ascent of Man, London, 1975, p. 124
11۔ Carl Sagan, The Dragons of Eden, New York, 1977, p. 97
12۔Encyclopedia Brittanica, vol. 9, p. 97
13۔ رگ وید (انگریزی ترجمہ)
Ralph T.H. Griffith, The Rigveda, Delhi, 1976, p. 19
14۔ ایضاً۔ ص 60
15۔ Frederick Engels, Anti-Duhring, p. 158.
16۔ V. Gordon Childe, Man Makes Himself, Sondon, 1956, p. 50
17۔رگ وید، بحوالہ سابقہ ،ص۔ 170
18۔ القرآن الحکیم معہ ترجمہ و تفسیر، لاہور و کراچی، تاج کمپنی، ص 9
19۔ تفہیم القرآن، جلد اول، لاہور، 1972ء ص۔ 66
20۔ ایضاً۔ ص 60
21۔ ایضاً۔ ص 65
22۔ ایضاً۔ ص 98
23۔ کتاب مقدس، لاہور، 1949، ص 6
24۔ ایضاً۔ ص 7
25۔ John Burnet: Early Greek Philosophy, New York, 1957, p. 134
26۔ آیونیا مغربی ترکی کے ساحلی خطے کا پرانا نام ہے۔ 90 میل لمبی اور 30 میل چوڑی اس پٹی میں آیون قبیلے 11 سو قبل مسیح میں جنوبی بلقان ( موجودہ یونان) سے آکر آباد ہوئے تھے۔ و ہ بڑے جفاکش اورہوشیار صنعت کار تھے اورتجارت اورجہاز رانی میں بھی بڑے مشاق تھے۔ ان کی کوششوں سے آیونیا جلد ہی مشرقِ وسطیٰ کا سب سے خوش حال اور ترقی یافتہ علاقہ بن گیا۔ چنانچہ یونانی فلسفہ، سائنس، تاریخ ، شاعری اور جمہوریت کا حقیقی مولد آیونیا ہی ہے۔ ہومر، سافو، کلاسیکی حکایات کا مصنف الیسوپ، بابائے تاریخ ہیرو ڈئس اور نیچرل فلسفے کے بانی طالیس، انکسی ماندر، فیثا غورث، زینو فانیس، انکسا غورث اور لکی پس آیونیا ہی کے باشندے تھے۔ 547 ق۔ م میں لینی ہرق لاطیس کی ولادت سے بارہ برس پہلے کوروش اعظم نے آیونیا پر قبضہ کرلیا اور تب آیونیا کا زوال اور ایتھنز کا عروج شروع ہوا۔ سنسکرت کا یونا اور عربی فارسی کا یونان دراصل یہی آیونیا ہے۔
27۔ Lenin, Collected works, vol. 38, Moscow, p. 349
28۔ ہرق لاطیس کے تمام اقوال John Burnet کی کتاب صفحہ 133تا 141 سے لئے گئے ہیں۔
باب ششم: زندگی کی نقش گری
وقت گزرتا رہا۔ سندھ، دجلہ اور نیل کی وادیوں میں تہذیبیں ابھرتی اور مٹتی رہیں۔ ایران، چین اور یونان میں علم و دانش کے چراغ جلتے اور بجھتے رہے۔ رومتہ الکبریٰ کا غلغلہ بلند ہوا اور فضا میں گم ہوگیا۔عباسیوں اور مغلوں کے پرچم بڑے جاہ وجلال سے لہرائے اور سرنگوں ہوگئے۔ مغربی علوم کی روشنی دوردورتکج پھیلی مگرانسانی تہذیب کے اولیں گہواروں میں اندھیرا ہی رہا۔
غار افسانہ بھی ہیں اور تاریخ بھی۔ وہم کی آنکھوں سے دیکھو تو ان غاروں میں ہرسمت موت کے مہیب سائے ناچتے نظرآئیں گے۔آدم خور دیوؤں کی چنگھاڑیں، بیتالوں اوربھوتوں کے خوف ناک قہقہے، چمگادڑوں کے روپ اِدھر اُدھر اڑتی ہوئی بد روحیں اور پچھل پائیاں ۔ منھ سے آگ اگلنے والےاژدھے اورانھیں کے آس پاس بھٹوں میں چھپے ہوئے شیر، بھالو، بھیڑیے، ڈاکو اور راہ زن۔۔۔۔ غرض روایت نے غاروں کو ہر قسم کی تخریبی قوتوں کا مسکن قرار دیا ہے۔ چنانچہ پرانی داستانوں میں غاروں کے ان دہشت ناک باشندوں کے تذکرے جابجا ملتے ہیں۔ وہ غار ہی تھا جس میں کانے دیو نے ہومر کے ہیرو اوڈیسیس کو ساتھیوں سمیت قید کیا تھا اور چالاک اوڈیسیس نے دیو کو نشہ پلایا تھا اور جب دیو مدہوش ہو گیا تھا تو اس کی آنکھ میں لوہے کی گرم سلائی پھیردی تھی۔ اور بھیڑ کے پیٹ سے لپٹ کر غار سے فرار ہوا تھا اور وہ بھی غار تھا جس میں علی بابا کے بھائی کو دولت کی ہوس لے گئی تھی مگر وہ “کھل جا سم سم” کا طلسمی کلمہ بھول گیا تھا اور ڈاکوؤں نے اسے قتل کرکے لاش درخت سے لٹکا دی تھی۔
مگرتاریخ کی آنکھ سے دیکھو تو یہی غار انسان کی قدیم ترین پناہ گاہ نظر آئیں گے جہاں اس نے اپنی 25،30 لاکھ سالہ زندگی کی بیش تر مدت بسر کی ہے۔ وہیں اس نے افزائش نسل کے راز سیکھے، موسم کی سخت گیریوں سے بچنے کے طریقے وضع کیے، آگ جلانے کے تجربے کیے،اوراس طرح تسخیرِ قدرت اور کیمیاوی عمل کے ایک ایسے انقلابی راز سے آگاہ ہوا جس نے آگے چل کر اسے اقلیمِ ارض کی فرماں روائی عطا کی۔ یہ غار اس کے اولین مولدو مسکن بھی تھے اور معبدو مقابر بھی۔ یہاں پہنچ کر وہ تمام ارضی و سماوی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ غار رحمِ مادر سے بھی کسی قدر مشابہ تھے۔ اپنی ظاہری شکل میں بھی اور باطنی کیفیت میں بھی۔ وہی پراسرار تاریکی، وہی پیچ و خم اور امن و عافیت کا وہی احساس۔ مگرانسان کی فراموش طبعی دیکھو کہ لاکھوں سال ان غاروں میں رہنے کے بعد جب اس نے یہ مسکن ترک کیے اور جھونپڑے، گاؤں اور شہر بسائے تو پھر ان غاروں کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ انھیں ایسا بھولا گویا ان سے کبھی وابستہ ہی نہ تھا۔ غاروں کے دہانے، چٹانوں، مٹی کے ملبوں اور جنگلی جھاڑیوں سے پٹ گئے۔ ان کی تلخ اور شیریں یادیں ذہنوں سے محو ہو گئیں اور آنے والی نسلیں اس حقیقت سے بھی واقف نہ رہیں کہ ان کے آباؤ اجداد کبھی غاروں میں رہتے تھے۔
وقت گزرتا رہا۔ سندھ ، دجلہ اور نیل کی وادیوں میں تہذیبیں ابھرتی اور مٹتی رہیں۔ ایران ، چین او ر یونان میں علم و دانش کے چراغ جلتے اور بجھتے رہے۔ رومتہ الکبریٰ کا غلغلہ بلند ہوا اور فضا میں گم ہوگیا۔ عباسیوں اور مغلوں کے پرچم بڑے جا ہ و جلال سے لہرائے اور سرنگوں ہوگئے۔ مغربی علوم کی روشنی دور دورتک پھیلی مگر انسانی تہذیب کے اولیں گہو اروں میں اندھیرا ہی رہا۔
پھریوں ہوا کہ انیسویں صدی کی ایک روشن سہ پہر میں اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کتا ایک لومڑی کا پیچھا کرتے کرتے ایک بھٹ میں گھس گیا۔ کتے کا مالک مارسیلو داساؤ تولا کتے کو نکالنے کی غرض سے بھٹ میں اترا تو پتہ چلا کہ اندر اچھا بڑا غار ہے۔ مارسیلو داساؤتولا کو آثارِ قدیمہ کا شوق تھا۔ اس نے غار کو کھودنا شروع کیا کہ شاید اس کے اندر پرانے زمانے کی کچھ چیزیں مل جائیں۔ ایک دن وہ غار میں اترا تو اس کی کمسن بچی ماریا بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ساؤتولا غار کھودنے میں مصروف ہوگیا اور ماریا پتھر کے ٹکڑوں سے کھیلنے لگی۔ دفعتاً ساؤتولا نے ماریا کی چیخ سنی۔ ” تورو، تورو (بیل بیل) ساؤتولا بچی کی طرف لپکا مگر وہ حیران تھا کہ اس تنگ غار میں بیل کہاں سے آئے۔ وہ ماریا کے پاس پہنچا تو ماریا غار کی چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ساؤتولا کو جب بیل کہیں نظرنہ آئے تو اس نے بچی سے پوچھا اور تب بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا جسے بیس ہزار سال سے کسی انسان نے نہ دیکھا تھا۔ سرخ اور سیاہ رنگ کے بیلوں کی ایک لمبی قطار تھی جو چھت پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ التمیرا کا غار تھا جس میں قدیم حجری انسان نے اپنی فن کاری کا مظاہرہ کیا تھا اور جس کو ساؤ تولا نے 1879ء میں اتفاقاً دیکھ لیا۔
ساؤتولا نے غار کی دیواروں کو غور سے دیکھا تو کہیں رنیگن بھِینسے اور بیل بنے ہوئے تھے، کہیں جنگلی سور، کہیں ہرن اور چیتل، کہیں ہاتھ کے چھاپے۔ شمارکیا تو اس نگار خانے میں جانوروں کی 170 تصویریں تھی۔ ان کے رنگ اس قدر شوق اور روشن تھے گویا یہ تصویریں ابھی کل بنی ہوں۔ ساؤتولا نے اپنے اس حیرت انگیز انکشاف کا اعلان اخباروں میں کیا اور آثارِ قدیمہ کے ماہروں سے درخواست کی کہ وہ آکر غار کا مطالعہ کریں لیکن دانایانِ مغرب نے ساؤتولا کا مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا یہ اسکول کے لڑکوں کا کھلواڑ ہے۔ کسی نے کہا مقامی چرواہوں نے اپنی اکتاہٹ دور کرنے کی خاطر مویشیوں کی تصویریں بنائی ہوں گی بعضوں نے غریب ساؤ تولا کو فریبی اور جعل ساز کہنے سے بھی دریغ نہ کیا اور یہ الزام لگایا کہ ساؤ تولا نے میڈرڈ کے کسی مصور سے ساز باز کیا ہوگا۔ تجارت اور شہرت کی خاطر۔ غرض کہ نہ حکومت نے ان دیواری تصویروں کی طرف توجہ کی اورنہ ماہرینِ فن نے اس غار کو در خور اعتنا سمجھا۔ بے چارہ ساؤ تولا خاموش ہورہا۔
یہ درست ہے کہ التمیرا کی دریافت سے بہت پہلے آثارِ قدیمہ کے ماہروں کو عہد قدیم کے پتھر کے اوزار، ہاتھی دانت کے ٹکڑوں پر کھدے ہوئے نقوش اور سیپ اور ہڈی کے زیورات دست یاب ہو چکے تھے۔ مثلاً بروئِیلے (Brouillet) نامی ایک فرانسیسی ماہر کو سوینی (Savigny) کے مقام پر ہڈی کا ایک ٹکڑا انیسویں صدی کی ابتدا میں ملاتھا۔ اس ٹکڑے پر دوہرن کندہ تھے۔ کلونی Cluny کے عجائب گھر نے 1851ء میں ہڈی کے اس منقوش ٹکڑے کو حاصل کرلیا تھا مگرکسی کو اس کی قدامت پر غور کرنے توفیق نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح 1833ء میں میئر Mayor نامی ایک انگریز محقق کو ہڈی کی ایک چھڑی ملی تھی جس کے ایک رخ پر ایک گھوڑا کندہ تھا اور دوسری طرف ایک پودا بنا تھا۔ 1852ء میں آری ناک (فرانس) کے مقام پر ہڈیوں کا ایک ہار اور ہڈی اور ہاتھی دانت کے چند زیورات بھی دریافت ہوئے تھے۔ ایڈورڈلارتیت کو مسات Massat کے مقام پر بارہ سنگھے کی ہڈی پر ریچھ کا سر کھدا ہوا ملا تھا اور 1863ء میں اسے وزیر ندی کی وادی میں جو پیرس سے ڈھائی سو میل جنوب مغرب میں واقع ہے متعدد چھوٹی چھوٹی چیزیں آلات اور و اوزار دست یاب ہوئے تھے۔ چنانچہ 1864ء میں اس نے ان دریافتوں پر ایک مختصر سا رسالہ فرانسیسی زبان میں شائع بھی کیا تھا۔ اسی سال کو مارلین (فرانس) کے مقام پر میمتھ کا ایک دانت ملا تھا جس پر نہایت باریک خطوں میں اس ناپید جانور کی شکل کندہ تھی۔
یہ تو خیر چھوٹی چھوٹی منقولہ اشیا تھیں جن سے قدیم انسان کی فن کاری کا کوئی واضح تصور قائم کرنا قدرے دشوار تھا مگر حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ التمیرا اسے پیش تر دنیا کے مختلف گوشوں میں چٹانوں پر اور غاروں میں جو تصویریں اور نقوش ملے ان کی تاریخی اہمیت کو بھی نظر اندزز کردیا گیا۔ مثلاً 1837ء میں سرجارج گرے نے آسٹریلیا کی سیاحت کے دوران اقلید سی انداز کی بڑی پراسرار اور رنگین تصویریں کمبر لے کی کوہستانی پناہ گاہوں میں دریافت کی تھیں۔ 1848ء میں جھیل اور نیگا (روس) کے مشرقی ساحل پر غاروں میں متعدد نقوش دیواروں پر کھدے ہوئے ملے تھے۔ یہ وہیل مچھلی، بارہ سنگھے اور ایلک کے نقوش تھے۔ انھیں دنوں سٹو (Stowe) کو جنوبی افریقہ کی چٹانوں پر اقلید سی انداز کی مصوری کے چند نادر نمونے نظر آئے تھے اور اس نے ان کو بڑی محنت سے نقل کرلیا تھا مگر یہ نقش و نگار تہذیب کے اصل مرکز یعنی یورپ سے بہت دور پس ماندہ علاقوں میں پائے گئے تھے۔ ان کو نہ تو ایک رشتے میں جوڑا جا سکا تھا اور نہ تہذیب انسانی کی ارتقائی تاریخ مرتب کرنے میں ان سے مدد مل سکتی تھی۔ کم سے کم اس دور کے دانش وروں کا یہی خیال تھا۔
ساؤلا تولا کے دس سال بعد موسیو شیرون (Cheron) نے شیبوت (Chabot) (فرانس) کے غار کی تفصیلات شائع کیں، اس غار کا سراغ انھوں نے کئی سال پیش تر لگایا تھا، لیکن ان کا حشر بھی وہی ہوا جو ساؤلا تولا اکا ہو چکا تھا۔
انیسویں صدی کے اختتام کو ابھی پانچ سال باقی تھے کہ ایک اور مصور غارلا موتھ (فرانس) کے مقام پر دریافت ہوا، وہ بھی اتفاقاً۔ ایک کاشت کار اپنے مویشیوں کے لیے ایک پہاڑی پناہ گاہ صاف کررہا تھا کہ اچانک غار کا دہانہ کھل گیا۔ گاؤں میں یہ خبر پھیلی تو چند نڈر لڑکوں نے غار میں اُترنے کی ٹھانی۔ انھوں نے موم بتیاں لیں اور غار میں گھس گئے۔ واپس آئے تو اُنھوں نے بتایا کہ غار کی دیواروں پر جا بجا گھوڑے، بیل، بارہ سنگھے، گینڈے، بیسن اور بیسن سے بھی بڑے بڑے جانوروں کی تصویریں بنی ہیں۔ چند سال بعد اسی غار کے نواح میں ایک پورا نگار خانہ ملا جس میں دو سو دیواری تصویریں موجود تھیں۔ یہ فونت دے گام کا مشہور غارتھا جو ستمبر 1901ء میں دریافت ہوا۔ اسی دوران میں مشرقی اسپین کی کھلی چٹانوں پر رنگین تصویروں کے آثار دیکھے گئے۔ ان تصویروں میں غلبہ جانوروں کا تھا مگر ہیئت میں یہ تصویریں التمیرا اور فونت دے گام سے مختلف تھیں لیکن کتابی علم کا غرور اور پندار کی بے اعتنائی کہیے کہ دانش و ران روشن نشانیوں کو بھی جھٹلانے پر اصرار کرتے رہے۔ چنانچہ فرانس میں آثارِ قدیمہ کے ماہرین کی جو بین الاقوامی کانفرنس ہوئی اس میں ان جدید دریافتوں پر بحث کرنے کی بھی اجازت نہ ملی۔
مگر حقیقت سے بہت دن تک چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔ اسے دیر سویر ماننا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ یکم اکتوبر 1902ء کو ماہروں کا ایک گروہ ایبے بروئیل کے اصرار پر پہلی بار التمیرا کے غار میں داخل ہوا۔ اس مہم کا ذکر کرتے ہئوے ایبے بروئیل لکھتا ہے کہ روشنی کےے لیے ہمارے پاس فقط موم بتیاں تھیں مگر اس نیم تاریک ماحول میں بھی ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ غار میں نمی تھی اس لیے سقفی تصویروں کا چربہ نہیں لیا جا سکا تھا کیوں کہ رنگ گیلا تھا اور کاغذ پر چپک جاتا تھا۔ چربہ لینے کے معنی ان تصویروں کو ضائع کرنے کے ہوئے لہٰذا اپیبے بروئیل نے ان کو ہو بہو نقل کرنے کا بیڑہ اٹھایا۔ ” میں روزانہ آٹھ گھنٹے زمین پر پیٹھ کے بل لیٹ کر ان تصویروں کو نقل کرتا جو چھت پر بنی ہوئی تھیں”۔ ایبے بروئیل نےیہ کام تین ہفتے میں مکمل کرلیا مگر کوئی پبلشر التمیرا کے اس رنگین مرقعے کو چھاپنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بالآخر ایبے بروئیل نے پرائیویٹ امداد سے التمیرا پر ایک مصور کتاب 1908ء میں شائع کی۔
ان حجری فن پاروں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایبے بروئیل جیسا دُھن کا پکا اور لگن کا سچا فن کارمل گیا۔ ایبے بروئیل نے اپنی زندگی حجری فن پاروں کی نقل اور تفتیش و تحقیق کے لیے وقف کردی۔ چنانچہ آج ایبے بروئیل کی نقل کی ہوئی تصویروں کا اتنا بڑا ذخیرہ فرانس میں موجود ہے کہ اس سے کئی دفتر تیار ہو سکتے ہیں۔
اب چراغ سے چراغ ملنے لگا۔ غاروں کی دریافت نے ایک مہم کی شکل اختیار کرلی۔ چنانچہ ہر سال ایک نہ ایک مصور غار کا سراغ ملتا۔ کبھی اسپین اور فرانس میں کبھی جرمنی اوراٹلی میں، کبھی روس اور چیکو سلواکیہ میں، کبھی سویڈن اور ناروے میں۔ آخری غارہ وہ ہے جو Baumed Dullins کے مقام پر مارچ 1951ء میں دریافت ہوا۔ اس سے پیش تر ایک نہایت اہم غار لاسکا میں ستمبر 1940ء میں دو لڑکوں نے دریافت کیا تھا۔
یوں تو قدیم حجری دور کے یہ فن پارے یورپ میں التمیرا سے جھیل بیکال تک اور فن ہاگن (ناروے) سے کیڈز (اسپین) تک بکھرے ہوئے ہیں مگر اس دور کے فن کا سب سے بڑا مرکز جنوب مغربی فرانس ہے۔ وہاں اب تک ستر غار دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ غار دو منطقوں میں واقع ہیں۔ ایک وہ پہاڑی علاقہ ہے جو دریائے دوردون کی وادی میں ہے اور دوسرا فرانس کی جنوبی سرحد پر کوہِ پیر نیز میں۔ ان کے علاوہ اسپین کے شمال مغربی، مشرقی اور جنوبی علاقوں میں اس عہد کے کم و بیش چالیس غار اور کوہستانی پناہ گاہیں اب تک مل چکی ہیں۔ پھر چٹانوں پر اور کھوہوں کے اندر رنگین تصویروں اور کندہ نقوش کا وہ طویل سلسلہ ہے جو اسپین سے شروع ہوتا ہے۔ سمندر پار کر کے مراکش اور الجزائر سے گزرتا ہوا صحرائے اعظم کو عبور کرتا وسطی مشرقی اور جنوبی افریقہ میں اپنے نشان چھوڑتا کیپ ٹاؤن پر ختم ہوتا ہے۔ یہ نقوش اور تصویریں گو قدم حجری دَور سے تعلق رکھتی ہیں مگر تکنیک اور ہیئت کے اعتبار سے یورپ کے ان فن پاروں سے مختلف ہیں جن کا ذکر ہم کررہے ہیں اس لیے اُن پر الگ بحث کی جائے گی۔ آسٹریلیا کی حجری دَور کی تصویریں افریقی تصویروں کے علاوہ ہیں البتہ وہ ٹیکنیک کے لحاظ سے آپس میں بڑی مشابہت رکھتی ہیں۔
سو ڈیڑھ سو سال پیش تر تک اس زمین کے بسنے والوں اور ان کے ماضی بعید کے بارے میں ہماری معلومات بہت ناقص اور محدود ہیں۔ عہدِ قدیم زمین کے سینے میں دفن تھا۔ ہمیں ان دفینوں کی خبر تھی اور نہ ان کی تلاش و تحقیق کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود تھا۔ ہماری آگہی کا سارا اثاثہ چند مذہبی کتابیں تھیں یا وہ لوک کہانیاں جو پرانی قوموں میں مدت سے رائج ہیں۔ انھیں روایتوں اور کتابوں کی روشنی میں انسان اور اس کے قدیم معاشرے کی ابتدا کا سراغ لگایا جاتا تھا۔ چنانچہ سترھویں صدی کے ایک پادری اشر نے انجیل کی کتاب پیدائش کی مدد سے یہ ثابت کیا تھا کہ ظہور آدم کا واقعہ 4004 قبلِ مسیح میں پیش آیا تھا اور دانایان مغرب نے پادری اُشرکی اس حساب دانی کو بہت سراہا تھا لیکن انیسویں صدی عیسوی میں جب سائنس نے ترقی کی اور نئے نئے علوم مثلاً علم الافلاک، علم الارض اور علم لحیوان کو فروغ ہوا تو ان پرانے عقیدوں کی صداقت خطرے میں پڑگئی۔ سائنس دان زمین اور زندگی کی عمریں متعین کرنے لگے۔ ارتقائے حیات کے نظریے بنانے لگے۔ انھوں نے زمین کی تہوں سے بے شمار ایسی چیزیں برآمد کیں جن سے ان کے دعوؤں کی تصدیق ہوتی تھی۔ انھوں نے ان معدوم جانوروں کے ڈھانچے بھی ڈھونڈ نکالے جو لاکھوں برس گزرے زمین پر موجود تھے اور جب 1891ء میں پروفیسر دوبائے کو جاوا میں قدیم انسان کی چار لاکھ برس پرانی ایک کھوپڑی دستیاب ہوئی تو پادری اُشرکا حساب بالکل ہی غلط ثابت ہوگیا۔ اس کے بعد 1907ء میں ہائیڈل برگ (جرمنی) کے مقام پر آدمی کا ایک جبڑا ملا جو پانچ لاکھ برس پرانا تھا اور 1927ء میں پیکنگ (چین) کے نواح میں ایک غار میں آدمیوں کے 45 ڈھانچے نکلے جو چار لاکھ برس پرانے تھے اور اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کم سے کم پندرہ لاکھ برس سے اس کرہ ارض پر آباد تھے۔
محققین نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس پندرہ لاکھ برس کے عرصے میں انسان کے رہن سہن، رسم و رواج، آلات و اوزار، عقاید اور عادات اور فکر و فن میں وقتاً فوقتاً نمایاں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ انسانی تہذیب کوئی ساکت اور جامد شے نہیں ہے جو ایک مقام پر ٹھہری رہتی ہو بلکہ وہ ایک تغیر پذیر اور فعال حقیقت ہے جس نے اب تک ارتقا کے مختلف مدارج طے کیے ہیں اور یہ عمل بدستور جاری ہے۔ ان تبدیلیوں کا باعث وہ آلات و اوزار ہیں جن کو انسان اپنی اپنی سماجی ضرورتوں کے تحت خود بناتا رہتا ہے۔ دراصل تہذیبِ انسانی کے مختلف عہدوں کی شناخت انھیں آلات و اوزار سے ہوتی ہے چنانچہ 1836ء میں کرسٹین ٹامیسن (Christian Toomsen) نامی ایک فرانسیسی عالم نے آلات و اوزار کے فرق کے پیشِ نظر انسانی تہذیب کے تین بنیادی عہد متعین کیے تھے۔
1۔ پتھر کا زمانہ ، جب آلات و اوزار پتھر، لکڑی یا ہڈی کے ہوتے تھے۔
2۔ دھات کا زمانہ، جب کہ آلات و اوزار (تانبے اور ٹن کو ملا کر) کانسے کے ہوتے تھے۔
3۔ لوہے کا زمانہ، جو ایک ہزار قبلِ مسیح کے قریب شروع ہوا اور ہنوز جاری ہے۔
پتھر کا زمانہ اندازً پانچ لاکھ قبلِ مسیح سے پانچ ہزار قبلِ مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کو زمانہ قبل از تاریخ بھی کہتے ہیں۔
قدیم حجری دور کے جو آثار اب تک ملے ہیں ان سے یہی اندازہ ہوتاہے کہ اس زمانے کا انسان تقاشی، مصوری، مجسمہ سازی اور موسیقی سے واقف تھا۔ یورپ کے غاروں میں حجری دورکے سب سے قدیم فن پارے 30،40 ہزار برس پرانے ہیں۔ ان کے عروج و کمال کا زمانہ مادی لانی دور کا وسطی عہد ہے جس کے آخر تک آتے آتے یہ فن ختم ہوگیا۔ کیوں کہ جن لوگوں نے یہ فن پارے تخلیق کیے تھے وہ معدوم ہوگئے یا ان علاقوں سے مستقل طورپر ہجرت کرکے کہیں اور آباد ہوگئے۔
قدیم حجری دور کا ماحول سخت برفانی تھا س لیے اس دور کو برفانی دور بھی کہتے ہیں۔ اس وقت یورپ کا تمام وسطی اور شمالی علاقہ ( برطانیہ، جرمنی پولینڈ، ناروے، سویڈن اور شمالی روس) برف کی چادروں سے ڈھکا ہوا تھا اور کسی جانور یا انسان کا وہاں گزر نہ تھا۔
البتہ اسپین، فرانس، اٹلی، جزیرہ نما بلقان اور دریائے وولگا کی وادی برف سے نسبتاً محفوظ تھی۔ سردیوں میں گو اس خطے میں بھی شدید برف باری ہوتی تھی اور سرد ہواؤں کے طوفان آتے تھے لیکن شمالی یورپ کے مقابلے میں وہاں کا موسم معتدل تھا۔ اس خطے میں اونچے اونچے درختوں کے جنگل تھے۔ پھل دار جھاڑیاں تھیں،دریا اور میدان تھے اورگھاس تھی لہٰذا میتمہ، بیسن، ریچھ، بالدار گینڈے، بارہ سنگھے، جنگلی بیل، گھوڑے اورہرن، غرض اس عہد کے تمام جانور اسی خطے میں رہتے تھے اوران کے بڑے بڑے غول خوراک کی تلاش میں دور دور تک نکل جاتے تھے۔ اس وقت کے انسان کا دارو مدار انھیں جانوروں کے شکار پر تھا اس لیے انسانی قبیلے بھی جانوروں کے تعاقب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔
انسانی قبیلے خانہ بدوشی کی یہ زندگی غاروں یا کوہستانی پناہ گاہوں میں گزارتے تھے البتہ میدانی علاقوں میں وہ اپنے رہنے کے لیے زمین میں گڑھا کھود لیتے تھے اور گڑھے کے اوپر گھاس پھوس کی چھت ڈال لیتے تھے۔ ان میں دو جھونپڑیوں کے آثار جنوب مشرقی یورپ میں ملے ہیں۔ جنگلی جانوروں ان کا کھاناپینا اور اوڑھنا بچھونا تھے۔ ان جانوروں کا گوشت وہ بطور غذا استعمال کرتے تھے۔ چربی سے چراغ جلاتے تھے۔ کھال اوڑھی اور بچھائی جاتی تھی۔ موٹی ہڈیوں سے شکار کے اوزار مثلاً نیزے کی انیاں اور تیروں کے پھل بنتے تھے اور پتلی ہڈیوں سے سینے کی سوئیاں، انتڑیوں اور نسو سے تاگے اور رسّی کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ لوگ آگ کے استعمال سے واقف ہوچکے تھے اور شکار کو بھون کر کھاتے تھے۔
برفانی دور کے ان شکار پیشہ قبیلوں کے آلات اور اوزار لکڑی، پتھر یا ہڈی کے ہوتے تھے۔ ہتھوڑے، کلہاڑیاں، نیزے، چاقو، سوئیاں وغیرہ سب انھیں چیزوں سے بنائی جاتی تھیں۔ شکار کے لیے بڑے بڑے بلم یا لاٹھیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ ان کے سرے پر پتھر یا ہڈی کی تیز اور نکیلی انی لگی ہوتی تھی۔ ان ہتھیاروں کی مار زیادہ دور تک نہیں تھی لہٰذا شکار یوں کو چھپ چھپا کر جانوروں کے بہت قریب تک جانا پڑتا تھا۔ مگر میمتھ، ہاتھی اور بیسن جیسے دیو پیکر جانوروں کو بھالوں یا لاٹھیوں سے مارنا ممکن نہ تھا۔ ان کے قریب جانے میں جان کا خطرہ بھی تھا اس لیے ان بڑے جانوروں کو ہانکا کر کے کسی گڑھے یا کھڈ کی سمت لے جاتے تھے جب شکار گڑھے میں گر پڑتا تھا تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کردیتے تھے۔ فرانس میں ایسے کئی کھڈ ملے ہیں جن میں ہزاروں بیسنوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ لیسکا کے غار میں ایک مقام پر اس طرزِ شکار کی باقاعدہ منظر نگاری بھی کی گئی ہے۔ اس منظر میں چند جنگلی گھوڑے ایک گڑھے میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ گھوڑوں کے درمیان چٹان میں جو قدرتی نشیب موجود ہے اس کو گڑھے کی علامت کے طورپر استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ تصویر کو دیکھنے سے یہی تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ عاجز اور پریشان گھوڑے واقعی گڑھے میں چھلانگ لگارہے ہیں۔ بعض خطوں کے لوگ بھالے کو دور دور تک پھینکنے کے لیے نیزہ انداز آلے بھی بنانے لگے تھے۔ جنوبی اسپین اور افریقہ کے قدیم حجری انسان نے تیر کمان بھی بنا لی تھی۔
برفانی دور کا انسان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ دراصل ایک گھرانا ہوتا تھا جو اجتماعی زندگی گزارتا تھا۔ آلات و اوزار مشترکہ ہوتے تھے اور شکار میں جو کچھ ملتا تھا اسے بھی آپس میں بانٹ کر کھالیتے تھے۔ قبیلے کے ہر فرد کا تحفظ پورے قبیلے کا فرض ہوتا تھا۔ قبیلے کے اندر تقسیم کار کا طریقہ رائج تھا۔ مرد شکار کرتے تھے، عورتیں ساگ پات جنگلی پھل اور جڑیں وغیرہ اکٹھا کرتی تھیں۔ یہ چیزیں خوراک کے کام آتی تھیں۔ شکار میں بھی عورتیں ہانکے می شریک ہوتی تھیں۔ حصول غذا کے علاوہ عورتوں کا کام بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کپڑے سینا اور غار کو صاف ستھرا رکھنا ہوتا تھا۔ مردوں کا بنیادی پیشہ یوں تو فقط ایک ہی تھا یعنی شکار مگر ان میں بھی تقسیم کارپائی جاتی تھی۔ قبیلے کے ہر فرد کو پتھر کاٹنے، آلات و اوزار بنانے، نشانہ لگانے اور شکار کرنے کا فن سیکھنا پڑتا تھا لیکن بعضوں کا نشانہ قدرتی طورپر اچھا ہوتا تھا۔ بعضوں میں صناع بننے کی صلا حیت دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی۔ بعضوں کو مصوری یا کندہ کاری کا شوق ہوتا تھا چنانچہ اسی ہنر مندی، صلاحیت اور شوق کے مطابق ان کے کاموں کی تقسیم بھی ہوتی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اپنے فن کے ماہر بن جاتے تھے۔ مصوری سے ملا ہوا سحر کا فن تھا۔ یہ فن ان کی شکار پیشہ زندگی کا لازمی جز تھا اوراس کی اہمیت شکار سے کم نہ تھی۔ ساحر قبیلے کا روحانی پیشوا ہوتا تھا۔ وہ شکار کی تصویریں بناتا اور سحر کی رسمیں ادا کرتا تھا۔ اس کے عوض قبیلہ اس کی ضروریاتِ زندگی کی کفالت کرتا تھا۔ خود شکاریوں کے بھی درجے ہوتے تھے۔ ان میں بعض ماہر شکاری ہوتے اور بعض بالکل مبتدی جن کو ہانککا کرنے کا کام سپرد کیا جاتا تھا۔ شکار کے بعد شکار کی تقسیم ہوتی تھی۔ گوشت عورتوں کو دیا جاتا تھا اور انتڑیاں، کھال، نسیں اور ہڈیاں الگ کر کے ان لوگوں میں تقسیم کردی جاتی تھیں، جو ان چیزوں سے سامان بناتے تھے۔
غاروں کے اندر جو مدفون ڈھانچے ملے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے برفانی دور کا انسان اپنے مردوں کو باقاعدہ قبر میں دفن کرتا تھا۔ زمین سے پودوں اور بوٹوں کو اگتا دیکھ کر شاید اسے یہ خیال گزرا ہو کہ اگر مردے کو زمین میں دفن کردیا جائے وہ بھی اوپر آجائے گا۔ یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ قبر کی شکل عورت کے اسی عضو بدن سے بہت مشابہ ہوتی ہے جہاں سے بچہ نکلتا ہے۔ چنانچہ برفانی دور کا انسان اپنے مردے کے گھٹنوں کو پیٹ سے ملا دیتا تھا اور اس طرح اس کی پوزیشن قریب قریب وہی ہو جاتی تھی جو بچے کی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ لاش کے سرکے نیچے پتھر کا تکیہ رکھ دیا دیا جاتا تھا اور قریب ہی گوشت کے ٹکڑے، ہڈیاں اور شکاری آلات و اوزار قرینے سے سجا دیے جاتے تھے۔ تب قبر کا منھ بند کر کے اوپر پتھر کی سل رکھ دی جاتی تھی۔ یہ قبریں آباد غاروں میں بنائی جاتی تھیں۔ بعض قبریں تو چولھے کے بالکل پاس ہی ملی ہیں۔ شاید لوگوں کا عقیدہ ہو کہ آگ کی گرمی سے مردے کے ٹھنڈے جسم کو زندگی کی حرارت دوبارہ حاصل ہو جائے گی۔ حیات اور حرارت میں جو رشتہ ہے اس سے وہ لوگ پوری طرح آگاہ تو نہ تھے مگر اس رشتے کا ایک مبہم سا تصور ان میں ضرور موجود تھا ۔ البتہ وہ حرارت کو زندگی کی علامت نہیں بلکہ اس کی علت سمجھتے تھے۔ گوان کے مردے کبھی نیند سے نہ جاگے اور چولھے کی گرمی نے کبھی زندگی کی حرارت نہ بخشی مگر رسم و رواج کی آہنی زنجیریں بڑی مشکل سے ٹوٹتی ہیں۔
قدیم حجری انسان ہنوز مذہب کے تصور سے آشنا نہ ہوا تھا۔ وہ کسی مافوق القدرت طاقت یا طاقتوں کو نہیں مانتا تھا اور نہ کسی دیوی ، دیوتا کی پرستش کرتا تھا البتہ سحر پر اس کا عقیدہ بہت پختہ تھا۔ مذہب اور سحر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہب کا محرک قدرت کی اطاعت اور خوشنودی کا جذبہ ہے۔ اس کے برعکس سحر کا محرک تسخیر قدرت کا جذبہ ہے۔ سحر دراصل سائنس کی بالکل ابتدائی شکل تھی اسی لیے فریزر نے سحر کو ” ساقط سائنس اور ناقص آرٹ” سے تعبیر کیا ہے۔
علمائے آثا ر کا خیال ہے کہ برفانی دور کا انسان کوئی زبان ضرور بولتا تھا البتہ اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ زبان کیا تھی۔ آیا تمام قبیلے ایک ہی بولی بولتے تھے یا مختلف خطوں میں مختلف بولیاں بولی جاتی تھیں۔ غاروں میں جو آثار ملے ہیں ان سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ قدیم انسان نقش گری، مصوری، مجسمہ سازی، موسیقی اور رقص کے فن سے آگاہ تھا لیکن ایسی کوئی شہادت اب تک نہیں ملی ہے جس سے اس کی زبان کے بارے میں کوئی بات یقین سے کہی جا سکتی ہو۔
برفانی دور میں شرح اموات بہت زیادہ تھی ، خصوصاً شیر خوار بچے بڑی تعداد میں فوت ہو جاتے تھے۔۔۔۔ بیماریوں میں سب سے عام بیماری گٹھیا کی تھی۔ لوگ طب اور جراحی کے فن سے واقف نہ تھے لیکن آدمیوں کے بعض ڈھانچھے ایسے ملے ہیں جن کے پاؤں کی ہڈیوں پر عمل جراحی کے آثار نظر آتے ہیں۔ شاید ان شکاریوں کے پاؤں شکار میں ٹوٹے ہوں اورپھر ان کو کسی طرح جوڑ گیا ہو۔
یہ ہے ایک دُھندلا سا خاکہ قدیم حجری دور کے انسان اور اس کے ماحول اور معاشرے کا مگر جب ہم اس عہد کے غاروں کے رنگین نقش و نگار اور حسین مجسموں کو دیکھتے ہیں تو اس شکاری انسان کی صناعی ، ہنر مندی، فن کاری اور ذہانت پر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ قدیم حجری دور کے بعد آج تک دنیا کی کسی قوم نے کسی ملک اور کسی عہد میں بھی جنگلی جانوروں کی حسی کیفیات سے لبریز اتنی جان دار اور متحرک، اتنی خوش رنگ اور خوش آہنگ، اتنی موزوں اور متناسب تصویریں نہیں بنائیں۔ قدیم حجری دور کا انسان اپنے فن میں یکتا و بے مثال ہے کیوں کہ کسی دوسرے دور میں انسان کو جانوروں سے اتنا گہرا لگاؤ نہیں رہا اور نہ جانوروں کے کردار، مزاج، عادات و اطوار اور جسم کے مطالعے پر ا س کی زندگی کا دارو مدار ہوا۔
قدیم حجری دور کے فن کار کی عظمت کا ا س سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ دورِ جدید کے کتنے ہی عظیم فن کار اس کی نقالی پر ہی اپنی شہرت کے پرچم اڑاتے ہیں۔
آئیے اب قدیم حجری دور کے گمنام فن کاروں کے ایک زمین دوز نگارخانے کی سیر کریں۔ یہ نگار خانہ لاسکا کے غار میں ہے۔ اب تک جنتے غار دریافت ہوئے ہیں لاسکا کا غار ان سب میں ممتاز ہے۔ اس کی رنگین تصویروں پر موسمی تغیرات کا بہت کم اثر پڑا ہے۔ یہ تصویریں ابھی تک اپنی اصلی حالت پر ہیں اوران کے رنگ کی آب و تاب میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ لاسکا کا غار دریائے وزیر کے شمالی ساحل پر ایک گھنے جنگل کے اندر واقع ہے۔ وہاں کوئی آبادی نہیں ہے البتہ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹا سا فرانسیسی گاؤں ہے۔ التمیرا کی مانند یہ غار بھی اتفاقیہ طورپر دریافت ہوا اور وہ بھی 1940ء میں ۔ ہوا یوں کہ نواحی مدرسے کے چار پانچ لڑکے جنگل میں کھیل رہے تھے۔ ان کا کتا ایک گڑھے میں جو کافی گہرا تھا گر پڑا۔ لڑکے کتے کو نکالنے گئے تو انھیں غار کا دہانہ نظر آیا۔ تلاش و جستجو کی یہ عمر انھیں غار میں لے گئی مگر دہانہ اتنا تنگ تھا کہ لڑکوں کو پیٹ کے بل رینگنا پڑا۔ ملبے کے ڈھیر سے رینگتے ہوئے وہ داخل ہوئے داہنی جانب بیس فٹ کی گہرائی پر انھیں ایک بڑا سا ہال ملا جو بیضاوی شکل کا تھا۔ سو فٹ لمبا، 33 فٹ چوڑا اور 20 فٹ اونچا۔ اس ہال کی چھت اور دیواریں بیلوں، گھوڑوں اور ہرنوں کی بڑی بڑی رنگین تصویروں سے آراستہ تھیں۔ لڑکوں نے یہ ماجرا اپنے استاد موسیو لاوالؔ سےس بیان کیا انھوں نے ایبے بروئیل کو خبردی۔ ایبے بروئیل نے غار کا معائنہ کیا۔ اسے آری ناسی دور کا شاہ کار قرار دیا اور اس طرح مہذب دنیا کو چالیس ہزار برس پرانا ایک نایاب وفینہ ہاتھ آیا۔
لاسکا کے ہال میں داخل ہوتے ہی پہلی تصویر ایک سیاہ گھوڑے کی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب جانور بنا ہے جس کے دو متوازی سینگ آگے کو نکلے ہوئے ہیں۔ پیٹ پھولا ہوا ہے اورجسم پر گول گول نشان ہیں۔ پھر چند بہت بڑے بڑے بیل ہیں جن میں سے چار اب تک محفوظ ہیں۔ ان کی لمبائی چار تا چھ گز ہے۔ دو بیل جن کے خاکے سیاہ لکیروں سے بنے ہیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں اوران کے درمیانی خالی جگہ میں پانچ سرخ، سیاہ اور زرد رنگ کے ہرن بنے ہیں۔ پہلے بیل کے اوپر لال رنگ کا ایک بڑا سا گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ اس کے کھر اور ایال کالے ہیں دوسرے بیل کے عقبی حصے میں لال رنگ کی ایک گائے بھی ہے جو چر رہی ہے۔ بیلوں کے درمیان بالائی حصے میں ایک اور لال گھوڑا ہے جس کی تھوتھنی دوسرے بیل کے سینگوں کے اندر ہے البتہ اس کے پاؤں غائب ہیں۔ بظاہر یہ چند جانوروں کی تصویریں ہیں مگر غور سے دیکھا جائے تو ان کی ایمائیت واضح ہو جاتی ہے اوران میں ترتیب و آہنگ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ بیل یوں تو بڑے مہیب اور قوی ہیکل ہیں لیکن مصور نے انھیں ساکت اور جامد بنا دیا ہے۔ وہ نہ حملہ کرسکتے ہیں اورنہ حرکت۔۔۔۔ وہ بالکل بے بس گم سم کھڑے ہیں، کیوں کہ وہ سحر زدہ ہیں۔ ان کے جسم پر بھالے کے چھوٹے چھوٹے نشان ہیں۔ اس کے برعکس گھوڑے بہت مگن دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سرپٹ دوڑ رہے ہیں، اور بارہ سنگھوں کا نڈرپن دیکھو کہ وہ ان خون خوار بیلوں کے درمیان بڑے بے فکری سے کھڑے چہلیں کررہے ہیں۔ رنگ زندگی کی علامت ہے اسی لیے گھوڑے اور بارہ سنگھے رنگین ہیں اور بیلوں کو اس سے محروم کردیا گیا ہے۔ داہنی جانب والے بیل کی ناک سے تو خون بھی نکل رہا ہے۔
ہال کے عقبی حصے میں چھت بہت نیچی ہو جاتی ہے اور زمین کی ڈھلوان بڑھ جاتی ہے۔ وہاں سے ہم ایک تنگ راستے میں داخل ہوتے ہیں تو عین دہانے کی چھت پر ایک ہرن اور اس کے ہم جنس دوسرے جانوروں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ آگے بڑھیے تو چھت پر لال رنگ کی نہایت حسین گائیں اور مختلف نسلوں کے چھوٹے بڑے بہ کثرت گھوڑے بنے ہیں، گایوں کی نازک اور حساس تھوتھنیاں اور پتلی پتلی سڈول سینگیں اپنی ساخت میں بڑے ہال کے بیلوں سے مختلف ہیں، یہاں پہنچ کر راستہ اور تنگ ہو جاتا ہے مگر اس تنگی سے بھی فن کار نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک دوڑتی ہوئی گائے کی تصویر اس انداز سے بنائی ہے کہ اس کے اگلے پاؤں دہانے کے ایک سرے پر ہیں اور پچھلے پاؤں دوسرے سرے پر۔ درمیان میں چھت کے نصف دائرے پر گائے کا پورا جسم پھیلا ہوا ہے اور یوں محسوس ہورہا ہے کہ گویا یہ گائے خلا میں چھلانگ لگا رہی ہے۔ اورآگے بڑھو تو ایک بے حد لمبی چوڑی گائے ایک جالی نما نشان کی جانب جست لگا رہی ہے ۔ یہ نشان مستطیل ہے اور اس میں تین متوازی لکیریں بھی ہیں۔
یہ نشان یا تو ہم رنگ زمین جال کی علامت ہے جس میں گائے کو پھنسا یا جارہا ہے یا سحر کی ۔ اور آگے بڑھو تو دو جنگلی گدھے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک حاملہ ہے آخرمیں چھت نیچی ہونے لگتی ہے اور موڑ آجاتا ہے۔ وہاں بھورے رنگ کا ایک گھوڑا ایک گڑھے میں گرتا نظر آتا ہے۔ اس کے چاروں پاؤں ہوا میں ہیں۔ یہاں چٹانوں میں جو قدرتی نشیب ہے فن کارنے اس سے گڑھے کا کام لیا ہے۔
غار کے دوسرے گوشے میں پتھر پر کندہ کاری کے بہ کثرت نشان ملیں گے۔ یہ تصویریں ایک کے اوپر ایک کھدی ہیں شاید یہ جگہ نو آموز فن کاروں کی مشق کے لیے تھی۔ یہاں کسی جگہ فقط کھربنے ہیں، کہیں دم، کہیں سر، کہیں کوہان مگران میں بڑی صفائی اور روانی پائی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ خاکے ہاتھ کی ایک ہی جنبش سے بنے ہیں۔ ایک اورگوشے میں پتوں والی ایک بیل کندہ ہے۔ یہ واحد شجری نمونہ ہے جو حجری دورکے کسی غار میں ملا ہے۔ ایک اور گوشے میں کئی گھوڑے اور گھوڑیاں ہیں۔ گھوڑیاں حاملہ ہیں اوران کے جسم میں بھالے پیوست ہیں۔ ایک گھوڑے ساتھ بھالے چبھے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑی سیاہ گائے بنی ہے جو حاملہ ہے۔ اس کے پاؤں کے پاس کئی مستطیل نشان ہیں۔ ایک جگہ دو بھورے رنگ کے بیسن پیٹھ جوڑے کھڑے ہیں۔ ایک چھت پر پانچ نہایت خوبصورت ہرن ندی میں تیرتے دکھائی دیتے ہیں، اس منظر کی لمبائی 16فٹ ہے۔
مگر لاسکا کا سب سے حیرت خیز منظر وہ ہے جو غار کے سب سے پوشیدہ ، تاریک اور مشکل مقام پر بنایا گیا ہے۔ دراصل یہ بیس فٹ گہرا ایک کنواں ہے۔ کنوئیں کے ایک طرف کی دیوار کو کاٹ کر اس میں سیڑھیاں نکالی گئی ہیں۔ کنوئیں میں اُترنے کا راستہ شاید یہی تھا۔ اس کنوئیں کی دیوار پر ایک آدمی کی اقلید سی شکل سہلہوٹ میں بنی ہے۔ اس کا سر اور چونچ پرندے کا ہے البتہ نچلا دھڑ آدمی کا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں لیکن ہاتھوں میں انگلیاں فقط چار ہی ہیں۔ اس کا عضو تناسل اِستادہ ہے اور وہ زمین پر گرتا نظرآتا ہے یا مردہ پڑا ہے۔ اس کی پشت کی جانب ذرا ہٹ کر ایک چھڑی زمین پر گڑی ہے۔ اس چھڑی پر ایک چڑیا بیٹھی ہے۔ اس چڑیا کا سرآدمی کے سر سے بہت مشابہ ہے۔ پاس ہی بھالا پھینکنے والا ایک اوزار پڑا ہے۔ اس اوزار سے زاویہ قائمہ بناتا ہوا ایک بھالا ہے جو ایک سیاہ رنگ کے بیسن کے پیٹ اورپیٹھ کے آرپار ہوگیا ہے۔ بیسن کی انتڑیاں باہر نکل آئی ہیں۔ اس کی دُم اُٹھی ہوئی ہے اور اس کی پیٹھ اور گردن کے بال کھڑے ہیں۔ اس کا سر حملے کے انداز میں جھکا ہوا ہے اور اس کی سینگوں کا رُخ آدمی کی طرف ہے۔ اس کے پاؤں کی سختی اور اس کے جسم کا داخلی تناؤ بتا رہا ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے بے چین ہے مگر حرکت سے معذور ہے۔ حملہ آور کے اندرونی تناؤ اور خارجی بے بسی کے درمیان جو تضاد ہے وہ اس تصویر سے نمایاں ہے۔ آدمی سے تھوڑے فاصلے پر ایک گینڈا بنا ہے جس کی پیٹھ آدمی کی طرف ہے اور وہ دور ہٹ رہا ہے۔ اس کے دو سینگ ہیں۔ یہ غار کا واحد گینڈا ہے۔ گینڈے اور آدمی کے درمیان چھ بڑے بڑے سیاہ دھبے بنے ہیں، دو دو کی قطار ہیں۔
اس غیر معمولی منظر کی اب تک کوئی معقول تشریح نہیں ہوسکی۔ بعض عالموں کا خیال ہے کہ یہ تصویر یادگاری ہے۔ اس کا تعلق کسی قبیلے کی زندگی کے کسی اہم واقعے سے ہے۔ شاید قبیلے کا سردار گینڈے یا بیسن کے شکار میں مارا گیا تھا۔ اس وقت اس نے چڑیے کا سوا نگ بھر رکھا تھا کہ یہ طریقہ بہت عام تھا ۔ (چنانچہ بِہلیے اور چڑی مار اب تک یہی کرتے ہیں)۔ مصور نے اس حادثے کی منظر کشی کرکے مورخ کے فرائض انجام دیے ہیں لیکن اس تشریح سے ان چھ نقطوں کی توجیہہ نہیں ہوتی جو آدمی اور گینڈے کے درمیان بڑے قاعدے سے لگائے گئے ہیں۔ نہ بیسن کی بے بسی کا سبب واضح ہوتا ہے اور نہ گینڈے کے فرار کی تشریح ہوتی ہے۔ یہ راز بھی نہیں کھلتا کہ اگر اس تصویر کا تعلق سحر کی کسی نہایت خفیہ رسم سے نہیں ہے تو پھر اس کو انتہائی پوشیدہ اور تاریک کنوئیں میں کیوں بنایا گیا تھا۔
لاسکا کے غار میں مختلف نسل کے گھوڑوں کی 58 تصویریں ہیں۔ دو جنگلی گدھے ہیں، بیس بیل اور گائیں ہیں، ہرنوں کی تعداد بیلوں سے کم ہے، سات بیسن ہیں، چھ بلی کی نسل کے جانور ہیں، ایک گینڈا ہے، ایک بھیڑیا ہے، ایک ریچھ ہے، ایک یونی کارن ہے اور ایک چڑیا۔
یوں تو قدیمی حجری دورکا ہر مصور غاردیدنی ہے لیکن فنی اعتبار سے چھ غار خاص طورپر ذکر کے قابل ہیں۔ اول التمیرا کا غار، جو سب سے پہلے دریافت ہوا اور سب سے مشہور ہے ۔ دوئم فونت واگام، سوئم تین بھائیوں کا غار، چہارم لاسیل، پنجم لے کومبریل اور ششم لاسکا۔
التمیرا کے غار میں جانوروں کی تقریباً170 تصویریں اب تک صحیح و سالم موجود ہیں۔ اس کے بڑے کمرے میں جو چار پانچ فٹ اونچا ہے چھت پر جو رنگین تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ دیواری فن مصوری کے قیمتی نوادر میں شمار ہوتی ہیں یہ دراصل پندرہ گز لمبا ایک منظر ہے جس میں ایک ہرن اور بیس بیسنوں کی خاموش جنگ کا مرقع پیش کیا گیا ہے۔ فقط دو گھوڑے اور دو سُور، ہرن کے حمایتی ہیں۔ مگر ہرن فتح یاب ہے۔ یہ تصویریں کندہ ہیں اور رنگ آمیز بھی۔ ان تصویروں میں حسنِِ ترتیب کے علاوہ بڑا تنوع ہے۔ دراصل اس مرقعے میں ہر جانور کی انفرادی کیفیت کا اظہار کیا گیا ہے مگر مجموعی تاثر کا خون نہیں ہوتا بلکہ اس میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ میکس رفیل نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ ہرن دراصل ایک قبیلے کی نمائندگی کرتا ہے جس نے اپنے سحر کے زور سے دوسرے حریف جانوروں کو جو دشمن قبیلوں کی علامت ہیں ہلاک کیا ہے۔ یہ منظر مُثلث یا عمودی اصولِ تو ضیح پر نہیں بنا ہے بلکہ انسان کے کھلے ہوئے ہاتھ سے مشابہ ہے۔
لے کو مبریل کا غار نو سو فٹ لمبا اور تین یا چھ فٹ چوڑا ہے۔ اس غار میں تقریباً تین سو تصویریں بنی ہیں جو مختلف جانوروں کی ہیں البتہ سوانگ بھرے ہوئے حیوان نما انسان کی تعداد یہاں سب سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی کا سر تو ممیتھ کا ہے۔ ان کے علاوہ ایک موٹا آدمی ہے جو ایک عورت کا تعاقب کررہا ہے۔ دیواروں پر جا بجا انسانی شکلیں کھدی ہیں مگر ان کے سر جانوروں کے ہیں۔
تین بھائیوں کا غار فرانس کےایک پرانے نواب کی زمین پرہے۔ 1912ء میں نواب کےتین لڑکے تعطیل میں گھر آئے ہوئے تھے۔ قریب ہی دریائے دولپ بہتا ہے۔ یہ دریا قصبے سے تھوڑے فاصلے پر ایک غار میں غائب ہوجاتا ہے اورپھر ایک دوسرے مقام پر پہاڑ سے نمودار ہوتا ہے۔ تینوں بھائیوں نے ایک چھوٹی سی کشتی بنائی اور اس زمین دوز دریا کا سراغ لگانے نکلے۔ کشتی غار میں چلتی رہی اورایک ایسے مقام پر پہنچی جو دراصل ایک جھیل تھی۔ وہاں چٹان پر انھیں سترھویں صدی کے چند آثار ملے جس سے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ ان سے پیش تر بھی وہاں تک پہنچے تھے۔ وہ اور آگے بڑھے تو ایک سمت ایک سرنگ ملی جس کا دہانہ پتھر کی ایک باریک سی چادر سے ڈھک گیا تھا مگر اس پار کی روشنی چھن کر آرہی تھی۔ لڑکوں نے یہ چادر توڑ دی اوراب وہ ایک نگار خانے میں تھے۔ اس غار میں یوں تو دوسرے غاروں کی مانند کندہ کاری اور مصوری کے بہ کثرت نمونے موجود ہیں مگروہاں کی چند اپنی خصوصیتیں بھی ہیں۔ مثلاً مٹی کے دو بیسن ایک چٹان سے لگے کھڑے ہیں۔برفانی اُلو کا ایک جوڑا چٹان پر کھدا ہوا ہے۔ قریب ہی ان کے بچے کی شکل بھی بنی ہے لیکن سب سے اہم دریافت وہ جادوگر ہے جس کے گرد لاتعداد جانوروں کا ہجوم نقش کیا گیا ہے۔ اس جادوگر کے کان بارہ سنگھے کے کانوں سے مشابہ ہیں اور کھڑے ہیں۔ اس کی داڑھی بہت لمبی ہے البتہ دہانہ ندارد ہے۔ اس کی کہنیاں اُٹھی اور آپس میں ملی ہوئی ہیں اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ انگلیاں ننھی ننھی اورپھیلی ہوئی ہیں۔ عضو تناسل بہت نمایاں ہے مگر استادہ نہیں ہے بلکہ بال دار دُم کے اندر پیوست ہے۔ ایبے بروئیل کی رائے میں اس کے سحر کا تعلق جانوروں کی افزائشِ نسل سے ہے۔
لاسیل (وادیِ دوردون) کے غار نمایاں خصوصیات عورتوں کے فرازی مجسمے ہیں جو چٹانوں پر اُبھرے ہوئے ہیں۔
لاسیل کے غار میں عورتوں کے جو پانچ فرازی مجسمے ملے ہیں وہ اس فن کی سب سے پرانی یادگار ہیں۔ ان مجسموں میں نسوانی اندام بہت نمایاں ہیں۔ انھیں میں ڈیڑھ فٹ کا وہ مشہور فرازی مجسمہ بھی ہے جو اب عجائب گھر کی زینت ہے۔ عورت کے اس مجسمے کے چاروں طرف پتھر کو کھود کر بہت گہرا کردیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے مجسمے کا اُبھار اور واضح ہو گیا ہے۔ یہ عورت سرسے پاؤں تک برہنہ ہے۔ اس کے کولھے بہت بھاری اور چوڑے ہیں۔ چھاتیاں بھی بہت بڑی ہیں اور لوکی کی مانند لٹکی ہوئی ہیں۔ رانوں کے درمیان اُبھار بھی بہت واضح ہے۔ وہ بیسن کی ایک سینگ لیے ہوئے ہے جو ہلالی ہے۔ سینگ پر چند متوازی عمودی نشان کندہ ہیں۔ اس کا بایاں ہاتھ پیڑو پھر دھرا ہے۔ پیڑو پھولا ہوا ہے جس سے حمل کا گمان ہوتا ہے۔ چہرے کی تفصیلات جان بوجھ کر نہیں بنائی گئی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف انھیں اعضا کی نمائش مقصود تھی جن کا تعلق افزائشِ نسل سے ہے۔ عورتوں کے چار مجسمے بھی ہیں جو اسی انداز کے ہیں۔ ان مجسموں پر جگہ جگہ سرخ رنگ بھی پایا گیا ہے۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ سرخ رنگے ہوئے تھے۔ سرخ رنگ حجری دورمیں زندگی کی علامت تھا۔
گارگاس کا غار اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہاں ہاتھ کے چھاپے بہ کثرت ملے ہیں۔ یہ چھاپے الگ الگ بھی ہیں اور اکٹھا بھی۔ ایک چٹان پر تو ایک ہی جگہ ڈیڑھ سو چھاپے لگے ہیں۔ ان میں ایک کمسن بچے کا چھوٹا سا ہاتھ بھی ہے۔ یہ چھاپے سرخ بھی ہیں اور سیاہ بھی۔ بعض جگہوں پر ہاتھ کو رنگ میں ڈبو کر دیوار پر چھاپہ لگادیا گیا ہے اور بعض جگہوں پرہاتھ کے سلہوٹ بنے ہیں یعنی انگلیوں کو دیوار پر پھیلا دیا گیا ہے اورپھران کے گرد رنگ پھیر دیا گیا ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اکثر چھاپوں میں چار انگلیاں نظر آتی ہیں مگر انگوٹھا غائب ہے اور انگلیوں کے سرے کے پور کٹے ہوئے مگر بعض پنجے پورے بھی ہیں۔ ان چھاپوں میں بائیں ہاتھ کی کثرت ہے اور یہ قدرتی بات ہے کہ کیوں کہ دائیں ہاتھ سے رنگ آمیزی کی جاتی تھی۔ قدیم حجری فن میں ہاتھ کے نشان کی جو اہمیت اور خصوصیت ہے اس پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔یہاں فقط اتنا بتا دینا کافی ہے کہ حجری فن کے ہنئیتی ارتقا کی سب سے ابتدائی شکل ہاتھ کے یہی چھاپے ہیں۔ اسی غار میں عورت کے جنسی عضو کی شکل بھی الگ کندہ ہے اورایک مرغابی کوپانی میں تیرتا دکھایا گیا ہے۔
ابتدا میں عام خیال یہی تھا کہ حجری دورمیں فن کار اپنی تصویریں اور مجسمے فقط غار کے عمیق ترین گوشوں میں بناتے تھے یا نہایت دُشوار گزار مقامات پر جو تنگ و تاریک ہوتے تھے۔ التمیرا اور اس قبیل کے غاروں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے مگر جنوبی اور مشرقی اسپین میں جو دریافتیں ہوئیں ان سے خیال کو تردید ہو گئی کیوں کہ ان خطوں میں بکثرت رنگین تصویریں زمین کےاوپر چٹانوں پر منقوش یا کندہ ملی ہیں۔ شاید اس عہد کے فن کاروں نے تصویریں غاروں کے اندر بھی بنائیں اور کھلی ہوئی چٹانوں پر بھی۔ جو تصویریں کھلی جگہوں پر تھیں وہ دھوپ ، ہوا اور بارش کے سبب ضائع ہوگئیں اور جو غاروں میں تھیں وہ موسمی اثرات سے محفوظ رہیں۔ یہ بھی قرین قیاس ہے کہ جو قبیلے غاروں کے اندر رہتے تھے اورجن کی بودوباش نسبتاً سخت ماحول میں تھی انھوں نے غاروں میں تصویریں بنائیں اور جنوبی اسپین اور افریقہ کے لوگوں نے جو دوسری نسل سے تعلق رکھتے تھے اور نسبتاً گرم ماحول میں رہتے تھے کھلی ہوئی چٹانوں کو ترجیح دی۔
سطح زمین سے اوپر کی حجری تصویروں کو بناتے وقت شاید مصنوعی روشنی روشنی کی ضرورت نہ پڑی ہو لیکن گہرے غاروں اور تاریک سرنگوں میں تو دن کے وقت بھی ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا چہ جائیکہ تصویر کشی اور کندہ کاری کرنا اس لیے روشنی کا انتظام ضروری تھا۔ قدیم حجری دور میں روشنی کےلیے چراغ اور مشعل استعمال ہوتے تھے۔ ان میں چربی جلائی جاتی تھی۔ غاروں میں بہ کثرت ایسی چیزیں ملی ہیں جن سے چراغ یا مشعل کا کام لیا جاتا تھا۔ کئی مقامات پر پتھر کے ایسے دیئے بھی دستیاب ہوئے ہیں جن میں چربی کے ٹکڑے اور جلی ہوئی بتیوں کے گل موجود تھے۔ اسی طرح جلی ہوئی لکڑی کے ٹکڑے بھی افراط سے ملے ہیں۔
قدیم حجری دور کےفن کار تین بنیادی رنگ استعمال کرتے تھے۔ سرخ۔ زرد اور سیاہ۔ نیلے اور سبز رنگ کے آثار کہیں نہیں ملتے۔ شاید یہ لوگ نیلا اور سبز رنگ نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ رنگ چوں کہ جلد خراب ہو جاتے ہیں اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ہزاروں سال بعد اب یہ اُڑ چکے ہوں۔ یہ رنگ معدنی اشیا سے بنائے جاتے تھے نہ کہ بناتات سے۔ کالے رنگ کے لیے تو لکڑی کا کوئلہ یا چراغ کا دھواں موجود ہی تھا البتہ سرخ اور زرد رنگ مینگینز، سیندور اور لوہے کے آکسائڈ سے بنائے جاتے تھے۔ یہ معدنی اشیا خود غاروں میں یا نواح میں افراط سے پائی جاتی تھیں۔ ان معدنی رنگوں کے باریک سفوف کو جانور کے خون، چربی اور انڈے کی سفیدی میں گوندھ لیا جاتا تھا۔ مو قلم کی جگہ ابتدا میں انگلیوں سے کام لیا گیا، پھر درخت کی پتلی پتلی شاخوں یا پرندوں کے پر کو کچل کر ان سے قاز بنائے گئے۔ زیادہ باریک کام کے لیے ہڈی کی پتلی پتلی تیلیوں کو پتھر پر رگڑ کر نوک نکال لیتے تھے۔ ان رنگوں کو پتھر کی تھالیوں میں رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ غاروں میں رنگوں کی تھالیاں اور برش کثرت سے ملے ہیں۔ کندہ کاری پتھر کے نکیلے ٹکڑوں سے کی جاتی تھی۔
یہ فن پارے ایک سال یا ایک صدی کے اندر نہیں بنائے گئے بلکہ و ہ انسان کی ہزاروں سال کی محنت کا ثمر ہیں، شکاریوں کے قافلے آتے، چند مہینے یا چند سال ایک مقام پر رہتے۔ اپنی ضرورت، ذوق اور صلاحیت کے مطابق غاروں میں نقش و نگار بناتے اورپھر شکار کے تعاقب میں کسی اور سمت کی راہ لیتے۔ برسوں بعد وہاں کسی دوسرے قبیلے کا گزر ہوتا تو وہ ان غاروں کو دوبارہ روشن کرتا اور اپنی ضرورت اور صلاحیت کے مطابق تصویریں بناتا۔ کبھی پرانی تصویروں سے ہٹ کر کبھی ان کے پہلو میں، اور کبھی انہیں کے اوپر۔ چنانچہ بعض غاروں میں تصوریروں کے خط اور رنگ آپس میں اس طرح گڈ مڈ ہوگئے ہیں کہ ان کو الگ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس گڈ مڈ کی وجہ سے تصویروں کو فنی نقصان ضرور پہنچا ہے لیکن ماہرین آثار کے لیے اب تصویروں کے مختلف عہد اور ادوار متعین کرنا آسان ہوگیا ہے۔ مثلاً ایبے بروئیل اور اوپر میئر نے فقط فونت دے گام کے غار میں سات مختلف ادوار کا سراغ لگایا ہے۔ بعض غاروں میں تو تیرہ چودہ اَدوار کے آثار موجود ہیں لیکن ہنوز یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ ان ادوار میں ایک سو سال کا فرق ہے یا ایک ہزار سال کا۔
بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ ایک قبیلے نے چند تصویریں بنائیں اور رخصت ہوگیا اور جب دوسرا قبیلہ آیا تو اس نے ان تصویروں کو جوں کا توں رہنے دیا البتہ چند تصویروں کا اضافہ کرکے ایک نیا منظر ترتیب دے دیا۔
بہرحال قدیم حجری دور کے اس فن نے ارتقا کی خواہ کتنی منزلیں کیوں نہ طے کی ہوں اور وقت اورقبیلوں کے فرق کے سبب سے خواہ اس فن میں کتنی تبدیلیاں کیوں نہ آئی ہوں مگر ان کے فن کی غرض و غایت اور نوعیت اور خصوصیت میں کبھی فرق نہیں آیا اور نہ اس کی بنیادی ہیئت بدلی۔ ہردور میں ا س آرٹ کا محور، مرکز اور محرک شکاری جانور ہی رہا وہ جانور جس کی افزائشِ نسل پر اور جس کے شکار پر خود انسان کی پوری زندگی کا دارو مدار تھا۔ اس پور ے عہد میں جانوروں کی جو شکلیں بنائی گئیں وہ اصل کے عین مطابق ہیں۔ بالکل سچی اور نمائندہ تصویریں نسبتاً بھونڈی اور ناقص تھیں۔
ان تصویروں کی عمر کی بابت اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان میں سب سے قدیم وہ ہیں جو کم سے کم چالیس ہزار سال پرانی ہیں اور جدید نقش و نگار بھی دس ہزار برس پرانے ضرور ہیں۔
قدیم حجری دور میں مصوری، کندہ کاری اور مجمسہ سازی کے فن کی ابتدا کیسے ہوئی۔ انسان نے سب سے پہلا نقش کیوں اور کیوں کر بنایا۔ وہ کون سےمحرکات تھے جنھوں نے اسے اس ایجاد پر آمادہ کیا۔ کیا وہ پیدائشی فن کار تھا، اور نقش گری ا س کی فطرت اور جبلت میں داخل تھی یا خارجی حالات و اثرات نے اس میں یہ شعور پیدا کیا۔ کیا کسی وجدانی اور غیر شعوری جذبے نے اس میں تصویر کشی کی امنگ پیدا کی اوراس نے دیواروں پر خط اور رنگ کے حسین مرقعے بنانے شروع کردیے یا اس تخلیقِ فن کے اسباب مادی اور تاریخی ہیں؟ مگر ان سوالوں کے جواب کیوں نہ خود فن کاروں سے پوچھیں۔ گو ان کی زبانیں مدت گزری بند ہو چکی ہیں اوران کے مو قلم ہزاروں برس سے سوکھے پڑے ہیں لیکن شاید ان کی تصویریں اور ان کے نقوش ہماری کچھ مدد کرسکیں۔
غاروں نقش و نگار کا بغور مطالعہ کرنے سے پیش ترہمیں ایک نہایت اہم نکتہ ذہن نشین کرلینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ مصوری کے فن کو ایجاد کرتے وقت انسا ن کو قطعاً یہ احساس نہ تھا کہ وہ کسی فن کی داغ بیل ڈال رہا ہے۔ ٹی ۔ایس۔ ایلیٹ نے کلچر کی بحث میں ایک جگہ لکھا ہے کہ کلچر بسا اوقات وہ لوگ تخلیق کرتے ہیں جن کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کلچر تخلیق کررہے ہیں۔ یہی حال قدیم حجری دورکے انسان کا تھا۔ وہ نہ تو فن کی اصطلاح سے واقف تھا اور نہ فن کی خاطر فن پیدا کررہا تھا۔
آئیے ، اب ایک غار میں چلیں۔ اس غار میں آپ کو چٹانوں پر چند نشان کھدے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ نشان آدمیوں نے نہیں بنائے بلکہ برفانی عہد کے بڑے بڑے ریچھوں نے اپنے ناخنوں سے کھودے تھے۔ ریچھ قدیم حجری دور کے انسانوں کا ہم عصر تھا اور آدمیوں کی مانند غاروں میں رہتا تھا۔ وہ اپنے سامنے پنجوں کو تیز یا صاف کرنے کی خاطر چٹان پر رگڑتا تھا۔ اس کے پنجے اتنے مضبوط اوراس کے دانت اتنے تیز تھے کہ ان کو رگڑنے سے پتھر پر نشان پڑجاتے تھے۔ اب ذرا اِن نشانوں کا مقابلہ اُن نشانوں سے کیجئے جو التمیرا کے غار میں انسان نے اپنی انگلیوں سے دیوار کی مٹی پر کھینچے ہیں۔ ریچھ نے ناخنوں سے جو کیاریاں بنائی ہیں اور انسان نے جو جلیبیاں اور سویاّں بنائی ہیں ان میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی بنا پر علما ئے آثارِ قدیمہ کا خیا ل ہے کہ قدیم انسان نے ریچھ کی دیکھا دیکھی یہ نشان بنائے تھے۔
مگرانسان نے ریچھ کی نقل کیوں کی!
اس لیے کہ اس نے ریچھ میں اوراپنے آپ میں بہت سی باتیں مشترک پائیں۔ ریچھ انسان کی مانند غار میں رہتا تھا۔ اس کےجسم پر بھی بڑے بڑے بال تھے۔ وہ اپنے سامنے کے پاؤں سے قریب قریب وہی کام لیتا تھا جو انسان اپنے ہاتھوں سے لیتا تھا۔ شاید اس کے بڑے بڑے ناخنوں والے بال دار ہاتھ ریچھ کے ناخن اور پنجوں سے ملتے جلتے ہوں۔ ریچھ انسان کی مانند پاؤں پر کھڑا ہوجاتا تھا۔ انسان ہی کی طرح درختوں پر چڑھ کر پھل توڑتا تھا اور جانوروں کا شکار کرتا تھا مگر بہت سی باتوں میں وہ انسان سے افضل تھا۔ مثلاً وہ انسان سے کہیں زیادہ طاقت ورتھا۔ ریچھ کی جنسی قوت کی جو حکاتیں سنی جاتی ہیں ممکن ہے قدیم انسان نے اس قوت کا مشاہدہ بھی کیا ہو، شاید قدیم انسان نے ریچھ کی جسمانی طاقت کا مرکز اس کے ہاتھوں اور ناخنوں کو سمجھا ہو اور یہ سوچا ہو کہ اگر میں بھی پتھر پر انگلیوں سے نشان بناؤں تو میرے ہاتھوں میں بھی وہی طاقت آجائے گی جو ریچھ میں ہے چنانچہ اوبر میئر اوبر میسر کہتا ہے۔
“ان جھجکے جھجکے سے ناقص نشانوں کی ابتدا بلا شبہ خارجی اثرات سے ہوئی۔ اس کے لیے ہمیں کم سے کم مغربی یورپ میں غار میں رہنے والے ریچھ کا ممنون ہونا چاہیے، مگر اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان تحت الشعور میں فنی رحجان پہلے سے موجود تھا۔ ریچھ کے کھرچے ہوئے نشانوں کی بدولت انسان نے جو ابتدائی کوششیں کیں انھیں ہم آرٹ کا نام دیں یا نہ دیں لیکن یہ طے شدہ امر ہے کہ قدیم انسان میں اگر ایسی صلاحیت ابتدا ہی سے ودیعت نہ کی گئی ہوتی جو فنی اثر قبول کرکے اورپھر خود فن کی تخلیق کرسکے تو وہ کبھی فن کار نہیں بن سکتا تھا۔”
غرض کہ کندہ کاری کی سب سے پہلی جلیبیوں اور سویوں کے سے وہ لہراتے اور بل کھاتے نشان تھے جو انسان نے ریچھ کی دیکھا دیکھی غار کی دیواروں پر جمی ہوئی گیلی مٹی پر اپنی انگلیوں سے کھینچے۔ ان نشانوں میں بڑی حرکت اور روانی ہے۔ مگر انسان ریچھھ کی اس نقالی سے بہت جلد آزاد ہوگیا۔اس کا تشکیلی اور تصویری شعور ابھر آیا اوروہ ان سوچوں جیسی لکیروں ہی سے جانوروں اور عورتوں کے خاکے بنانے لگا۔ اس نے انگلیوں کا استعمال ترک کردیا اور ان خاکوں کے لیے دو شاخی، سہ شاخی سینگ یا لکڑی کے ٹکڑوں سے کام لینے لگا۔ گیلی مٹی میں کھدے ہوئے یہ خاکے چوں کہ بہت جلد خراب ہو جاتے تھے اس لیے اس نے پتھر کے نکیلے اورتیز ٹکڑوں کی مدد سے یہ خاکے چٹانوں میں کھودنے شروع کردیے۔
پروفیسر جو ہانزمارنگز کا خیال ہے کہ رنگین تصویروں کی ابتدا کا زمانہ بھی وہی ہے جو کندہ کاری کا ہے اور فنِ مصوری کے عہدِ ترقی کی تاریخ بھی غاروں کے بغور مطالعے سے باآسانی مرتب ہو سکتی ہے۔ پروفیسر کی رائے میں سب سے پرانی تصویریں وہ ہاتھ ہیں جو برفانی انسان نے دیواروں پر بنائے۔ ہاتھوں کے یہ چھاپے ابتدائی عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ چھاپے سل ہوٹ ہوتے تھے۔ انسان اپنا ہاتھ گیلی چٹان پر رکھ دیتا تھا۔ انگلیوں کو پھیلا دیتا تھا اور پھرایک نالی کے ذریعے رنگین سفوف کو انگلیوں کے گرد پھونکتا تھا یا رنگ کو پانی میں گھول کر ہاتھ اس میں ڈبو دیا جاتا تھا۔ پھر اس کی چھاپ دیورا پر لگای دی جاتی تھی۔ ایسے سرخ، بادامی، اودے، زرد، سیاہ اور سفید چھاپے متعدد غاروں میں ملے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ہاتھ غائب ہوجاتے ہیں اوران کی جگہ رنگین لہریے لے لیتے ہیں۔ یہ لہریے انگلیوں کور نگ میں ڈبو کر بنائے جاتے تھے۔ ابتدا میں بھری مٹی پر انگلیوں سے جو بے رنگ نشان کھینچے جاتے تھے، ان کے مقابلے میں یہ رنگین نشان زیادہ جاذبِ نظر ہوتے ہوں گے اور غار کے اندھیرے میں سرخ اور زرد رنگوں کی چمک کا اثر ابتدائی انسان کے جذبات اور احساسات پر بہت شدید ہوتا ہوگا۔ ان لہریوں کے درمیان جانوروں کی ابتدائی شکلیں بھی ملنے لگتی ہیں۔ شروع میں جانوروں کی یہ شکلیں دراصل خاکے ہیں جن کے لیے دو یا تین متوازی لکیروں سےکام لیا گیا ہے۔ تب کہیں واحد لکیروں کی باری آئی ہے۔ یہ واحد لکیریں بھی پہلے موٹی ہیں، پھر پھیکی پھیکی سی جیسےکسی نے انھیں سوختے سےخشک کیا ہو او رتب وہ باریک ہوتی گئی ہیں۔ خاکوں میں رنگ بھرنے کا دور بہت بعد میں آیا۔ ابتدا میں جانوروں کے خاکے بھونڈے ہوتے تھے۔ ان کے اعضا اکڑے اکڑے سے اور سخت ہوتے تھے اور جسم کے وہی حصے بنائے جاتے تھے جو قریب اورسامنے سے نظر آتے ہیں مگر کچھ عرصے کے بعد خاکوں میں روانی آجاتی ہے اوروہ متحرک نظر آنے لگتے ہیں۔
قدیم حجری دورمیں فنِ مصوری کا آغاز ہاتھ کے چھاپوں سے کیوں ہوا۔ جانوروں کی تصویروں سے کیوں نہیں ہوا؟ اس کی سب سے معقول توجیہہ میکس رفیل نے کی ہے۔
” دراصل جو چیز انسان کو دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کے ہاتھ ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان کی بقا اور ترقی میں دماغ اورزبان کی اہمیت کم ہے۔ مگر جس عضو بدن کی بدولت وہ د وسرے جانوروں سے الگ ہوا ، جو اس کا سب سے کارآمد اورموثر حربہ اور اَوزار ثابت ہوا اورجس کی مددسے اس نے تسخیرِ قدرت کی ابتدا کی وہ اس کے ہاتھ ہی تھے۔”
دانش وروں میں ا تک اس بات پر شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ فکر اورگویائی کی طاقت فقط انسان کا خاصہ ہے یا دوسرے جانور بھی اپنے اپنے انداز میں سوچتے اور بولتے ہیں۔ بعض دانش ور کہتے ہیں کہ دماغ اورزبان انسان کا اجارہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرے جانورو ں کے پاس بھی دماغ اورزبان موجود ہے اور ثبوت میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس چیز کو سریا بھیجا کہتے ہیں تمام جانوروں کے پاس ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو قوتِ فکر سے محروم قراردیں۔ اسی طرح وہ اعضا بھی جو کلام کے لیے ضروری ہیں یعنی زبان، دانت، حلق، منھ اور سر، اکثر جانوروں میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اکثر جانور منھ سے طرح طرح کی آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ لہٰذا فقط اس بنا پر کہ ہم ان آوازوں کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے ہم ان کو بے زبان کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ مگراس بات پر تمام دانش وروں کا اتفاق ہے کہ جس عضو بدن کو ہم ہاتھ کہتے ہیں وہ فقط انسان کو نصیب ہے اور اِس عضو سے جو کام انسان لیتا ہے دوسرا کوئی جانور اپنے کسی عضو سے نہیں لے سکتا۔
دراصل انھیں ہاتھوں نے انسان کو صحیح معنی میں انسان بنایا۔ ان ہاتھوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ذریعے انسان نے تخلیق کا عمل شروع کیا۔ اس نے ان کی مدد سے نئی چیزیں پیدا کیں۔ دنیا کا کوئی دوسرا جانور مظاہرِ قدرت میں کوئی تبدیلی نہیں کرسکتا بلکہ اس کی اطاعت پر مجبور ہے کیوں کہ وہ خود کوئی چیز پیدا کرنے اور بنانے پر قادر نہیں ہے۔ اس کے برعکس انسان پیدا آور جانور ہے۔ اس نے پتھر کے ٹکڑوں کو رگڑ کر آگ پیدا کی ہے، آلات و اَوزار بنائے ہیں پوشاک تیا ر کی ہے مٹی کے برتن گڑھے ہیں، زمین کھودکر نئی فصلیں اُگائی ہیں ، اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کی ہیں، تحریر کا فن ایجاد کیا ہے، کارخانی اور فیکٹریاں تعمیر کی ہیں اور برقی اورایٹمی طاقت پیدا کی ہے اور یہ ساری تخلیقیں اور ایجادیں براہِ راست ہاتھوں سے ہوئی ہیں۔ ہزاروں سال پیش تر کا ابتدائی انسان دماغ کے پراسرار اور پوشیدہ عمل سے واقف نہیں ہو سکتا تھا اور وہ ذہن اور ہاتھوں کے تخلیقی عمل میں جو رشتہ ہے اس کا ادراک کرسکتا تھا البتہ وہ ہاتھوں کی معجز نمائیوں کو دیکھ سکتا تھا، محسوس کرسکتا تھا، اس کا سارا سرمایہ حیات واقعی یہی ہاتھ تھے۔ پھر وہ اس دولت آفریں عضو بدن کو سحر سے معمور کیوں نہ خیال کرتا۔
ہاتھ اس کے نزدیک جسمانی طاقت کی علامت تھے اس لیے بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہاتھوں ہی سے شکار کرتا تھا۔ چنانچہ اس کی منطق یہ تھی کہ اگرکسی ترکیب سے ہاتھوں کی تعداد بڑھائی جا سکے تو شکار کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے۔ چھاپے چوں کہ ہاتھ کا ہو بہو عکس ہوتے تھے اس لیے قدیم انسان کے نزدیک ان میں ہاتھوں کی تاثیر کا ہونا لازمی تھی۔ وہ چھاپوں کو بے جان تصویریں نہیں سمجھتا تھا ، کیوں کہ جان دار اوربے جان کے فرق سے ہنوز اس کا ذہن نا آشنا تھا۔
کوئی فن ایک دن میں نہیں آتا بلکہ اس کو سیکھنے کے لیے پہیم مشق کرنی پڑتی ہے۔ آج کل تو خیر حصولِ فن کے لیے درس گاہیں موجود ہیں جہاں کہنہ مشق استاد اپنے نو آموز شاگردوں کو فن کی تعلیم دیتے ہیں۔ مگرکیا اب سے چالیس ہزار سال پیش تر بھی استاد اور مدرسے ہوتے تھے؟ شواہد کہتے ہیں کہ استادو شاگرد کا رشتہ اس وقت بھی موجود تھا اور قبیلے کے نوجوانوں کو مصوری اور کندہ کاری کا فن باقاعدہ سکھایا جاتا تھا۔ مثلاً لیموئیل کے غار میں ایک ہی مقام پر پتھر کی 137 چھوٹی چھوٹی تختیاں ملی ہیں جن پر نقاشی کی مشق کی گئی ہے۔ ان میں بعض خاکے بہت اچھے ہیں اور بعض بے حد ناقص۔ ان پر جا بجا کسی استاد کی اصلاح بھی نظرآتی ہے۔ اسی طرح پاریا لو (اسپین) کے غار میں پتھر کی 1430 تختیاں ملی ہیں جن پر تصوریریں کھدی یا بنی ہیں۔ پتھر کا ایک ایسا ٹکڑا بھی ملا ہے جو تصویروں سے لپا ہوا ہے۔ اُلٹی سیدھی، آڑی ترچھی، اوپر تلے، پشت پر غرض کہ سیکھنے والے نے اس ایک ٹکڑے پر لا تعداد شکلوں کی مشق کی ہے۔ ہونہار شاگرد تعلیم سے فارغ ہو کر خود استاد بن جاتے تھے۔ سحرکی رسوم بھی یہی فن کار ادا کرتے تھے، ابتدا میں ان ساحروں اور فن کاروں کی حیثیت قبیلے کے دوسرے افراد سے مختلف نہ تھی اور نہ انھیں خاص رعایتیں حاصل تھیں مگرفن کے تقاٖضے اور ادائیگی رسوم کی ضرورتیں بڑھیں تو ساحروں کو شکار یعنی حصولِ غذا کے فرائض سے مستثنٰی کردیا گیا۔ وہ اپنے سحر اورفن کے ذریعے قبیلے کو شکار حاصل کرنے میں مدد دیتے تھے اور قبیلہ اس کے عوض ان کو غذا فراہم کرتا تھا۔
غاروں کے نقش و نگار خود پکا ر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اناڑی ہاتھوں کی تخلیق نہیں ہیں بلکہ ہمیں بڑے کہنہ مشق استادوں نے بنایا ہے۔ ایسے صاحبِ فن استاد جن کی آنکھوں نے اپنے گردو پیش کے جانوروں کا ان کے عادات و خصائل کا، کردار، مزاج اور حرکات کا بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ یہ فن کار جانتے تھے کہ حملہ کرتے وقت یا دوڑتے وقت جانور کے جسم کی داخلی اور خارجی کیفیت کیا ہوتی ہے اور جانور زمین پر بیٹھا یا آرام کرتا ہو تو اس کی دھج کیا ہوتی ہے۔ تجربے اور مشاہے سے اس نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ جسم کے کسی حصے پر بھالے کی ضرب سے جانور کو گرایا جا سکتا ہے۔
غار کی تصویروں پر نیزوں اور بھالوں کی مشق کے جو نشان بنے ہیں ممکن ہے کہ ان کا مقصد نو آموز شکاریوں کی تعلیم ہو۔ ابتدائی حجری دور کا انسان کفایت شعاری کرنے پر مجبور تھا۔ اس کے پاس نہ تو آلات و اَوزار کی فراوانی تھی اورنہ جانوروں کی۔ وہ نہ تو آلاتِ شکار ضائع کرسکتا تھا اور نہ شکار۔ یوں بھی بعض جنگلی جانور بڑے خطرناک ہوتے تھے اور چوں کہ وار بہت قریب سے کیا جاتا تھا اس لیے اندیشہ رہتا تھا کہ وار خالی ہونے کی صورت میں شکار کہیں پلٹ کر حملہ نہ کردے لہٰذا دُور اندیشی کا تقاضہ تھا کہ جانوروں کے ہو بہو مجسمے اور تصویریں بنائی جائیں اور نئے شکاریوں سے ان پر نیزہ اندازی کی مشق کرائی جائے تاکہ نشانہ پختہ ہو جائے۔ تب انھیں شکار کی مہم میں شریک ہونے کی اجازت دی جاتی تھی۔ آج کل جو چاند ماریاں یا فوجی مشقیں ہوتی ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے۔ پرانے زمانے میں دیو پیکر جانوروں کا شکار جنگی مہم سے کم خطرناک نہ ہوتا تھا۔
ہر عہد کا فن روحِ عصر کا ترجمان یا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس میں معاشرے کی اجتماعی اور انفرادی ہیجانات و اضطراب کی جھلک پائی جاتی ہے۔ وہ معاشرے کی کلفتوں اور اذیتوں، آرزؤوں اور امنگوں کا اظہار کرتا ہے، اس کی خوشیوں اور کامرانیوں کے گیت گاتا ہے اس کی قدروں کی پاس داری کرتا ہے اوراس کے مروجہ عقائد و تصورات کی خدمت کرتا ہے۔ چنانچہ قدیم مصری آرٹ کا محور اور محرک پرستی ہے کیوں کہ مصر کے فرعونوں اور پروہتوں نے بڑی چالاکی سے پوری قوم کو حیات بعد الموت کے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ خود نہایت عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے اور عام رعایا کو دوسری دنیا کا سبز باغ دکھاتے تھے۔ وہ بھی اس شرط پر کہ رعایا فرعون اور دوسرے بر گزیدہ بندوں کی بے چوں و چراں خدمت کرتی رہے۔ اسی طرح یونان اور ہندوستان کے فنون کی بنیاد صنم پرستی پر ہے اور قرونِ وسطیٰ کے مغربی فن کی مسیحی عقائد کی ترویج و اشاعت پر۔
فن اور معاشرے کا یہ تعلق فقط مقصد اور ماہیت تک محدود نہیں ہے بلکہ فن کی ہیئت اور طرزِ اد ا میں بھی روحِ عصر کا پر تو صاف نظر آتا ہے۔ مثلاً زراعت کی ایجاد کے بعد ہر ملک کا فن اقلید سی اصول کا پابند ہوگیا۔ چنانچہ مصر اور بابل کے تمام مجسمے، تصویریں اور عمارتیں دراصل ایک مَثلت ہیں۔ اس کے برعکس جسمِ انسانی سے لذت لینے والے یونانیوں اور ہندوستانیوں کا تمام آرٹ جسمِ انسانی کی بنیادی ساخت کے تابع ہے۔ ایک خطِ مستقیم ہے جو ریڑھ کی ہڈی کی مانند پوری تصویر کا بوجھ برداشت کرتا ہے اور جس طرح جسمِ انسانی میں تناسب موجود ہے یعنی ریڑھ کی ہڈی کے ایک سمت ایک ہاتھ ہوتا ہے اور دوسری سمت دوسرا ہاتھ یا دو آنکھیں اور دو پاؤں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان ملکوں کی تصویروں میں بھی تناسب پایا جاتاہے۔
مگر قدیم حجری دور کے انسانی معاشرے کے بارے میں ہماری معلومات اتنی مختصر اور ناکافی ہیں کہ اس عہد کے فن کے مقاصد و محرکات کی تہہ تک پہنچنا آسان نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آثارِ قدیمہ کے عالموں میں غاروں کی تصویروں، کندہ کارویوں اور مجسموں کی غرض و غایت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
بعض دانش وروں کا خیال ہے کہ یہ فن پارے دراصل وقت کاٹنے کے مشغلے تھے۔ بارش، برف باری یا شدید سردی میں لوگ جب غاروں میں بے کار بیٹھتے تھے تو دل بہلانے کی خاطر تصویریں بنایا کرتے تھے۔
اسی سے ملتا جلتا وہ دبستانِ فکر ہے جس کا خیال ہے کہ یہ تصویریں فقط ذوق جمال کی تسکین اور اظہارِ حسن کے جذبے کے تحت بنائی گئیں۔ ان تصویروں کا مقصد فقط غاروں کی آرائش و زیبائش تھی۔
مگران جمالیاتی اور تفریحی نظریوں کے خلاف بکثرت داخلی اور خارجی شہادتیں موجود ہیں۔
اوّل یہ کہ قدیم انسان نے یہ تصویریں ان غاروں میں نہیں بنائیں جن میں وہ رہتا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مصور غاروں میں بودو ماند کے کوئی آثار نہیں ملتے۔ وہاں نہ جانوروں کی ہڈیاں پائی گئی ہیں اور نہ کوئلے اور راکھ کے ڈھیر۔ اس کے برعکس فن کاروں نے بسا اوقات غیر آباد غاروں کے کسی نہایت تاریک اور تنگ گوشے کو چنا ہے۔ ان غاروں میں روشنی کا گزر نہ تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے انھیں رینگ کر جانا ہوتا تھا اور تصویر بنانے کے لیے زمین پر لیٹ کر کام کرنا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ تفریح کے لیے با ذوقِ جمال کی تسکین کے لیے کوئی اتنے پاپڑ نہیں بیلتا۔
دوسرے یہ کہ بکثرت تصویریں غاروں کے ایک مخصوص حصے میں ایک دوسرے کے اوپر بنائی گئی ہیں۔ حالاں کہ باکل قریب کی چٹانیں بالکل خالی پڑی ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہےکہ سحر پر اعتقاد رکھنے والے قدیم انسانوں کی نظر میں ان مخصوص جگہوں کی بڑی اہمیت تھی۔ یہ جگہیں بڑی سبھاگی تھیں۔ بڑی بخت آور تھیں۔ ایک کے اوپر دوسری تصویر بنانے کی روایت غالباً اس طرح پڑی ہوگی کہ پہلے کسی قبیلے نے اپنے سحر کے لیے غار کا ایک حصہ چنا ہوگا اور وہاں شکاری جانوروں کی تصویریں بنائی ہوں گی اور افزائشِ نسل اور ہلاکت نسل کے سحر میں کامیاب ہوئے ہوں گے یعنی جانوروں کی نسلیں بڑھیں ہوں گی اور شکار بھی افراط سے ہاتھ آیا ہوگا۔ اس قبیلے کے چلے جانے کے بعد دوسرا قبیلہ آیا ہوگا۔ اس متبرک مقام کا علم ممکن ہے اسے پہلے سے ہو یا وہ وہاں پہنچ کر اس راز سے آگاہ ہوا ہو۔ زیبائش و آرائش سے نہ تو اس کے پیش رؤوں کو کوئی دل چسپی تھی نہ نو واردوں کا مقصد زیبائش و آرائش تھا ورنہ وہ اپنے پش رؤوں کے شاہکار کو خراب نہ کرتے اور نہ پرانی تصویروں کے اورپر دوسری تصویریں بناتے۔ اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ ان کا افزائش نسل اور ہلاکت نسل کا سحر بھی اسی طرح کامیاب ہو جس طرح ان کے پیش رؤوں کا ہوا تھا۔
تیسرے یہ کہ اکثر دیواری تصویروں کے اردگرد عجیب و غریب اقلید سی علامتیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ علامتیں جمالیاتی اورفنی نقطہ نظر سے بہت بھونڈی اور بے جوڑ ہیں اور تصویروں کے حسن ترتیب و آہنگ سے میل نہیں کھاتیں اور نہ اصل تصویر کا جز معلوم ہوتی ہیں۔ دراصل سحر کے علاوہ ان علامتوں کی اور کوئی توجیہہ ہوہی نہیں سکتی۔ اسی طرح بہ کثرت تصویریں ایسی ہیں جن میں بھالے، نیزے، تیروغیرہ کے نشان بنے ہیں جو صاف بتاتے ہیں کہ فن کار نے شکار کے مناظر کی نقشہ کشی کی ہے۔ بہت سی مصور چٹانوں پر تو بھالے، نیزے اورتیراندازی کے نشان تک موجود ہیں، ان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تصویروں کی تکمیل کے بعد کسی خاص رسمِ سحر کے تحت ان پر ہتھیار پھینکے گئے تھے یا نشانے کی مشق کی گئی تھی۔
آلاتِ شکار پر بھی جانوروں کی تصویریں اسی سحر کے ماتحت بنائی گئی ہیں کیوں کہ برفانی دور کے انسان کا عقیدہ تھا کہ ہڈی، ہاتھی دانت اورپتھر کے آلاتِ شکار پر جانوروں کے نقش کھودنے سے اصل جانور آلات کے قابو میں آجاتے ہیں۔ہڑپا، موہن جودڑو، مصر، عراق اور ایران وغیرہ میں قدیم زمانے کے جو نقشی ظروف ملے ہیں ان کے نقوش کا تعلق بھی عمل سحر سے ہے۔ یہ ظروف سجاوٹ کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ اورنہ روز مرہ کے استعمال میں آتے تھے مگر اس بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برفانی دور کا انسان ذوقِ جمال یا جمالی ذوق سے خالی تھا۔اس کی فنی آگہی کا سب سے بڑا ثبوت اس کی تصویریں ہیں جن میں اس نے فن کے تمام تقاضے بڑی خوبصورتی سے پورے کیے ہیں۔ وہ ان تصویروں کو بڑی محنت اور محبت سے بناتا تھا۔ ان تصویروں میں خطوط کی روانی، اختصار اور سادگی ان کے لیے اثر انگیز اور معنی خیز رنگوں کا انتخاب، ان کی گہرائی ااور موزونیت غرض جس پہلو سے بھی دیکھئے ان قدی فن کاروں کے شعور کی داد دینی پڑے گی۔ ہونہار مصوروں کو باقاعدہ تصویر کشی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ برسوں مشق کرتے تھے تب کہیں انھیں متبرک مقامات پر تصویر بنانے کی اجازت ملتی تھی۔ گھٹیا درجے کی تصویریں رد کر دی جاتی تھیں۔ عمدہ تصویروں کے نمونے اور چربے دُور دُور بھیجے جاتے تھے یا محفوظ رکھ لیے جاتے تھے۔ یہ ساری کاوش و مشق، یہ ردد قبول ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا اپنا ایک معیارِ حسن اورمیزانِ فن ضرور تھا۔ البتہ وہ فقط زریعہ تھا اصل مقصد کی تسکین کا۔
بعض تصویریں ایسی ضرور ہیں جن کی حیثیت تاریخی یا یادگاری ہے۔ شاید ان کاتعلق قبیلے کی زندگی کے اہم حادثے سے ہو یا کوئی ایسا سانحہ پیش آیا ہو جس سے پورا قبیلہ متاثر ہوا ہو۔ مثلاً لیسکا کے غار میں موت کا منظر یا ریچھ اور آدمی کی لڑائی یا التمیرا کے سقف کی تصویریں۔
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برفانی انسان نے نمائندہ تصویریں کیوں بنائیں۔ تجریدی تصویریں کیوں نہیں بنائیں۔ پروفیسر ہینز کون کا خیال ہے کہ برفانی انسان کا ذہن فقط ٹھوس حقیقتوں کا تصور کرسکتا تھا۔ وہ جو کچھ دیکھتا تھا اس کے ہو بہو نقل بنا سکتا تھا، مگرابھی اس کے ذہن نے اتنی ترقی نہ کی تھی کہ وہ ان ٹھوس حقیقتوں کی تجرید کرسکے۔ وہ درختوں کو دیکھ سکتا تھا، مگر جنگل کا تصور نہ کرسکتا تھا پروفیسر ہیو گو اوبرمیئرؔ اور ایبے بروئیلؔ اس نظریے کو نہیں مانتے۔ وہ اپنی تائید میں آدمیوں کی وہ مجرد تصویریں پیش کرتے ہیں جو جانوروں کی نمائندہ تصویروں کی ہم عصر بلکہ ان کا جز ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ برفانی انسان ہو بہواور نمائندہ تصویریں بھی بنا سکتا تھا اور تجریدی عمل سے بھی واقف تھا اور حسب ضرورت ان دونوں طریقوں سے کام لیتا تھا۔ اس نے جانوروں کی نمائندہ تصویریں اس لیے بنائیں کہ ان پر آلات شکار کی مشق کرنی ہوتی تھی یا اس لیے بنائیں کہ ایک نئے اور حقیقی جانور کو اپنے سحر کے زور سے عدم سے وجود میں لانا تھا یا اسے ہلاک کرنا تھا۔ برفانی انسان کی مثال اس ریڈ انڈین کی ہے جس نے ایک آرٹسٹ کو بیسن کی تصویریں بناتے دیکھ کر شکایت کی تھی کہ تم نے ہمارے کئی بیسن اپنی کتاب میں بند کرلیے ہیں۔
برفانی دور کا انسان تین قسم کے سحر پر اعتقاد رکھتا تھا:
1۔۔۔۔ سحرِ تخلیق
2۔۔۔۔ سحرِ تخریب
3۔۔۔۔سحرِ رضا جوئی سے
ان میں سب سے قدیم تخلیق کا سحر ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ برفانی عہد کے سب سے پرانے فن پارے وہی ہیں جن کا تعلق تخلیق کے سحر سے ہے۔ یہ فن پارے عورتوں کے مجسمے ہیں۔ یہ مجسمے مشرق میں جھیل بیکال سے اسپین کی شمالی سرحد تک پائے گئے ہیں یعنی اس پورے خطے میں جو عہدِ قدیم میں برف سے ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ یہ مجسمے جن کی تعداد 130 سے تجاوز کر گئی ہے اسپین، فرانس، جرمنی ، اٹلی، آسٹریا، روس چیکو سلو واکیہ کے غاروں میں ملے ہیں۔ ان کی ساخت میں قبیلوں کی فنی روایتوں اور جغرافیائی حالات کے اختلاف کے باعث تھوڑا بہت فرق ضرور پایا جاتا ہے م گر اپنی نوعیت اور ماہیت کے اعتبار سے سب مجسمے یکساں ہیں۔ مثلاً پتھر کے یہ مجسمے قریب قریب سب ہی عورتوں کے ہیں اوران میں فن کار کی توجہ کا مرکز عورتوں کے جنسی اعضا ہیں۔ ان اعضا کو برے مبالغے کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے البتہ دوسرے اعضا کو مثلاً آنکھ، ناک، منھ کو نظرا نداز کردیاگیا ہے۔ یہ مجسمے بالکل برہنہ ہیں مگربعض مجسموں میں عورتیں زیور پہنے ہوئے ہیں۔ یہ مجسمے ” ماں” کے ہیں جو تخلیق کا سر چشمہ ہے۔
ان میں سب سے مشہور مجسمہ وہ ہے جو 1908ء میں وِلن دراف (آسٹریا) کے مقام پر دریافت ہوا۔ عورت کا یہ بت ساڑھے چارانچ بڑا ہے۔ اس کے سر کے بال شہد کے چھتے کی طرح ہیں۔ ان کی چھاتیاں مشک کی مانند پھولی ہوئی اور لوکی کی مانند نیچے کو لٹکی ہوئی ہیں۔ اس کے کولھے بہت چوڑے ہیں اور پیٹ بہت بڑا ہے۔ اس کی بانھیں بہت پتلی ہیں اورپیڑو پر رکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی کنواری لڑکی یا بانجھ عورت کا مجسمہ نہیں ہے بلکہ ایسی عورت کا مجسمہ ہے جو ماں بن چکی ہے یا بننے والی ہے۔ فنی اعتبار سے پونے چھ انچ کا وہ مجسمہ بھی نہایت حسین اور مکمل ہے جو جنوبی فرانس میں ملا ہے۔ یہ مجسمہ بھی عورت کا ہے جس کے جنسی اعضا کو بڑھا چڑھا کر بتایا گیا ہے۔ قدیم انسان کے لیے جنسی اعضا کو بالخصوص عورت کے جنسی اعضا کو تخلیق کی علامت قرار دینا قدرتی بات تھی۔ اس تخلیقی عمل میں مرد کے کردار کا انسان کو شاید شعور نہ ہو لیکن عورت کے بارے میں تو کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہ تھی کیوں کہ وضعِ حمل کے کچھ عرصے کے بعد عورت کے جسم میں تبدیلیاں ہونے لگتی تھیں اورایک دن جب مرد شکار سے واپس آتا تو غار میں اسے نومولود بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تخلیق کے یہی مظاہر اس نے جانوروں میں بھی دیکھے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے عقیدے میں عورت کی اہمیت مرد سے زیادہ تھی۔ لہٰذا عورت کا جسم تخلیق کی علامت بن گیا۔ اس وقت کے انسان کو خاندانی منصوبہ بندی کی ضرورت نہ تھی بلکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ افزائش نسل تھا کیوں کہ آبادی بہت کم تھی۔ موسم نہایت سخت تھا۔ برف کے طوفان آتے اور ٹھنڈی اور بھیگی ہواؤں کے تیر ہڈیوں میں پیوست ہو جاتے تھے۔ بچے موسم کی اس سخت گیری کی تاب نہ لا سکتے اور بیمار ہو کر مرجاتے۔ دوا علاج کا بھی کوئی انتظام نہ تھا نتیجہ یہ تھا کہ صغرسنی کی موت عام تھی۔ قبیلوں کے لیے اپنی زندگی کی بقا اوراپنی نسل کی افزائش اتنی ہی اہم تھی جتنی شکار کی تلاش۔ آبادی کی قلت کے باعث جنگلی جانوروں کے شکار میں بھی دشواری پیش آتی تھی۔ قبیلے کی آبادی زیادہ ہوتی تو شکار بھی زیادہ ہاتھ آتا تھا۔ آبادی کم ہوتی تو شکار بھی کم ملتا تھا اور جب شکار کم ملتا تو آبادی کی قوتِ مدافعت گھٹنے لگتی اور قبیلے کی تعداد اورکم ہو جاتی۔ غرض پورا معاشرہ بدی کے ایک چکر میں مبتلا تھا اوراس چکر سے نکلنے کی بس یہی صورت تھی کہ نسلِ انسانی میں جس طرح بھی ہو اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ افزائش نسل کے لیے مادرِ تخلیق کے مجسمے بنائے گئے تاکہ تخلیق کے سحر میں کام آسکیں۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ سحر کیا تھا۔ شاید عورت اور مرد مباشرت سے پہلے اس مجسمے کو چھوتے ہوں یا اپنے بعض اعضا کو اس پر رگڑتے ہوں یا جب عورت یا مرد سنِ بلوغ کو پہنچتا تو جادوگر ان کو پاس بٹھا کر کوئی منتر پڑھتا یا کوئی خاص رسم ادا کرتا۔ بعض پرانی قوموں میں اب بھی یہ رواج ہے کہ لڑکی کو جب پہلی بارحیض آتا ہے تو پوری بستی میں بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ لڑکی کو سرخ رنگ کی پوشاک پہنائی جاتی ہے کہ سرخ رنگ قدیم سے زندگی کی علامت ہے اورپھر سب لوگ اسے مبارک باد دیتے ہیں۔ یہ رسمیں اسی زمانے کی یادگار ہیں جب افزائشِ نسل ایک اہم سماجی عمل تھا۔ بہرحال برفانی انسان کے لیے یہ مجسمے تخلیق کی علامت تھے۔ اس سے غرض نہیں کہ وہ ان کو چھوتا تھا یا ان پر منتر پڑھتا تھا البتہ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ وہ ان مجسموں کی پرستش نہیں کرتا تھا کیوں کہ ابھی تک اس میں اپنے سے افضل و اعلیٰ کسی خارجی طاقت کا شعور پیدا نہیں ہوا تھا۔ ان غاروں میں جہاں یہ مجسمے تھے پرستش کے کوئی آثار بھی نہیں ملے ہیں نہ چڑھاوے کی چیزیں نکلی ہیں اورنہ قربانی کے نشان۔ البتہ کئی ہزار سال بعد جب آنے والی نسلوں نے دیوی دیوتا بنائے تو اس مادرِ تخلیق نے کہیں عشتار کا روپ دھارا اور کہیں وہ ناہید، اَشاء افرودیتی یا وینس کی شکل میں لوگوں کی عبادت کا مرکز بن گئی۔
مادرِ تخلیق کے یہ مجسمے تاریخی اعتبار سے سب سے قدیم ہیں اوران کا محرک نسلِ انسانی کی افزائش کا جذبہ ہے البتہ بعد میں جب آبادی بڑھ گئی اور نسلِ انسانی کی افزائش سے زیادہ جانوروں کی افزائش ضروری خیال کی جانے لگی تو عورتوں کے ان مجسموں کی جگہ حاملہ جانوروں کی تصویروں نے لےلی۔ چنانچہ اسپین اور فرانس کے غاروں میں حاملہ جانوروں کی کثرت ہے۔
نسل انسانی کی افزائش اور بقا کے علاوہ برفانی انسان کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اپنے قبیلے کے لیے غذا اور دوسری ضروریاتِ زندگی کیوں کر حاصل کی جائیں۔ یہ ضروریات زندگی فقط جانوروں کے شکار سے پوری ہوتیں تھیں شکار کی یہ مہمیں آج کل کے مرغابی یا ہرن کے شکار کی مانند نہ تھیں بلکہ ان میں جان جوکھم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جنگل میں شیر، بھالو، گینڈا اور دوسرے درندے ہوتے تھے۔ ہڈی کے تیر اورپتھر کے نیزے ان پر اثر نہ کرتے تھے۔ دوسرے جانور بھی مشکل سے ہاتھ آتے تھے۔ اس لیے شکار کی مہم سے پیش تر ہلاکتی یا تخریبی سحر کی ضرورت پڑتی تھی۔ کبھی وہ ایک رسم کے تحت دیوار پر بنی ہوئی تصویروں پر تیر، نیزے اور بھالے مارتے تھے (اس نشان بازی کے نشان تصویروں پر اب تک موجود ہیں) اوران کو یقین ہو جاتا تھا کہ ان کا شکار ہلاک ہوگیا یا ہو جائے گا۔ کبھی ساحرا نہیں ان تصویروں کے رو برو لے جاتا تھا جن میں جانوروں کو جال میں پھنسا ہوا یا سحر کے اثر سے بے بس اور لاچار دکھایا گیا ہے یا جن کے جسم پر زخم کے نشان بنے ہیں اور وہ خون آلود ہیں یا جن کے جسم میں آلاتِ شکار پیوست ہیں۔ ان رسموں کے بعد شکاری بڑی خوداعتمادی اور یقین سے اپنی مہم پر روانہ ہو جاتے تھے۔ اگر کامیاب لوٹے تو سحر کی گرفت ان کے ذہنوں پر اور مضبوط ہو جاتی تھی۔ ناکام ہوئے تو اپنے آپ کو یہ کہہ تسلی دے لیتے تھے کہ ادائیگی رسم میں ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو گی۔
رضا جوئی کا سحر درندوں اور دوسرے خطرناک جانوروں کی خوشنودی کےلیے مخصوص تھا۔ برفانی انسان ان درندوں کو ہلاک کرتے ڈرتا تھا کہ مبادا وہ یا ان کی نسل خفاہوکر ہمیں کوئی گزند پہنچا دے چنانچہ یہ لوگ شکاری درندوں کو مارنے کے بعد ایک رسم کے تحت ان کی خوشامد کرتے تھے تاکہ ان کی خفگی دور ہوجائے۔ فرانس کے ایک غار میں مٹی کا بنا ہوا ریچھ کا ایک مجسمہ ملا ہے جس کا سر ندارد ہے البتہ اس کی گردن کے پاس خون کے نشان ہیں اور آس پاس کئی ریچھوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ علمائے آثار نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ برفانی انسان ریچھ کا شکار کرنے بعد اس کا سر (جسے وہ جسم کا سب سے اہم حصہ سمجھتا تھا) مٹی کے دھڑ سے جوڑ دیتا تھا اور یہ سمجھ لیتا تھا کہ ریچھ کو اس کے ہاتھوں کوئی ضرر نہیں پہنچا ہے بلکہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ تب وہ ریچھ کے جسم کو کھا لیتا تھا اور اس کی کھال سے اپنے لیے پوشاک تیار کرتا تھا۔ کتنا کارآمد تھا یہ سحر۔ التمیرا کے سقف میں اسی طرح بیسنوں کی رضا جوئی کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔ چین اور جاپان کی پرانی رسم ہے کہ باورچی سبزیوں کو پکانے سے پہلے میز پر قرینے سے سجا دیتے ہیں اوران کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر اورہاتھ جوڑ کر سبزیوں سے معافی کی دعا مانگتے ہیں۔
قدیم حجری دورکے ہم پر برے احسانات ہیں۔ اُس دَور میں انسان جانور سے آدمی بنا۔ تہذیب کی ابتدا ہوئی، آدمی نے آگ کا استعمال معلوم کیا، آلات اور اوزار بنائے، تسخیر قدرت کی کوششیں شروع کیں اور مادے کی ہیئت و ماہیت میں تبدیلیاں کرکے سائنس کی جانب پہلا قدم اٹھایا۔اس نے مصوری اورمجسمہ سازی جیسےدو نہایت دل کش فن ایجاد کیے۔ حجری انسان کی فنی تخلیقات کی دریافت سے ہمارے تہذیبی سرمائے میں گراں قدر اضافہ ہی نہیں ہوا بلکہ جدید انسان کا نقطہ نظر بھی بدلا ہے۔ ان دریافتوں سے پیشتر دورِ حاضر کے لوگ حجری دَور کے انسانوں کو جنگلی اور وحشی خیال کرتے تھے اوران کو جمالیاتی ذوق اور لطیف احساسات سے قطعاً عاری سمجھتے تھے۔ غاروں کے حسین نقوش نے ثابت کردیا کہ حجری انسان کا تخلیقی شعور بیدار ہو چکا تھا۔ اس کا عزم جوان تھا اورہمت شکن حالات کے آگے سپر ڈالنے کے بجائے وہ بڑی خود اعتمادی سے ان حالات کا مقابلہ کرتا تھا اوران کو بدلنے میں حتی المقدور کامیاب بھی ہوتا تھا۔
غلطی ہائے مضامین
مولانا کوثر نیازی کی ذاتِ گرامی سے میں 1953ء سے واقف ہوں۔ مولانا ممدوح تحریکِ ختمِ نبوت ؐ کے سلسلے میں گرفتار ہوکر لاہور سینٹرل جیل تشریف لائے تھے۔ اس وقت ان کا تعلق جماعتِ اسلامی سے تھا۔ سیاست میں ہر چند کہ ہماری راہیں جدا تھیں لیکن جیل سے نکلنے کے بعد بھی ہم ایک دوسرے سے ملتےرہے، کبھی لاہور میں اورکبھی کراچی میں۔ پھر یوں ہوا کہ مولانا مرکزی حکومت میں وزیر ہوگئے۔ اب کہاں ایک مقتدر وزیر کی بلند پروازیاں اورکہاں ایک پاشکستہ خاک نشین کی درماندگیاں، ملاقات کے تمام امکانات ختم ہوگئے۔ مولانا کی بے پناہ مصروفیتوں نے ان کو کبھی اتنی فراصت نہ دی کہ ایک پرانے رفیق ِ زندان کو یاد کریں اور یہاں یہ شرم دامن گیر کہ غرض مندروں کی طرح دربار میں جائیں تو درخواست میں لکھیں کیا۔ کاغذ کی فراوانی ضرور تھی لیکن کاغذی پیرہن پہننا ہم کو آتا نہیں لہٰذا ہم کبھی راہ میں ملے نہ مولانا نے ہم کو اپنی بزم میں بلایا۔
اب حسنِ اتفاق کہیے یا سوء اتفاق کہ جن دنوں میں نفسیاتی ڈاکٹروں کی کانفرنس کے لیے مقالہ لکھ رہا تھا (تہذیب کا اثر ہمارے خیالات پر) تو اخبار جنگ میں مولانا کوثر نیازی کا ایک مضمون نظر سے گزرا۔ اس مضمون میں مولانا نے کہ شاعر شیریں سخن بھی ہیں مولانا مفتی محمد شیخ مرحوم سے عقیدت کے جوش میں ایک جن کا قصہ کیا لکھا کہ مجھ کو ” خوباں” سے چھیڑ کا بہانہ ہاتھ آگیا۔ میں سمجھا تھا کہ جس طرح بچے جن پری کے قصوں کوفرضی حکایت جان کر پڑھتے ہیں مولانا نے بھی مفتی صاحب کی داستان جن کا قصہ سمجھا ہو گا مگر نہیں جناب، مولانا کوثر نیازی توقرآن، حدیث اور مشرق و مغرب کے علماء کے اقوال زریں سے جنوں کا وجود ثابت کرنے بیٹھ گئے۔ اِدھر ہم ہیں کہ اپنی حرکت پر نادم۔ عقیدت کے رنگین محل میں جس پر منقولات کا پورا لشکر پہرہ دے رہا ہو مجھ سے بد عقیدہ کا گزر کہاں ہو سکتا ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا نے جنوں کی بحث اس لیے چھیڑی ہے کہ وہ اُن مسائلِ زندگی پر جن سے ہم دو چار ہیں کچھ لکھنا خلافِ مصلحت خیال کرتے ہیں۔
مولانا کوثرنیازی نے مفتی محمد شفیع مرحوم کے حوالے سے جن کا جو قصہ بیان کیا اس سے یہ تو پتہ چلا کہ یہ جن صاحب بڑی مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک تھے اور بحمداللہ مسلمان بھی تھے لیکن یہ راز نہ کھلا کہ موصوف ایک بزرگ عالمِ دین کی زوجہ محترمہ کی طرف جو پردہ فرماتی تھیں کیوں متوجہ ہوئے اوران کی اس غیر شرحی حرکت کا جواز کیا تھا۔
میرا مقالہ چونکہ ذہنی امراض کے ڈاکٹرو ں کے لیے تھا لہٰذا میں نے مثالیں دے کر بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو مختلف تو ہمات رائج ہیں ان سے سیدھے سادے عقیدت مندوں کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ مثلاً یہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا جس میں ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کردو چنانچہ انھوں نے سنتِ ابراہیمی کی تقلید میں بیٹے کو ذبح کردیا۔ اسی طرح ایک بانجھ عورت نے کسی کے کہے میں آکر اپنے پڑوسی کے بچے کو قتل کیا اوراس کے خون سے نہائی تاکہ صاحبہ اولاد ہوجائے۔ میں نے لکھا تھا کہ بہ ظاہر یہ دیوانوں کے افعال ہیں لیکن درحقیقت ایک بڑے سماجی مرض کی نشان دہی کرتے ہیں اور وہ مرض ہے توہم پرستی کا جور وز بروز بڑھتا جارہا ہے۔ مولانا کوثر نیازی کو شاید علم نہ ہو کہ فقط شہر کرامی میں ذہنی مریضوں کی تعداد پچاس ہزار کے قریب ہے۔ میں ان پیٹ بھروں کا ذکر نہیں کررہا ہوں جو اعصابی بیماریوں کا شکار ہیں بلکہ کم استطاعت لوگوں کا جو کسی شدید صدمے، حادثے یا گھریلو پریشانیوں کے سبب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ میرے ایک دوست نے حال ہی میں ایک دستاویزی فلم ” آسیب زدوں” پر بنائی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا مریضوں کو ان کے خوش عقیدہ اعزاواقربا ایک درگاہ سے دوسری درگاہ اور آسیب اُتارنے والے ایک بزرگ کے آستانے سے دوسرے بزرگ کے آستانے پر لیے پھرتے ہیں اور ذہنی امراض کے اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس آخر میں اس وقت پہنچتے ہیں جب مرض لا علاج ہو چکتا ہے۔ کیا کسی کو یقین آئے گا کہ اس “ترقی یافتہ” شہر میں آسیب اُتارنے والے اصحاب کے اپنے نجی “قید خانے” بھی ہیں جن میں ہمارے بد نصیب مجنوں زنجیروں بیڑیوں سے بندھے زمین پر بے حس و حرکت پڑے رہتے ہیں اور ہزاروں مکھیاں ان کے جسموں پر بھنبھناتی رہتی ہیں۔ اس دستاویزی فلم کی ہر تصویر سچی ہے اور مولانا اگریہ فلم دیکھ لیں تو شاید پھر کبھی جنوں کا ذکر نہ کریں ۔
نفسیات کے ڈاکٹروں سے گفتگو کیجئے تو وہ اپنے مریضوں کے بیان کردہ ایسے ایسے ” سچے” واقعات کا ذکر کریں گے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ لطف یہ ہے کہ ہر مریض بڑے خلوص سے یہی کہے گا یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا یہ سانحہ خود پر گزرا ہے۔ یہ تو خیر دیوانوں کی بڑ ہوئی۔ اگرآپ کسی بھلے چنگے شخص کو جس کو سراب کی اصل حقیقت نہ معلوم ہو ریگستان میں دوپہر کے وقت کھڑا کردیں تو اس کو ہر طرف پانی سے بھری جھیلیں نظر آئیں گی اوروہ قسم کھاکر کہے گاکہ میں نے فلاں ریگستان میں جھیلیں دیکھی ہیں۔
طب کی پرانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں کو بیماریوں کے اصل اسباب معلوم نہ تھے۔ ان کا راسخ عقیدہ تھا کہ انسان کے جسم میں جب کوئی عفریت یا بھوت داخل ہو جاتا ہے تو وہ بیمار پڑجاتا ہے لہٰذا ہر بیماری کا علاج خواہ و زکام اور بخار ہو یا یرقان اور مرگی جادو منتروں سے ہوتا تھا۔ علاج کرنے والے یہ جادوگر “طبیب” عبادت گاہوں کے پروہت ہوتے تھے۔ چنانچہ اہلِ بابل کی عکادی زبان میں طبیب، پروہت اورجادوگر، تینوں کے لیے ” آزو” اور “ایازو” کی اصطلاحیں استعمال ہوتی تھیں۔ سحر اور طب میں کوئی فرق نہ تھا۔ پھر رفتہ رفتہ جادو منتروں کے ساتھ دوائیں بھی استعمال ہونے لگیں اور دواؤں کا پلہ بھاری ہوتا گیا لیکن یونانی طب کے فروغ سے قبل تک قدیم مصر اور بابل میں جادو منتر علاج کا لازمی جز سمجھے جاتے تھے۔ مثلاً مصری آثارِ قدیمہ کی کھدائی میں پندرھویں صدی قبل مسیح سے سن عیسوی کی ابتدا تک کے بے شمار خریطے ملے ہیں جن پر امراض اوران کے علاج کی ترکیبیں درج ہیں۔ ان سب کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ بیمار پر کوئی عفریت سوار ہے یا کوئی بد روح اس میں گھس گئی ہے لہٰذا علاج تجویز کرنے والا جادو گر طبیب یہ نہیں لکھتا کہ ” یہ نسخہ” فلاں بیماری کا ہے۔” بلکہ یہ لکھتا ہے کہ یہ نسخہ عفریت کو ” مار بھگانے ” کا ہے یا ” ڈرانے دھمکانے” کا ہے یا “ہلاک کرنے” کا ہے۔
مگرجوں جوں علم طب نے ترقی کی ، بیماریوں کے اصل اسباب پتہ چلے اوران سے شفا پانے کے لیے دوائیں دریافت ہوتی گئیں تو لوگوں نے اپنے تجربے سے دیکھ لیا کہ بیماریوں کا علاج جادو منتر ، ٹونے ٹوٹکے جھاڑ پھونک سے نہیں ہوتا بلکہ دواؤں سے ہوتا ہے لہٰذا لوگوں کا اعتقاد ان توہمات پر سے اٹھتا گیا لیکن اب بھی ہزاروں لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں عقیدت مند ایسے ہیں جو علاج کے قدیم طریقوں پر یقین رکھتے ہیں نتیجہ یہ ے کہ آپ کو ہر شہر، قصبے اور دیہات میں ایسے پیر فقیر مل جائیں گے جن کا جھاڑ پھونک کا کاروبار انھیں توہمات کے طفیل چلتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جن بھوت ان لوگوں کو بالکل نہیں ستاتے جو ان کے وجود کو سرے سے مانتے ہیں نہیں حالاں کہ اس بد اعتقادی کی سزا سب سے پہلے انھیں کو ملنی چاہیے نہ کہ ان سیدھے سادے لوگوں کو جو ان قوتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔
جن بھوتوں کا عقیدہ دراصل قدرت کی ظاہرہ اور ان دیکھی قوتوں کے تجسیمی تصور ہی کی ایک شکل ہے۔ ابتدائی انسان ان قوتوں کو۔۔۔ سورج چاند، ہواطوفان، بادل کی گرج، بجلی کی چمک، سیلاب، آندھی، زلزلہ وغیرہ۔۔۔ اپنی ہی طرح جان دار، فعال اور با ارادہ سمجھتا تھا۔ جو قوتیں اس کو فائدہ پہنچاتی تھیں ان کو وہ خیر اورنیکی کی قوتوں سے تعبیر کرتا تھا اوران کو پیارکرتا تھا۔ اس کے برعکس جو قوتیں اس کو نقصان پہنچاتی تھیں ان کو وہ بدی اور شرکی قوتیں خیال کرتا تھا اور ان سے ڈرتا تھا۔ چنانچہ مصر و بابل ، یونان و ایران ، ہندوستان و چین ہر جگہ ان قوتوں کو دیوی دیوتا کا روپ دے دیا گیا اور بری قوتیں کہیں یم کہلائیں، کہیں قیامت، کہیں اہرمن اور کہیں موت۔ یہ دیوی دیوتا انسانوں ہی کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے عادات و اطوار بھی انسانوں کے سے تھے۔ شادی بیاہ، آل اولاد، محبت نفرت، دشمنی دوستی، غرض یہ کہ دیوی دیوتاؤں کی دنیا کسی انسانی جذبے سے خالی نہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ انسانوں کے معاملات میں بھی دخل دیتے تھے چنانچہ ٹرائے کی دس سالہ جنگ میں کوہ اولمپس کے بعض دیوتا ایک فریق کی حمایت کرتے اور بعض دوسرے فریق کی۔ اسی طرح رگ وید کے بقول جب آریا قوموں نے وادیِ سندھ پر حملہ کیا تو اِندر دیوتا نے اشوروں اور پانٹریوں کو ہرانے میں آریوں کی سپہ سالاری کی۔ افسوس ہے کہ کوہِ اولمپس کے دیوی دیوتا یورپ میں عیسائیت کے رواج پاتے ہی یکسر غائب ہوگئے حالاں کہ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں ان کا وجود “حقائق ثابتہ” میں شمار ہوتا تھا یہاں تک کہ سقراط کو دیوتاؤں کے انکار کے جرم میں زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا اور اس کے ہم عصر فلسفی انکسا غورث اور ڈرامہ نویس یوری پڈتیرایتھنز سے جلا وطن کردیے گئے تھے۔ مصر ، لبنان و فلسطین، عرب اور ایران، ہندوستان اور چین اور غرض یہ کہ پرانی دنیا کے تمام دیوی دیوتا جو ہزاروں سال تک اپنے عقیدت مندوں کو اپنے وجود کا ثبوت فراہم کرتے رہے آج فقط دیو مالائی داستانوں میں زندہ ہیں۔
مولانا کوثر نیازی نے برسبیلِ تذکرہ جنوں اور انسانی عورتوں کے درمیان “نکاح” اور ” طلاق” کی بات بھی کی ہے۔ معلوم نہیں کہ اس شادی خانہ آبادی سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی یا اب بھی ہوتی ہے اس کا شمار جنوں میں ہوگا یا انسانوں میں۔بہرحال مافوق الفطرت اشخاص کا زمین پر رہنے والی عورتوں سے جذباتی لگاؤ بھی دیو مالائی دَور ہی کا قصہ ہے۔ کوہِ اولمپس کے دیوتاؤں کی عاشق مزاجی تو مشہور ہے۔ کسی خوش جمال لڑکی کو باغ میں ٹہلتے یا چشمے کے کنارے نہاتے دیکھا تو جھٹ اس سے جنسی رشتہ قائم کرلیا۔ چنانچہ یونان کے کتنے ہی ہیرو زیوس یا اپالو کی اولا دکہے جاتے تھے۔ اسی طرح مہابھارت کی رانی کنتی کا پہلا بیٹاکرن سورج دیوتا کے نطفے سے تھا بلکہ بلکہ راجپوتانہ کے راجے مہاراجے ابھی کل تک سورج بنسی اور چندر بنسی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ پھر جنوں نے کیا قصور کیا ہے جو ہماری بہو بیٹیوں پر فریفتہ نہ ہوں۔
پرانی قوموں کے عقائد و اوہام کے تذکرے سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ مافوق الفطرت قوتوں بالخصوص جنوں کے وجود کا تاریخی اور معاشرتی پس منظر واضح ہو جائے۔ جنوں کا وجود بھی دراصل سی شجرِ تخیل کی ایک شاخ ہے جو عہد قدیم میں خوب پھلا پھولا لیکن انسان جوں جوں قدرت اور قوانین قدرت سے آگاہ ہوتا گیا ، جوں جوں سائنسی علوم اور تجربات و مشاہدات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا دیوی دیوتاؤں، جنوں پر یوں کا دائرہ عمل و اختیار بھی تنگ ہوتا گیا۔
مولانا کوثر نیازی کا یہ ارشاد بالکل درست ہے کہ ” نامعلوم جہانوں اوراجنبی مخلوقوں تک علمی رسائی حاصل کرنے کی کوشش بجائے خود وقت کا کوئی برا مصرف نہیں۔ ” چنانچہ معلوم سے نا معلوم تک پہنچنے کی تگ و دو سائنس دانوں کا صدیوں سے مستقل مشغلہ رہا ہے۔ ہم مولانا کو بھی بلا پس و پیش اپنے عہد کا سائنس دان محقق مان لیتے اگرانھوں نے منقولات پر تکیہ کرنے کے بجائے سائنسی طرز فکرو عمل اختیار کی ہوتی اور عقلی دلائل اور سائنسی تجربوں سے جنوں کے وجود کو ثابت کیا ہوتا مگرانھوں نے توائمہ، علماء، فقہا اور صوفیا کے علاوہ مغربی مصنفین کے اقوال کا ایک پورا دفتر پیش کردیا اور تب ہم کو جنوں کے بے شمار عادات و خصائل کا علم ہوا۔ مثلاً یہ کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں اور ہزاروں میل کا سفر پلک جھپکتے طے کرلیتے ہیں وہ آگ سے بنے ہیں۔ ان میں بعض مسلمان ہیں اور بعض غیر مسلمان، وہ ہماری عورتوں سے شادی کرتے ہیں اورپھر ان کو طلاق بھی دیتے ہیں۔ وہ ہم سے چمٹ جاتے ہیں اور ہم کو ستاتے ہیں (البتہ ان کے اس طرز عمل کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے۔ یہ نہیں معلوم) مگرافسوس ہے کہ ان “حقائقِ ثابتہ” کی تائید میں بے شمار کتابی کتابی شہادتیں پیش کرنے کے باوجود مولانا نے کوئی ایک عقلی دلیل بھی جنات کے وجود کے حق میں نہ دی۔
حقیقت یہ ہے ک ہ جنوں کے وجود کا تعلق عقائد سے ہے نہ کہ عقل سے۔ برطانوی فلسفی جان لاک کے بقول عقیدہ وہ شے ہے جس کو اس کی سچائی ثابت ہونے سے پیش ترہی تسلیم کرلیا جائے۔ عقیدے کی پرورش ماں کی گود میں نشوونما گھریلو روایات اور معاشرتی ماحول میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایتوں کے ماحول میں پرورش پانے والا بچہ عموماً اسلامی عقائد کا پابند ہوتا ہے، ہندو ماحول کا بچہ ہندو اور یہودی ماحول کا بچہ یہودی ہوتا ہے۔ تعلیم پاکر بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ علم سے اپنے عقیدوں کا جواز پیدا کریں یا علم اور عقیدے کو ہم آہنگ کرلیں۔ عقائد کی چھاپ ہمارے جذبات و احساسات پر اتنی گہری ہوتی ہے کہ ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو ہم مشتعل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ان عقیدوں کو منقولات سے بڑا سہارا ملتا ہے۔
لیکن جب ہم عقیدے کی دنیا سے عقل کی دنیا میں آتے ہیں تو “کیا”، “کیوں” اور “کیسے” کے بے شمار سوالات ہم کو ستانے لگتے ہیں بقول غالبؔ
شکنِ زُلفِ عنبرین کیون ہے
نِگہ چشم سرمہ سا کیا ہے؟
سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں
ابرکیا چیز ہے ، ہوا کیا ہے؟
عقیدے کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ کیوں کہ عقیدہ نام ہے تسلیم و رضا کا، اقرار و تقلید کا، روایتوں کے احترام کا۔ اس میں “کیوں”، “کیسے” کی گنجائش نہیں۔ وہ ہم کو ” مان لینے” کی تلقین کرتا ہے اور بحث ، شک اور انکار سے منع کرتا ہے کیوں کہ یہ رحجان اس کے حق میں مفید نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس عقل کا مدار شعور اگہی پر ہے۔ شعور و آگہی کی اساس عملی تجربے اور مشاہدے ہوتے ہیں۔ انھیں کی مدد سے انسانی عقل نے بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیے ہیں۔ نئی نئی دریافتیں اور ایجادیں کی ہیں، وہ چیزیں بنائی ہیں جو کائنات میں موجود نہ تھیں بلکہ قدرتی اشیا ہی سے ایک نہایت عظیم الشان مصنوعی دنیا تعمیر کرلی ہے۔
مولانا کوثر نیازی کا طرزِ استدلال ” منقولاتی” ہے۔ سائنسی یا عقلی نہیں، یعنی کسے شے کا وجود ثابت کرنے کے لیےوہ علما، فقہا، صوفیا کی شہادتوں پر بھروسہ کرتےہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ:
“جنوں کا وجود، انسانوں کو ان کا تکلیف پہنچانا اور بزرگانِ دین کا ان کو مسخر کرلینا علماء اور فقہا ہی میں نہیں صوفیا کے طبقے میں بھی مسلم رہا ہے اور اس میں ایسی ایسی شخصیات کے نام شامل ہیں جن کی صداقت اور تقدس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ”
گویا کسی شے کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے معتبر اور مقدس علماء ، فقہا اور صوفیا وغیرہ کی تائیدی شہادتیں کافی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم مان لیں کہ زمین ساکت و قائم ہے اور چاند سورج سیارے سب زمین کر گرد گھومتے ہیں اس لیے کہ کپلر اور گلیلو کی دریافت سے پیش تر مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی، بودھ، پارسی غرض یہ کہ تمام دنیا کے “بزرگان دین علما، فقہا، صوفیا” حتیٰ کہ قرآن حکیم کے مفسرین متفقہ طور پر یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ چاند، سورج، ستارے، سیارے سب زمین کے گرد طواف کرتے ہیں اور کائنات کا مرکز زمین ہے۔
مولانا کوثر نیازی ارسطو کے مقام اور مرتبے سے ضرور واقف ہوں گے۔ وہی ارسطو جس کو دنیائے اسلام ” معلم اول” کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ یہ عظیم فلسفی اور سائنس دان ڈیڑھ ہزار برس تک مغربی دنیا کے خیالات و عقائد پر حکمرانی کرتا رہا۔ خود کلیسائے روم کی نظروں میں ارسطو کے مفروضات اور نظریات کا رتبہ انجیل مقدس سے کم نہ تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ارسطو کے دعوؤں پر شک کرسکے۔ چنانچہ کپلر نے(جو خود پادری تھا) علم ریاضی کی مدد سے اور گلیو نے اپنی دُور بین کے شواہد سے جب یہ ثابت کردیا کہ ارسطو اور بطلیموس کے مفروضات غلط ہیں اور نظامِ شمسی کا مرکز سورج ہے نہ کہ زمین تو ایوانِ کلیسا میں تہلکہ مچ گیا۔ گلیلو کو روم کی مذہبی عدالت میں طلب کیا گیا اور حکم ہوا کہ اس کفر سے توبہ کرو ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گلیلو بے چارے نے موت کے ڈر سے توبہ کرلی مگرچپکے سے کہا کہ میں مانوں یہ نہ مانوں زمین تو برابر گھومتی رہے گی۔
سائنسی طرزِ استدلال ” منقولاتی” نہیں بلکہ تجرباتی ہوتا ہے۔ سائنس کسی شے کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نیوٹن اورآئن سٹائن ، ڈارون اور پرلیٹلے کی شہادتوں کا سہارا نہیں لیتی بلکہ تجربوں سے ثابت کرتی ہے اور تجربے بھی وہ جس میں ساری دنیا کو شریک کیا جا سکے اور ہر شخص ان کی سچائی کو اپنے ذاتی تجربے سے پرکھ سکے۔ مثلاً یہ دعویٰ کہ پانی دو گیسوں (ہائیڈروجن اور آکسیجن) سے مل کر بنا ہے ایک ایسے تجربے کی بنا پر ہے جو اسکول کا لڑکا بھی کرسکتا ہے اوراگر کوئی شخص انکار کرے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم ایک بوتل میں ہائیڈروجن لو اور دوسری میں آکسیجن، پھر دونوں گیسوں کو ملا دو پانی بن جائے گا۔ اسی طرح اگرکوئی شخص ہوا کے وجود سے انکار کرے تو معمولی سے عملی تجربے سے نہ صرف ہوا کا وجود ثابت ہو سکتا ہے بلکہ یہ بھی کہ ہوا میں وزن ہوتا ہے اور وہ جگہ گھیرتی ہے۔ چنانچہ بچوں کی چوتھی جماعت میں بھی یونان کے ڈھائی ہزار برس پرانے نیچری فلسفی ایمپوڈا کلیز کے مشہور تجربے کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً ایک خالی غبارے کو وزن کرلو پھراس میں ہوا بھر کر وزن کرو۔ ہوا سے بھرا ہوا غبارہ خالی غبارے سے زیادہ وزنی ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ ہوا میں وزن ہوتا ہے۔ اب ایک خالی بوتل لیں اور اس کو اُلٹا کرکے پانی سے بھری بالٹی میں سیدھا ڈبوئیں۔ پانی کا ایک قطرہ بھی بوتل میں نہ جائے گا کیوں کہ بوتل میں ہوا موجود ہے۔ اب آپ بوتل کو تھوڑا سا ٹیڑھا کردیں۔ پانی میں بلبلے اٹھنے لگیں گے اور تھوڑی دیر میں بوتل پانی سے بھر جائے گی کیوں کہ بوتل کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے ہوا کو باہر نکلنے اور پانی کو بوتل میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ پس ثابت ہوا کہ ہوا جگہ گھیرتی ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر موجودات کی دو ایسی مثالیں چنی ہیں جو نظر نہیں آتیں (پانی کا ہواؤں سے بننا اور ہوا میں وزن کا ہونا)
وجہ یہ ہے کہ ہم کو مولانا کے اس ارشاد سے بحث کرنا ہے کہ کسی شے کا نظر نہ آنا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا۔ مولانا کے دس کالم کے مضمون میں جو منقولاتی شہادتوں سے پر ہے یہ ایک واحد عقلی دلیل ہے اور ہم کو اس سے پورا پورا اتفاق ہے۔ مثلاً ہم کو خوشبو نظر نہیں آتی، برقی توانائی نظر نہیں آتی، کشش زمین نظر نہیں آتی، حرارت نظر نہیں آتی، زمین گھومتی نظر نہیں آتی بلکہ سورج چاند گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر بھی ہم ان حقیقتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے وجود کا عملی تجربوں سے مظاہرہ کرسکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پانی اور ہوا کے ضمن میں کیا لیکن مولانا کا کہنا ہے کہ کسی شے کا نظر نہ آتا عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا البتہ وجود کی دلیل بن سکتا ہے۔ اس دلیل میں جو منطقی مغالطہ پوشیدہ ہے مولانا نے شاید اس پر غور نہیں فرمایا۔ حالاں کہ جس طرح کسی شے کا نظر نہ آنا عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا اسی طرح وجود کی دلیل بھی نہیں بن سکتا۔ وجود کے صرف وجود سے ثابت کیا جا سکتا ہے عدم وجود سے ہر گزنہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ” آفتاب آمد دلیل آفتاب۔” حقیقت یہ ہے کہ کسی شے کے وجود کا انحصار ہم کو نظر آے یا نظر نہ آنے پر ہے ہی نہیں۔ نظر آنا تو ایک طرف رہا، قدرتی اشیا کے وجود کا انسان کے وجود سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ تو انسان کے وجود سے لاکھوں برس پہلے بھی موجود تھیں۔
مگر مولانا نے اس منطقی مغالطے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک اور منطقی مغالطے میں الجھ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ” کتنے حقائق تھے جو پچھلی صدی کے لوگوں پر منکشف نہ ہوئے تھے آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کیا پچھلی صدی کے لوگوں کا محض اس بنا پر انھیں رد کردینا کہ وہ انھیں نظر نہیں آئے ان کے عدم وجود کی دلیل بن سکتا ہے؟” اس دلیل میں مولانا نے اشیا کے موجود ہونے کو ان کے منکشف یا دریافت ہونے سے گڈ مڈ کردیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انیسویں صدی کا انسان ہو یا بیسویں صدی کا کسی حقیقت کے منکشف یا دریافت ہونے سے پیش تر اس کے وجود کو یقینی طورپر کس طرح تسلیم کرے گا۔ بے شمار جراثیم ایسے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے تھے مگر وہ موجود تھے البتہ جب سائنس دانوں نے خوردبین کے ذریعے ان کے وجود کو دریافت کرلیا تو ہر شخص کو ان کا وجود تسلیم کرنا پڑا لیکن ان کی دریافت سے پہلے انسان زیادہ سے زیادہ قیاس آرائی کرسکتا تھا۔ وہ یہ دعویٰ کیسے کرتا کہ جراثیم موجود ہیں اور دعویٰ کرتا تو ثابت کیسے کرتا۔ قدرت کے خزانے میں اب بھی بے شمار ایسی چیزیں ہوں گی جن کا ہم کو علم نہیں لیکن کوئی شخص اگریہ دعویٰ کرے کہ زمین کے اندر شترمرغ کے انڈوں کے برابر موتی پوشیدہ ہیں تو ان موتیوں کے وجود کا بارِ ثبوت اس کی گردن پر ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتا کہ تم کو کیا معلوم زمین کے اندر ابھی کیا کیا پوشیدہ ہے۔ میں اس سے الٹ کر یہ سوال بھی کرسکتا ہوں کہ مجھ کو تو واقعی نہیں معلوم مگرتم کو کیسے معلوم ہوا۔ اس کے علاوہ میں کسی ماہرِ ارضیات سے پوچھ سکتا ہوں کہ موتی کن مادی اشیا سے بنتا ہے، کیا زمین کے اندر یہ اشیا موجود ہیں اورکیا زمین کہ تہوں کے درجہ حرارت میں موتیوں کی تشکیل ممکن ہے۔ اگرجواب نفی میں ملا تو میں شتر مرغ کے انڈوں کے برابر موتی کے زمین میں موجود ہونے سے انکار کردوں گا۔
لیکن جنوں کے سلسلے میں وجود اور عدم وجود کی بحث فضول ہے کیوں کہ مولانا جنات کے وجود کو یقینی طورپر تسلیم کرتے ہیں۔ وہ جنوں کے وجود کو ثابت تو نہ کرسکے البتہ انھوں نے کتابوں کے حوالے سے جنوں کے بعض خصائل ضرور بیان کردیے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگروہ اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے سے یا کتابوں کے حوالے سے ہم کو یہ بھی بتا دیتے کہ جنوں کی خوراک اور پوشاک کیا ہے۔ وہ رہتے بستے کہاں ہیں، زمین پر، ہوا میں یا آسمان پر۔ انسانوں کی طرح کیا ان کی بھی گھریلوزندگی ہوتی ہے اور یہ کہ سیدھے سادے بے قصور انسانوں کو ستانے کے علاوہ ان کے اور مشاغل کیا ہیں۔ یہ سوالات میں نے طنز و استہزا کے طورپر نہیں کیے ہیں بلکہ مخلوقات اگرجان دار اور باشعور ہیں تو ان کے بارے میں اس قسم کے سوالات کا اٹھنا قدرتی امر ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جن ہر چند کہ آگ سے بنے ہیں پھر بھی ہم کو نظر نہیں آتے حالاں کہ آگ اپنی مختلف شکلوں میں ہم کو نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ چنگاری بھی جو پتھروں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یہ عرض کرنا بے محل نہ ہوگا کہ آگ بذاتِ خود کوئی شے نہیں ہے، پانی، لوہے، چاندی سونے، لکڑی یا کوئلے پتھر کی طرح بلکہ مادی اشیا کے مابین کیمیاوی عمل کی ایک کیفیت ہے۔ ان کا درجہ حرارت ہے۔ وہ لکڑی، کوئلہ، مٹی کے تیل، پیٹرول اور دوسرے آتش گیر مادوں کے کیمیاوی عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنا الگ وجود نہیں رکھتی بلکہ کسی نہ کسی مادی شے کے وجود کی محتاج ہوتی ہے۔ تو کیا جن حضرات بھی مادی اشیا کے کیمیاوی عمل کا نتیجہ ہیں؟۔
مولانا نے مجھ کو مغرب زدہ تصور کرکے کئی مغربی مصنفوں سے جن میں سویت روس کے مصنف بھی شامل ہیں، استناد کیا ہے۔ مولانا کا مطالعہ بے شک بہت وسیع ہے اور ان کا ذوق کتب بینی بھی لائق ستائش ہے لیکن کیا ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ نہ ہر چھپی ہوئی تحریر معتبر اور مستند، خواہ وہ مغرب کی ہو یا مشرق کی۔ ہم کو ہر صورت میں اپنی قوتِ عقلیہ سے ضرور کام لینا چاہیے۔مولانا سے یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہ ہوگی کہ خواجگی ہر دور میں نئے نئے مسکرات بناتی رہتی ہے اور یہ کہ کھلونوں سے بچوں ہی کو بہلایا نہیں جاتا۔ سامراجی نظام گزشتہ نصف صدی سے جس اقتصادی، سیاسی، فکری اور اخلاقی بحران میں مبتلا ہے وہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ عام لوگوں کو گمراہ کرنے، ان کی توجہ زندگی کے روزمرہ کے مسائل سے ہٹانے ، ان کی قوتِ فکر و عمل کو مفلوج کرنے کے وہ کون سے حربے ہیں جو مغربی بازی گر استعمال نہیں کررہے ہیں۔ کبھی “ایک دنیا” اور “ایک عالمی حکومت” کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے وہ بھی ایسے وقت میں جب ایشیا اور افریقہ کے محکوم ملک آزادی اور خود مختاری کی جدو جہد میں مصروف تھے۔ دلیل یہ دی جاتی تھی کہ دنیا اب بہت سکڑ گئی ہے، ریاست کے پرانے نظریے اب فرسودہ ہو چکے ہیں اور دنیا کے مسائل اب آپس میں اتنے گتھ گئے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے ایک ” عالمی حکومت” کا قیام لازمی ہوگیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ” عالمی حکومت” کی سربراہی کا اہل امریکہ کے سوا دوسرا کون ہے۔ پھر پروفیسر ٹوائن بی کی فلسفہ تاریخ کی دُھوم مچتی ہے، سارتر صاحب کے فلسفہ وجودیت کو جو وجودیت کی نفی کرتا ہے بانس پر چڑھایا جاتا ہے کہ بالآخر مارکسی فلسفے کا توڑ مل ہی گیا۔ ” مہمل اور بے مقصد” ادب کا بازار گرم ہوتا ہے۔ سر آلیور لاج اور سر آرتھر کوئن ڈائل روحانی کلب قائم کرتے ہیں جہاں روحوں سے بات چیت ہوتی ہے۔ سائنسی ایجادات کی مدد سے بھوتوں، آسیبوں ، ڈراکو لاؤں اور دوسری مافوق الفطرت مخلوقوں پر فلمیں بنتی ہیں، ” مرکر زندہ ہونے والوں” کی آپ بیتیاں چھپتی ہیں، جنوں کی داستانیں شائع ہوتی ہیں، ہپی ازم کا نیا مسلک رائج ہوتا ہے، حشیش کا کاروبار چمکتا ہے اور اس کی اتنی قسمیں بنتی ہیں کہ ” ساحرالموط” ہوتا تو شرما جاتا۔ لندن، پیرس اور نیو یارک کی سڑکیں ” ہری اوم”، “ہری اوم” کے بھجنوں سے گونجنے لگتی ہیں اور یوگا کے ماہر مہارشیوں کی چاندی ہو جاتی ہے اور ہم خوش ہیں کہ دیکھا مادہ پرست افرنگیوں کو آخر کار روحانیت کا قائل کرلیا۔ کتنے سیدھے ہیں ہم لوگ! میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ ان کے نزدیک مغرب کی ابلہ فریبییاں کیا، زمانے کے اتفاقات ہیں یا ان کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی حکمتِ عملی بھی کارفرما ہے؟
آخر میں مولانا سے میری مودبانہ درخواست ہے کہ حیات بعد الموت کے تذکرے اور جنون کی داستانیں اپنی جگہ لیکن کیا یہ بہتر نہ ہو گا کہ آٹھ کروڑ زندہ پاکستانیوں کے زندہ مسائل و مصاحب سے بحث کی جائے۔ ان کی قوتِ فکر و عمل کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے علم و شعور میں اضافے کی تدبیریں اختیار کی جائیں اوراُن توہمات کاطلسم توڑا جائے جن میں ہم صدیوں سے گرفتار ہیں۔
